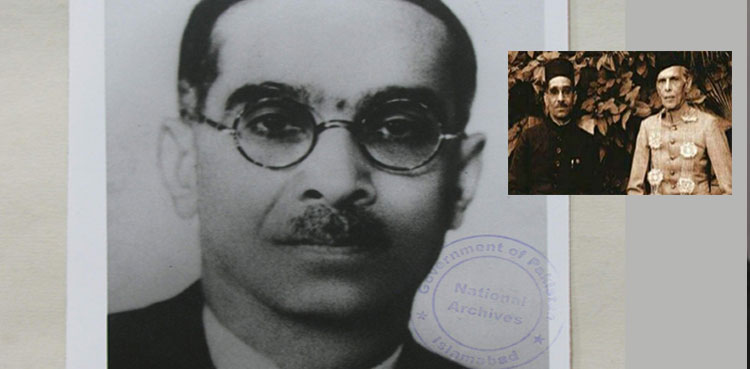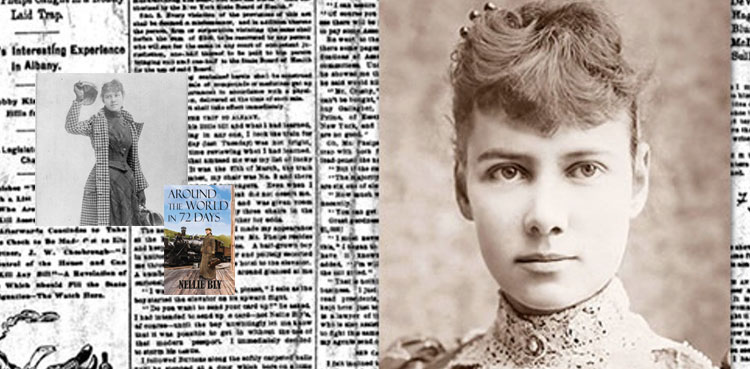آج کا افغانستان امریکا کی بدترین شکست، اتحادی افواج کے مکمل انخلا کے بعد اس سرزمین پر طالبان کی فتح اور اقتدار کے لیے دنیا بھر میں زیرِ بحث ہے۔ چند دہائیوں پہلے اسی ملک میں شکست کے بعد دنیا نے روس کا نقشہ ‘بگڑتا’ دیکھا تھا اور بعد میں وہاں طالبان نے اپنی حکومت قائم کی تھی۔
آج پھر یہ ملک سیاسی انتشار اور افراتفری کا شکار نظر آرہا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق ہزاروں سال پہلے ایک چوتھائی دنیا میں یہ سلطنت خوش حالی اور فلسفہ پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے۔
یہی افغانستان تاریخ کے مختلف ادوار میں اپنی تہذیب و ثقافت، علم و فنون، صنعت گری اور تجارت کے حوالے سے بھی پہچانا جاتا رہا ہے۔ صدیوں پہلے بھی اس ملک کے مختلف علاقہ جات کابل، ہرات، قندھار، غزنی، بدخشاں اور بلخ دنیا میں مشہور تھے۔
ہندو کش کے اونچے پہاڑوں میں گھرا افغانستان ایک زمین بند ملک ہے۔ اس کے دشوار گزار، پہاڑی اور نیم ہموار راستے بھی غیرملکی افواج کی مہمّات کی ناکامی کی ایک وجہ ہیں۔
ہمارا یہ پڑوسی ملک خطّے کے دیگر تمام ممالک سے بھی تاریخ و مذہب اور ثقافتی اعتبار سے نہایت گہرے اور قریبی تعلقات رکھتا ہے۔ اس تمہید کے ساتھ ہم آپ کو افغانستان کے شمالی صوبے بلخ کے قدیم اور اہم تاریخی مقامات کے بارے میں بتاتے ہیں جو آپ کی دل چسپی کا باعث بنے گا۔
دراصل بلخ اپنے تاریخی تجارتی راستے کی وجہ سے اہمیت کا حامل رہا ہے۔ صوبہ بلخ چار ہزار سال سے اس خطّے میں سیاسی، معاشی، مذہبی اور سماجی لحاظ سے اس علاقے کو اہمیت کا حامل بناتا رہا ہے۔
مؤرخین کے مطابق آج کے افغانستان میں شامل باختر ایک ایسا تاریخی اہمیت کا حامل میدانی علاقہ ہے جو کبھی کئی دیگر علاقوں پر مشتمل ایک ریاست تھی جس کے بادشاہ کا سکندرِ اعظم کی فوج سے آمنا سامنا ہوا اور اس بادشاہ کے قتل کے لگ بھگ پندرہ سو سال بعد چنگیز خان کی فوج نے بھی اس علاقے کو تاراج کیا۔ اس زمانے میں باختر کا دارُالسّلطنت شہر بکترا (بلخ) تھا جو اب افغانستان میں شامل ہے۔
تاریخ بتاتی ہے کہ 35 سو سال قبل زرتشت مذہب کے بانی بھی اسی علاقے میں رہے اور قیاس کیا جاتا ہے کہ یہیں ان کی وفات ہوئی۔ بعد میں اس خطّے میں اسلام کی روشنی پھیلی تو یہاں کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔
فارسی کے مشہور شاعر اور عظیم بزرگ مولانا رومی بھی یہیں پیدا ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ ان کا مدفن بھی بلخ ہی میں واقع ہے۔
مؤرخین نے کتابوں میں اس علاقے میں مٹّی سے تعمیر کردہ ایک دیوار کا تذکرہ کیا ہے جو بلخ کے زرخیز علاقوں کو صحرا کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ دیوار اس دور کی اہم اور قابلِ ذکر دریافت ہے۔
اسی بلخ کے شہر دولت آباد کا ایک چھوٹا سا گاؤں زادیان اپنے مٹّی کے ایک خوب صورت اور عظیمُ الشان مینار کی وجہ سے ماہرینِ آثارِ قدیمہ اور مؤرخین کی توجّہ کا مرکز رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بارہویں صدی میں تعمیر کردہ اس مینار کو اس وقت کوئی نام نہیں دیا گیا تھا۔
یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر چشمۂ شفا کا نخلستان ہے جہاں واقع قربان گاہ میں ایک بہت بڑا اور وزنی پتّھر موجود ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں زرتشت بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس پتّھر کے اوپر ایک سوراخ بھی ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے منہ پر زرتشت تیل ڈال کر آگ لگاتے تھے۔ یہ آگ بھڑکتی رہتی تھی جسے دور دور سے دیکھا جاسکتا تھا۔