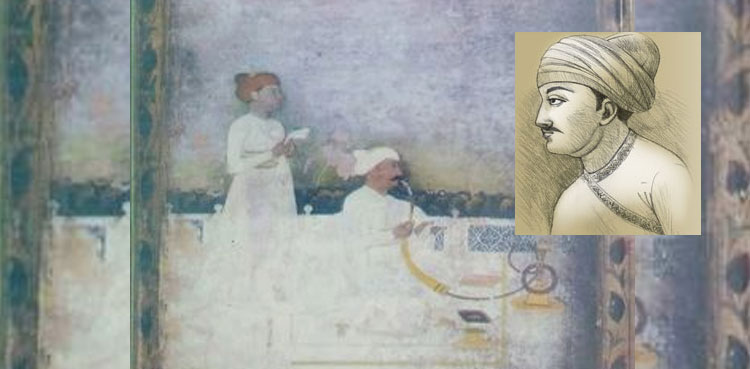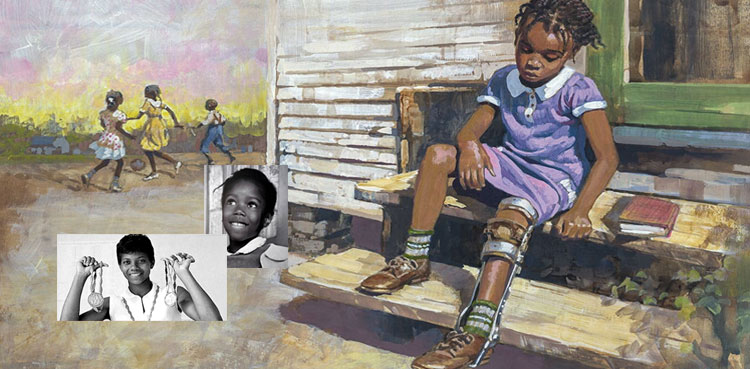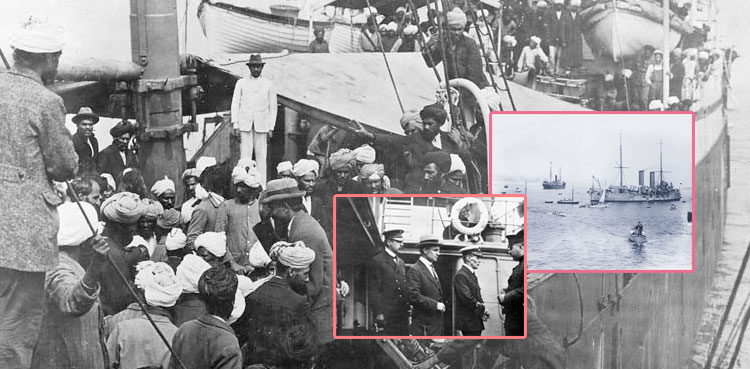جنوبی بحرِ اوقیانوس میں ارجنٹائن کے ساحل سے 480 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود جزائر کا مجموعہ فاک لینڈ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں 776 چھوٹے جزائر اور دو بڑے جزیرے مشرقی فاک لینڈ اور مغربی فاک لینڈ کہلاتے ہیں۔ یہ رقبے کے اعتبار سے 12,000 مربع کلومیٹر سے زائد پر محیط ہیں اور یہاں کی آبادی 3 ہزار نفوس پر مشتمل ہے۔
ان جزائر کا انتظام 1833ء سے برطانیہ نے سنبھال رکھا ہے، لیکن ارجنٹائن بھی ان پر اپنا حقِ ملکیت جتاتا ہے اور اس حوالے سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کشیدہ رہے ہیں۔ برطانیہ اور ارجنٹائن کے درمیان 1982ء میں ان جزائر پر قبضے کے لیے جنگ بھی ہوچکی ہے جس میں ارجنٹائن کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔
1982ء میں مارگریٹ تھیچر برطانیہ کی حکم راں تھیں اور جب ان جزائر پر قبضے کے لیے ارجنٹائن کی جانب سے فوجی کارروائی کی گئی تو مارگریٹ تھیچر نے طاقت ہی سے اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا۔
برطانیہ کی سابق وزیرِ اعظم مارگریٹ تھیچر 2013ء میں آج ہی کے روز انتقال کرگئی تھیں۔ ان کی موت سے صرف ایک ماہ قبل یعنی 10 مارچ 2013ء کو فاک لینڈ میں عوامی ریفرنڈم میں وہاں کے باسیوں نے برطانیہ کی عمل داری قبول کی تھی۔ ارجنٹائن کے حق میں صرف 3 ووٹ آئے تھے۔
مارگریٹ تھیچر کو برطانیہ میں ‘آئرن لیڈی’ کہا جاتا ہے۔ وہ مضبوط اعصاب کی مالک اور اپنے فیصلے پر ڈٹ جانے والی خاتون تھیں۔ 3 اپریل 1982ء کو ارجنٹائن نے ان جزائر پر قبضہ کرنے کے لیے فوج اتاری تو انھوں نے وزیرِ اعظم کی حیثیت سے جنگ کے لیے ایک سو جنگی بحری جہاز اور 27 ہزار فوجی روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپریل میں شروع ہونے والی فاک لینڈ جنگ 74 دنوں تک جاری رہی اور جون کے مہینے میں ارجنٹائن کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔
مارگریٹ تھیچر کے فوجی کارروائی کے فیصلے کی برطانوی عوام نے بھی کھل کر تائید اور حمایت کی تھی اور اسی فیصلے نے انھیں برطانیہ کے اگلے عام انتخابات میں بھی کام یاب کروایا۔
اگلی بار بھاری کام یابی کے بعد مارگریٹ تھیچر نے اپنے ایک مشکل ترین فیصلے سے خود کو پھر آئرن لیڈی ثابت کیا، ان کے اس دورِ حکومت میں برطانیہ میں نمایاں اقتصادی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں۔
وہ برطانیہ کی پہلی خاتون وزیرِاعظم تھیں، ان کا پورا نام مارگریٹ ہلڈا تھیچر تھا۔ وہ اپنے ارادوں کی پختگی اور سخت گیر مؤقف کے لیے ہی مشہور نہیں تھیں بلکہ ناقدین انھیں سخت اور مفاہمت نہ کرنے والی خاتون بھی کہتے تھے۔
مارگریٹ تھیچر نے ثابت کیا کہ ملکی سیاست اور اس عہدے کے لیے ان کا انتخاب غلط نہ تھا۔ اپنے دور میں انھوں نے کئی سیاسی، اقتصادی اور عسکری فیصلے کیے جو نہایت مشکل تھے، لیکن انھوں نے اس پر اپنی سخت مخالفت اور تنقید کی بھی پروا نہ کی۔
انھیں تین بار اپنے ملک کے اہم ترین منصب کے لیے منتخب کیا گیا۔
مارگریٹ تھیچر کا سنِ پیدائش 1925ء ہے۔ وہ گرانتھم، لنکاشائر میں پیدا ہوئی تھیں۔
ان کے والد سبزی فروش تھے۔ وہ ایک جُزوقتی مبلغ اور مقامی کونسلر بھی تھے جن کا ان کی بیٹی کی زندگی پر اثر تھا۔
وہ کہتی تھیں کہ ’میرے والد نے میری ایسی تربیت کی ہے کہ میں ہر اس چیز پر یقین کروں جس پر مجھے یقین ہو۔‘
آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کرنے والی مارگریٹ تھیچر کیمسٹری کے مضمون میں ڈگری لینے کے بعد 1947ء سے لے کر1951ء تک ایک ادارے میں تحقیق میں مصروف رہیں۔
1951ء میں شادی کے بعد بھی مارگریٹ تھیچر نے تعلیمی سلسلہ جاری رکھا، مگر اب وکالت ان کا مضمون تھا۔ 1953ء میں امتحان میں کام یابی کے بعد وہ ٹیکس اٹارنی بن گئیں۔ یہاں سے انھیں سیاست کے میدان میں قدم رکھنے کا موقع ملا اور وہ کنزرویٹو پارٹی سے وابستہ ہو گئیں۔
مارگریٹ تھیچر 1959ء میں اپنی جماعت کے ٹکٹ پر دارالعوام کی رکن منتخب ہوئیں۔ ان کی سیاسی بصیرت اور اہلیت نے انھیں آگے بڑھنے کا موقع دیا اور ایک روز وہ برطانیہ کی وزیراعظم بنیں۔
مارگریٹ تھیچر کے دور میں برطانیہ میں کئی شعبوں میں اصلاحات کے سبب وہاں عوام کو کئی مشکلات پیش آئیں اور انھیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن بعد میں ان اصلاحات اور بطور وزیرِ اعظم مارگریٹ تھیچر کے فیصلوں کے مثبت اثرات ظاہر ہونے لگے۔ ان کی پالیسیوں کے باعث برطانیہ میں بے روز گاری کی شرح بہت بڑھ گئی تھی، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ انہی پالیسیوں کی وجہ سے برطانوی معیشت میں دیرپا ترقّی دیکھنے میں آئی۔
ان کی پالیسیوں کے تحت برطانیہ میں نجکاری کا عمل تیز ہوا۔ انھوں نے اپنے ملک میں ’فری مارکیٹ اکانومی‘ کی ترقّی کے لیے کام کیا۔ ان کے دور میں مزدور یونین تنظیموں کے اثرات کو کم کرنے اور نجکاری کے لیے قوانین متعارف کرانے کے علاوہ کونسل کے گھروں میں رہنے والوں کو وہی گھر خریدنے کی اجازت جیسے اہم فیصلے کیے گئے تھے۔
برطانیہ اور ارجنٹائن جنگ کے دوران ان کی کام یاب خارجہ پالیسی کو بھی بہت سراہا جاتا ہے۔
بعض ناقدین کی نظر میں سخت مزاج اور اپنا مؤقف تبدیل نہ کرنے والی مارگریٹ تھیچر کے بارے میں ان کے بعد وزیرِاعظم کا عہدہ سنبھالنے والے سَر جان میجر نے کہا تھا، ’ان کی اقتصادی اور مزدور تنظیموں کے قوانین میں اصلاحات اور فاک لینڈ جزیروں پر برطانوی کنٹرول یقینی بنانے کے اقدامات نے انھیں ایک اعلیٰ پائے کے سیاست دان ثابت کیا۔ یہ ایسی کام یابیاں تھیں جو شاید کوئی اور راہ نما حاصل نہیں کر سکتا تھا۔‘
مارگریٹ تھیچر بیسویں صدی کی اہم ترین سیاسی شخصیات میں شمار کی جاتی ہیں جنھوں نے 1979ء، 1983ء، اور 1987ء کے عام انتخابات میں کام یابی حاصل کی تھی۔
برطانیہ کی آئرن لیڈی 1992ء میں پارلیمان کے ایوانِ زیریں ریٹائر ہوئیں۔ ان کی سیاست کا بعد میں بھی آنے والے راہ نماؤں کی پالیسیوں پر گہرا اثر رہا۔