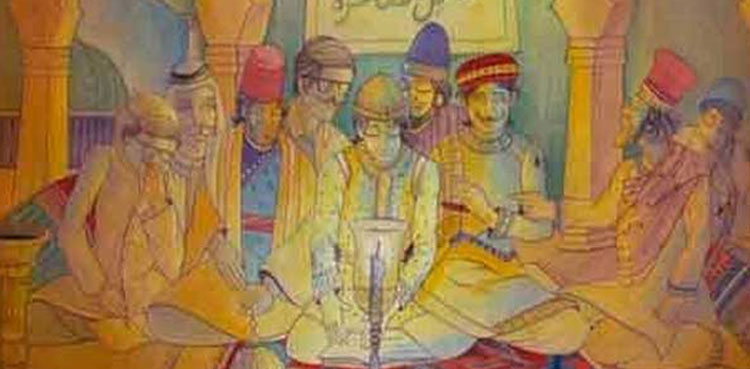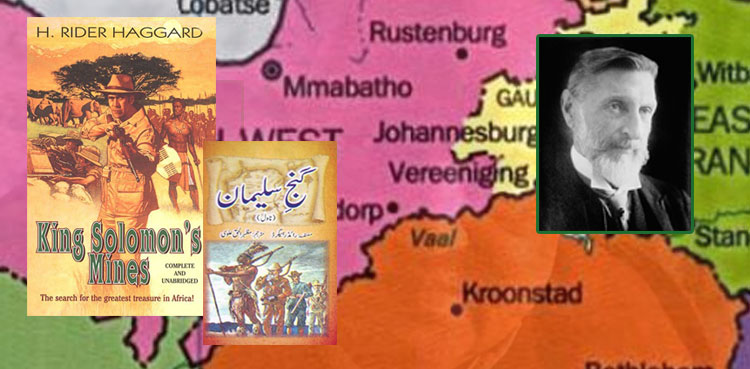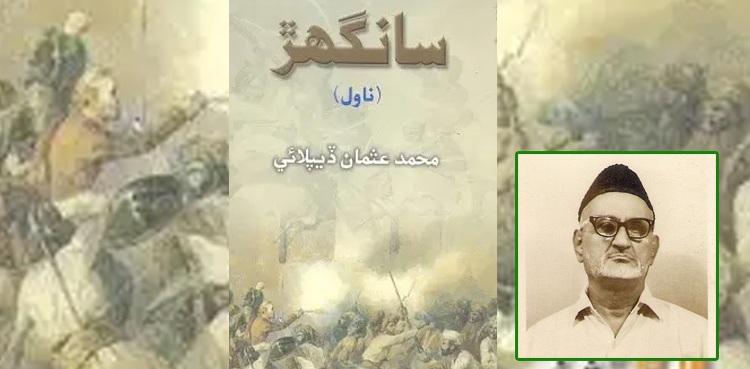ہزار ہا صدیوں سے روئے زمین پر زندہ رہنے کے لیے جتن کرتے انسان نے کئی قیامت خیز منظر دیکھے، طرح طرح کی افتاد کا سامنا کیا اور ناگہانی آفات کا شکار ہوا۔
کبھی دریا بپھرے تو کہیں سمندر کی لہروں نے بے رحمی کا ثبوت دیا، کبھی جیتے جاگتے شہروں کو گرد و باد کے طوفان نے انسانوں کا مدفن بنا چھوڑا۔ زلزلے آئے، شدید بارشیں ہوئیں اور موسم کی سختیوں کے آگے انسان ڈھیر ہورہا۔ اسی طرح مہلک امراض اور وبائیں بھی انسانوں کی ‘قاتل’ ثابت ہوئیں۔
آج دنیا کو کرونا کی وبا کا سامنا ہے جس نے لاکھوں انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا ہے جس طرح ماضی میں مختلف خطّوں میں طاعون، چیچک، اسپینش فلو جیسی وباؤں اور مہلک امراض نے لاکھوں، کروڑوں انسانوں کو ہلاک کردیا تھا۔
جس طرح آج ہم کرونا کی وبا کے سبب اپنے سماج اور طرزِ زندگی میں بدلاؤ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح ماضی کی بعض وباؤں نے جہاں کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کی زندگی کا خاتمہ کیا، وہیں دنیا بھر میں نمایاں تبدیلیوں کا محرّک ثابت ہوئیں۔
یہاں ہم چند مہلک وبائی امراض کا ذکر کرتے ہوئے ان وباؤں کی بات کریں گے جنھوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔
ماضی کے ہلاکت خیز وبائی امراض
ہسپانوی فلو نے 1918ء میں سَر اٹھایا اور 1920ء تک اس مہلک وبا نے دس کروڑ انسانوں میں موت بانٹ دی تھی۔ دنیا اس وقت پہلی جنگِ عظیم کی تباہی کے اثرات جھیل رہی تھی اور اس وبا نے زندگی مزید دشوار کردی۔ ہسپانوی فلو سے ہلاک ہونے والوں میں خاصی تعداد جوانوں کی تھی۔
ایک وبا ایشیائی فلو کے نام سے تاریخ میں ‘زندہ’ ہے جو 20 لاکھ انسانوں کی قاتل ثابت ہوئی۔ 1957ء میں چین سے فلو کی یہ قسم دنیا بھر میں پھیل گئی اور ایک سال کے اندر فقط امریکا ہی میں 70 ہزار لوگ اس کے ہاتھوں ہلاک ہوگئے۔
1915ء میں نیند کی وبا نے سر اٹھایا جس کا سبب ایک جرثومہ تھا۔ 1925ء تک اس مصیبت نے لگ بھگ 15 لاکھ انسانوں کی زندگی ختم کردی تھی۔ یہ گردن توڑ بخار کی ایک شکل تھی جس میں مریض پر شدید غنودگی طاری ہو جاتی تھی۔
اگر ہم وباؤں کے ساتھ مختلف مہلک جراثیمی امراض کی بات کریں تو ہیضہ، خسرہ، ملیریا کے علاوہ انفلوئنزا، ہنٹا، ایبولا، کانگو وائرس، ڈینگی نے بھی دنیا کو متاثر کیا تھا، لیکن بعض وبائیں ایسی ہیں جنھوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ان وباؤں میں مغربی یورپ میں پھیلنے والا طاعون جسے بلیک ڈیتھ کہا جاتا ہے، 1350ء کا طاعون، 15 ویں صدی میں امریکا میں پھوٹنے والی چیچک کی وبا، 1801ء میں افریقی ملک ہیٹی کا زرد بخار اور 1641ء میں شمالی چین کا طاعون قابلِ ذکر ہیں۔
دنیا میں بڑی تبدیلیوں کا محرّک بننے والی وباؤں پر ایک نظر
جسٹینین طاعون
آغاز کرتے ہیں جسٹینین طاعون سے جس کا زمانہ 541ء کا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس طاعون نے ڈھائی کروڑ انسانوں کی جان لی تھی۔ اس کی مدت دو سال بتائی جاتی ہے، لیکن اس عرصے میں اس مہلک وبا نے اس زمانے کی بازنطینی ریاست اور ساسانی سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وبا کے بعد خطّے کی تاریخ کا رُخ ہی بدل گیا اور چند عشروں بعد ہی عرب اس خطّے کی سیاسی طاقتوں کو پیچھے دھکیلنے میں کام یاب رہے۔
انتونین
انتونین کی وبا لگ بھگ 50 لاکھ اور بعض ماہرین کے مطابق ایک کروڑ انسانوں کی موت کا سبب بنی تھی۔ اس وبا نے 165 سے 180 عیسوی تک انسانوں کو خوف زدہ کیے رکھا۔ یہ وہ وقت ہے جب رومی سلطنت کا عروج تھا۔ اس زمانے میں یورپ کا بڑا حصّہ اس سے متاثر ہوا اور لوگوں کے حالات بدتر ہوگئے جس نے افراتفری اور انتشار کو جنم دیا۔ مشہور حکیم جالینوس اسی دور میں گزرا ہے جس نے اس مرض کے بارے میں بھی لکھا تھا۔
طاعون کی وبا اور یورپ
یہ 1346ء کی بات ہے جب ایک وبائی مرض نے بحیرہ روم، فرانس اور شمالی افریقا میں ہر طرف گویا موت بانٹنا شروع کردی۔ متاثرہ علاقوں کی آدھی آبادی مٹ گئی۔ اس بوبونک طاعون نے یورپی سماج، معیشت اور سیاست کو بدترین دوراہے پر لا کھڑا کیا۔ یہ وبا مغربی یورپ میں پھوٹی تھی، اور اس نے وہاں جاگیرداری نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔
مسلسل اموات کے سبب زمین داروں اور اشرافیہ کو نوکروں اور کسانوں کی کمی کا مسئلہ درپیش تھا۔ محنت کشوں کی اکثریت موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔
وبا تھمی تو وہاں بھوک اور بدحالی منڈلا رہی تھی۔ اب غریب اور محنت کش طبقہ معقول اجرت اور معاوضہ چاہتا تھا۔ امرا کی ضرورت کا اندازہ کرتے ہوئے مزدوروں میں ان سے سودے بازی کی ہمّت پیدا ہوئی اور انھوں نے بہتر معاوضہ اور اجرت طلب کی۔ اسی وبا کے بعد یورپ دو حصّوں مغربی اور مشرقی یورپ میں بٹ گیا تھا۔
مغربی یورپ کے کسان اور محنت کش اکٹھے ہوگئے اور انھوں نے مختلف ٹیکس اور محاصل دینے سے انکار کرتے ہوئے اس کے خلاف باقاعدہ تحریک شروع کردی۔
کسانوں نے جرمانوں اور جبری مشقت کے خلاف مہم چلائی اور مغربی یورپ میں پھیل گئے۔ وہ بادشاہت کا زمانہ تھا، اور 1381ء میں عوام نے شاہی احکامات ماننے اور مزید ٹیکس دینے سے انکار کردیا۔ یوں وہاں سیاسی اور انتظامی تبدیلیوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تب کسانوں کے حالات بھی کسی قدر بہتر ہوئے۔
دوسری طرف مشرقی یورپ بھی اس وبا سے متاثر ہوا تھا، لیکن وہاں اس وبا کے بعد مختلف صورتِ حال نظر آئی۔ وہاں جاگیرداری نظام مزید مستحکم ہوا جس کے مختلف اسباب ہیں۔ تاہم یہ بھی ایک بڑی تبدیلی تھی۔
مشرقی اور مغربی یورپ 1600ء تک الگ الگ طاقت بنے اور یہ وبا کے بعد پیدا ہونے والے حالات ہی کا نتیجہ تھا۔
نوآبادیاتی نظام اور چیچک کی وبا
پندرھویں صدی کے آخری برس امریکا میں چیچک کی وبا سے ہلاکتوں اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے تاریخ میں یاد رکھے گئے ہیں۔
برطانیہ میں یونیورسٹی کالج لندن کے ایک علمی اور تحقیقی مطالعے سے یہ بات سامنے آئی کہ یورپ کی توسیع کی خواہش کے نتیجے میں اس خطّے کی آبادی ایک سو سال میں صرف پانچ یا چھے ملین رہ گئی تھی۔ ان میں زیادہ اموات نو آبادیاتی نظام کا نتیجہ تھیں، کیوں کہ مختلف برسوں کے دوران مہمّات سَر کرکے اپنے آبائی علاقوں کو لوٹنے والے اپنے ساتھ وبائی امراض بھی لائے اور وہ اس سے بے خبر تھے۔ انہی میں سب سے بڑا قاتل چیچک تھا جس نے امریکا میں پنجے گاڑ دیے۔ بعد میں اس وبا کے ہمہ گیر اثرات ظاہر ہوئے۔
ان وباؤں کے سبب افرادی قوّت کی کمی اور انسانی آبادیوں کا توازن بگڑنے سے کھیتی باڑی کم ہو گئی اور اس نے ماحول کو بھی متاثر کیا۔زمین جنگلات میں تبدیل ہونے لگی اور اس کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کم ہوگیا جس سے دنیا کے بعض خطّوں میں درجہ حرارت بھی گر گیا۔
سائنس دانوں کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہی بڑے آتش فشاں پھٹے اور ایک ایسا دور گزرا جسے "لٹل آئس ایج” کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ یورپ متاثر ہوا، جہاں فصلوں کو شدید نقصان پہنچا اور قحط پڑا۔
چین کا وبائی مرض جو منگ بادشاہت کو لے ڈوبا
منگ خاندان نے تقریباً تین صدیوں تک چین پر راج کیا، لیکن طاعون کی وبا نے مشرقی ایشیا میں اس کی طاقت اور اثر رسوخ کو تباہ کردیا۔1641ء میں شمالی چین میں وبائی مرض سے کچھ علاقوں میں بیس سے چالیس فی صد آبادی ختم ہوگئی۔
طاعون سے پہلے وہاں خشک سالی اور ٹڈی دل نے بھی پنجے گاڑ رکھے تھے جس کے بعد وہاں لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ اس طاعون نے حالات کو مزید خراب کردیا اور ایک یلغار نے منگ خاندان کی تین صدیوں پرانی بادشاہت کو بھی نگل لیا۔
ہیٹی کا زرد بخار جس نے ‘کالونیوں’ کا راستہ روکا
کہتے ہیں ہیٹی میں پھیلنے والی وبا ہی تھی جس نے فرانس کو شمالی امریکا سے باہر نکالا اور نوآبادیاتی نظام کا راستہ روکا جس کے بعد امریکا کو وسعت ملی اور اس کی طاقت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔
یہ 1801ء کی بات ہے جب یورپ نوآبادیاتی نظام پر توجہ دے رہا تھا۔ ہیٹی میں زرد بخار کی وبا پھیل گئی جس نے تقریباً پچاس ہزار فوجی، انتظامی افسران، معالج اور ملاحوں کی جان لے لی۔ وہاں بغاوت پھوٹ پڑی اور اس وقت وہاں سے فرانس کے صرف تین ہزار مرد زندہ لوٹنے میں کام یاب ہوئے۔
اس افریقی وبا نے نپولین کو نوآبادیاتی عزائم ترک کرنے پر مجبور کردیا۔کہتے زرد بخار نے نہ صرف ہیٹی بلکہ شمالی امریکا کو بھی فرانس کی نوآبادیات بننے سے بچا لیا۔
جانوروں میں پھیلنے والی بیماری اور نئی کالونیاں
یہ کوئی وبائی مرض نہ تھا بلکہ 1888ء سے 1897ء کے جانوروں میں پھیلنے والا وائرس تھا جسے رینڈر پیسٹ وائرس کہتے ہیں۔ اسے مویشیوں کا طاعون بھی کہا گیا ہے۔ اس وائرس نے افریقا میں 90 فی صد مویشیوں کو ہلاک کردیا جو بھوک اور بدحالی کا سبب بنا اور وہاں افراتفری اور بدانتظامی پھیلی۔ زرد بخار کے برعکس اس طاعون نے یورپ کو نئی کالونیاں قائم کرنے کا موقع دے۔
طاقت ور یورپی ممالک نے انیسویں صدی کے آخر میں افریقا میں افراتفری اور بدحالی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں قدم جمائے۔ فرانس، جرمنی، پرتگال، بیلجیئم اور اٹلی سمیت یورپ کے 14 ممالک نے کئی افریقی علاقوں پر بعد میں اپنا حقِ حکم رانی منوایا اور نقشہ سازی کی اور 1900ء تک اس برّاعظم کے 90 فی صد حصّے پر ان ممالک کا تسلط قائم ہوگیا۔