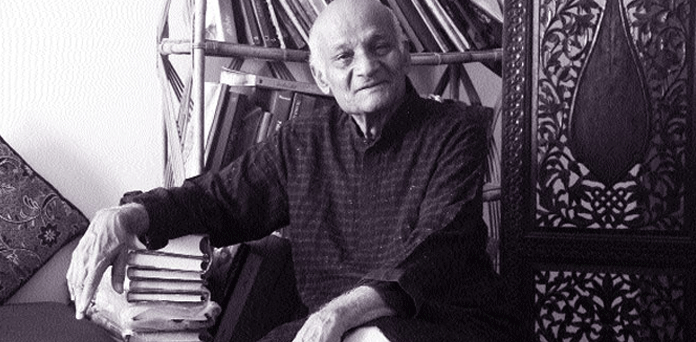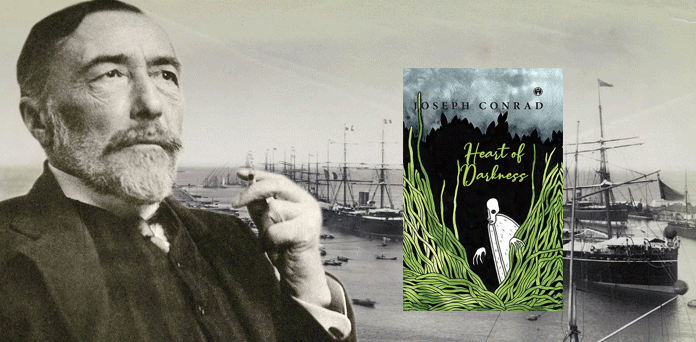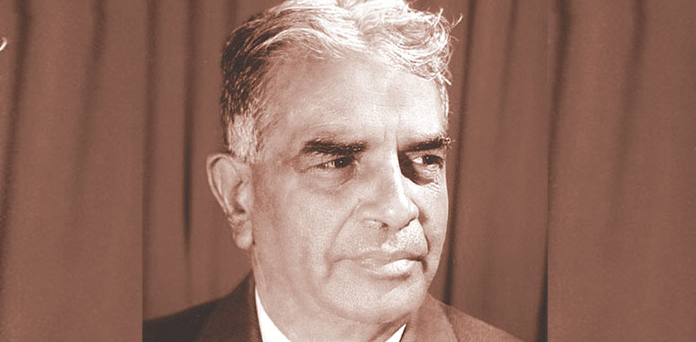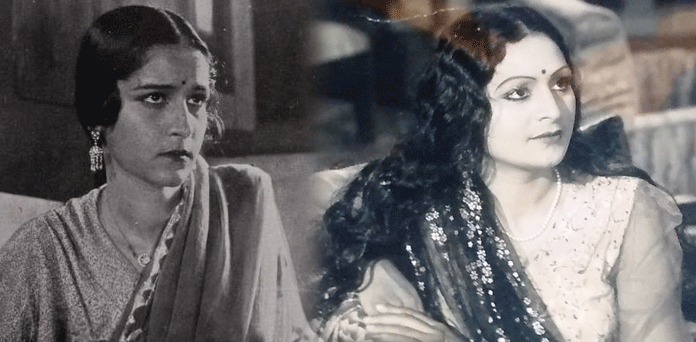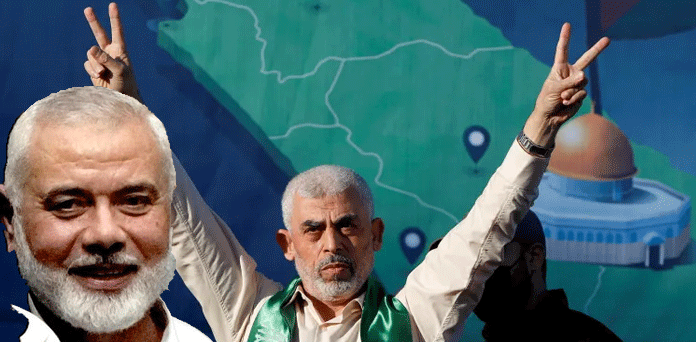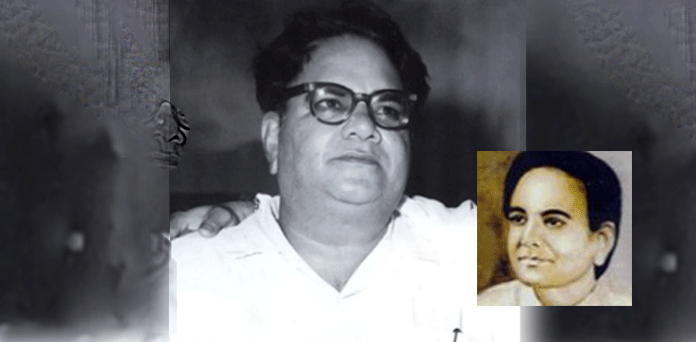بڑے ادیب کی تخلیق کئی عشروں کا احاطہ کرتی ہے، وہ صدیوں پر پھیل جاتی ہے اور ادیب کے گزر جانے کے بعد بھی برسوں پڑھی جاتی ہے۔ اس پر تنقیدی مباحث جاری رہتے ہیں اور ادبی دنیا میں اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔
جوزف کونریڈ (Joseph Conrad) بھی ایسا ہی ایک ادیب تھا، جس کا عالمی ادب میں خوب چرچا ہوا، اس کا اندازہ ان تقاریب سے لگایا جاسکتا ہے جو اس ادیب کی وفات کے سو برس مکمل ہونے پر اس کی یاد میں منعقد کی جارہی ہیں۔
گزشتہ دنوں آرٹس کونسل کراچی میں بھی ایسی ہی ایک تقریب "رائٹرز اینڈ ریڈرز کیفے” کے زیرِ اہتمام منعقد ہوئی، جس میں اس باکمال ادیب کے فن و اسلوب کا ذکر چھڑا، تو کئی نئے سوالات اور ان کے جواب سامنے آئے جن سے بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اس تقریب کا احوال جاننے سے پہلے جوزف کونریڈ کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
جوزف کونریڈ کون تھا؟
جوزف کونریڈ ایک پولش نژاد برطانوی ادیب تھا، جسے اپنے موضوعات، منفرد انداز بیان کے ساتھ انسانی فطرت اور اس کی نفسیات کو بیان کرنے کے لیے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جوزف کونریڈ نے 1857ء میں آنکھ کھولی، اور اس کی زندگی کا یہ سفر 1924 میں تمام ہوا۔ کونریڈ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بحری سفر میں گزارا، اور اس کے تجربات کونریڈ کی تحریروں میں بھی جھلکتے ہیں۔ اس کے مشہور ناولوں میں ہارٹ آف ڈارکنس، لارڈ جم، اور نوسٹرو مو شامل ہیں۔

یہ ناولز وجودیت، نوآبادیاتی نظام اور اخلاقی گراوٹ جیسے موضوعات کو کمال مہارت سے منظر کرتے ہیں۔ ہارٹ آف ڈارکنس(Heart of Darkness) کونریڈ کا سب سے مقبول ناول ہے، جسے یورپی سامراجیت پر ایک گہری تنقید تصور کیا جاتا ہے، جو انسانی فطرت کے تاریک پہلو اور افریقا میں نوآبادیاتی دور کے مظالم کو بیان کرتا ہے۔ گو بعد میں چنوا اچیبے سمیت مختلف ناقدین نے جوزف کونریڈ پر تعصب برتنے اور نوآبادیاتی نظام کی شبیہہ سازی کا الزام بھی لگایا۔ جوزف کونریڈ کے اس مشہورِ زمانہ ناول، ہارٹ آف ڈراکنس کا ترجمہ اردو کے ممتاز ادیب اور مترجم، سلیم الرحمان صاحب نے قلبِ ظلمات کے نام سے کیا۔

تذکرہ رائٹرز اینڈ ریڈرز کیفے کا:
رائٹرز اینڈ ریڈرز کیفے ایک ادبی تنظیم ہے، جس میں شامل ارکان کی اکثریت قلم قیبلے سے ہے۔ اس کی ہفتہ وار نشستیں آرٹس کونسل کی جوش ملیح آبادی لائبریری میں منعقد ہوتی ہیں، جہاں کراچی کے ادبا کی بڑی تعداد باقاعدگی سے شرکت کرتی ہے، ساتھ ہی اس کی فیس بک پر لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے دیگر شہروں میں بسنے والے بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس کی روحِ رواں معروف شاعر، مترجم، نقاد اور انگریزی ادب کی استاد ڈاکٹر تنویر انجم ہیں۔ گزشتہ دو برس میں اس کے نوے اجلاس ہوچکے ہیں، جن میں ادب، سماج، سیاست، اور فلم سمیت فنون لطیفہ کی تمام اصناف زیر بحث آئیں۔
جوزف کونریڈ اور کیفے کے ۸۹ اجلاس کی جھلکیاں:
ماہ ستمبر کی بارہ تاریخ کو رائٹرز اینڈ ریڈرز کیفے نے "جوزف کونریڈ کے سو سال” کے عنوان سے آرٹس کونسل میں ایک تقریب سجائی، جس کی صدارت دنیائے صحافت و ادب کی ممتاز شخصیت، غازی صلاح الدین نے کی۔

اس تقریب میں ڈاکٹر تنویر انجم، سید کاشف رضا، ماخام خٹک، بشام خالد اور وشال خالد نے جوزف کونریڈ کے فن کے مختلف پہلوئوں کا احاطہ کیا۔ سید طلحہ علی نے اس کی نظامت کی۔
اپنے صدارتی خطے میں غازی صلاح الدین نے کہا کہ جوزف کونریڈ کا مطالعہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے، وہ ایک اہم ادیب تھا، جس نے نیا طرز اسلوب اختیار کیا اور نوآبادیاتی نظام کے سقم عیاں کیے۔
مقررین میں حشام خالد نے جوزف کونریڈ کے ناول "لارڈ جم”، جب کہ ماخام خٹک اور وشال خالد نے ہارٹ آف دی ڈارک نیس کے مختلف پہلوئوں کا احاطہ کیا۔ سید کاشف رضا نے جوزف کونریڈ کے ناولز یوتھ اور Typhoon کے فنی محاسن پرروشنی ڈالی۔
اس موقع پر شرکا نے بھی مقررین سے سوالات کیے۔ یہ مکالمہ ڈھائی گھنٹے جاری رہا، جس میں اس ممتاز قلم کار پر سیر حاصل بحث ہوئی۔
حرفِ آخر:
قارئین، آج کے دور میں جوزف کونریڈ کو پڑھنا اس لیے بھی اہم ہے کہ اُن کے موضوعات طاقت، شناخت، اور عالمی استحصال جیسے موجودہ مسائل سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی نثر قارئین کو عصری مسائل پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کی دعوت دیتی ہے، ساتھ ہی ہمیں یہ خبر بھی دیتی ہے کہ نوآبادیاتی دور کے انگریز ادیب بھی ایک حد تک اپنے سانچے سے باہر جاسکتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی باغی کیوں نہ ہوں۔