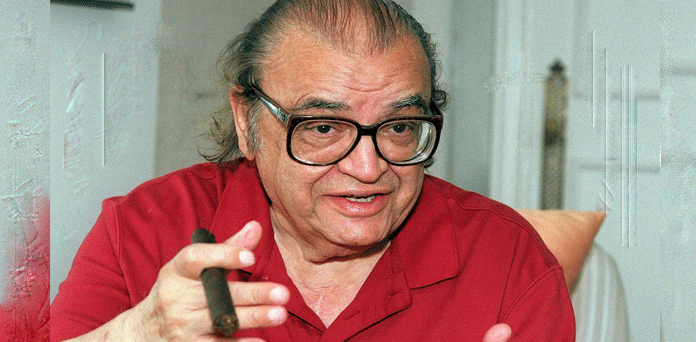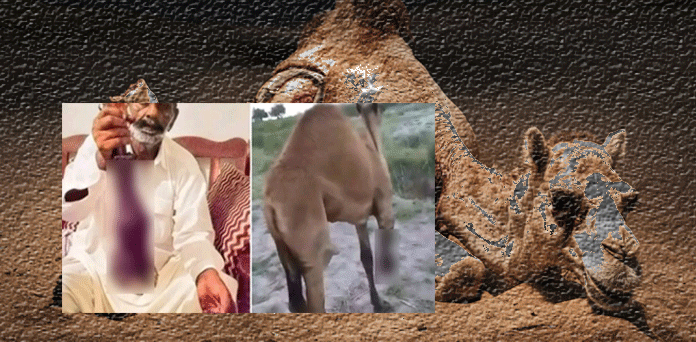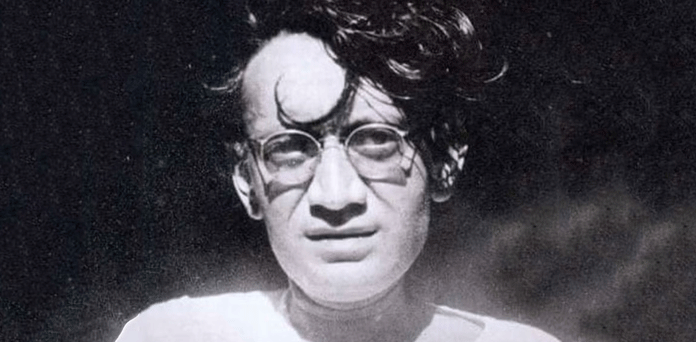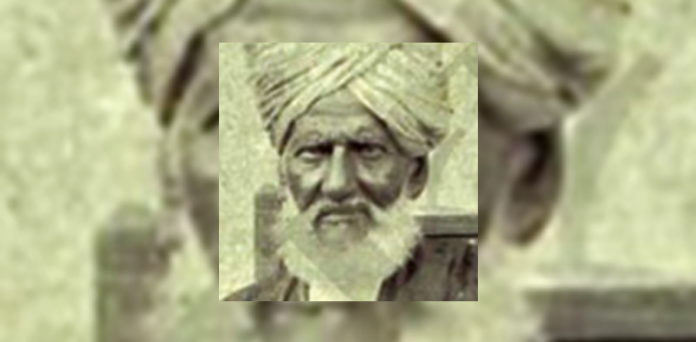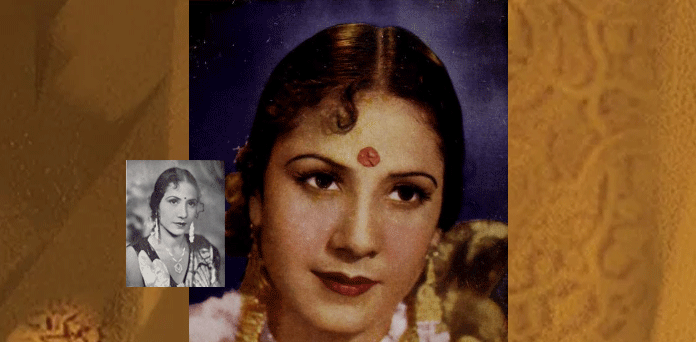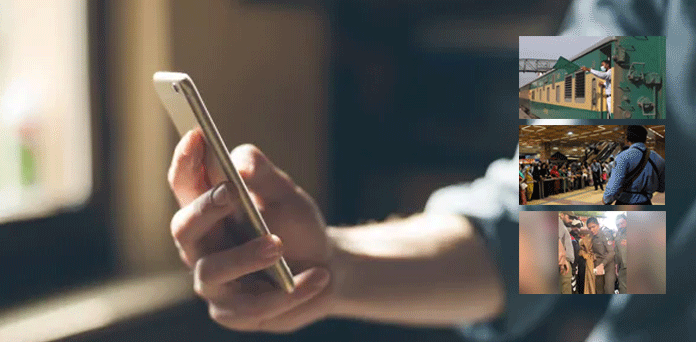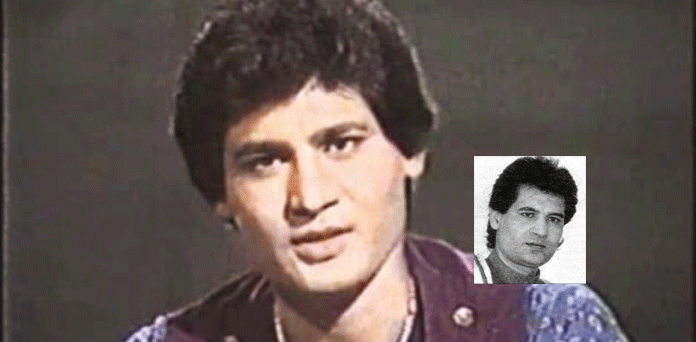ادبی دنیا کے ناقدین کا خیال ہے کہ ماریو پوزو(Mario puzo) کا تذکرہ کیے بغیر گزشتہ دہائیوں کا ادبی منظر نامہ مکمل نہیں ہوسکتا۔ عالمی شہرت یافتہ ناول نگار اور شارٹ اسٹوری رائٹر ماریو پوزو کا جرم اور اس تاریک دنیا پر مبنی ایک ناول ‘دی گاڈ فادر’ بہت مقبول ہوا جس پر فلم بھی بنائی گئی تھی۔ ماریو پوزو 2 جولائی 1999ء کو اس دنیا سے رخصت ہوگئے تھے۔
ماریو پوزو کے حالاتِ زندگی، ان کے تخلیقی سفر پر نظر ڈالیں تو وہ ایک بہترین ناول نگار ہی نہیں مختصر کہانی نویس اور اسکرین رائٹر بھی تھے اور باکمال ادیب کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ ماریو پوزو کے آباء و اجداد کا تعلق اٹلی سے تھا، لیکن ان کا تعلق جس کنبے سے تھا، وہ امریکہ میں مقیم تھا۔ یہاں نیویارک کے شہر مین ہٹن میں ماریو پوزو 15 اکتوبر 1920ء میں میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک معمولی گھرانے کے فرد تھے۔ انھوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نیویارک ہی سے گریجویشن کیا اور جب دوسری جنگِ عظیم شروع ہوئی تو انھوں نے امریکی فضائیہ میں شمولیت اختیار کر لی لیکن معلوم ہوا کہ ماریو پوزو کی نظر کمزور ہے۔ ان کے لیے شعبۂ تعلقاتِ عامّہ میں اسامی نکالی گئی اور وہاں تبادلہ کر دیا گیا۔ ماریو پوزو مطالعہ کا شوق رکھتے تھے اور لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی شروع کرچکے تھے۔ یہ سلسلہ دورانِ ملازمت ان کے افسانوں اور کہانیوں کی شکل میں جاری رہا اور رفتہ رفتہ ماریو پوزو قارئین اور ادبی دنیا میں پہچان بنانے لگے۔
1950ء میں نوجوان ماریو پوزو کا پہلا افسانہ شایع ہوا۔ بعد کے برسوں میں ماریو پوزو نے شارٹ اسٹوریز کے ساتھ ناول نگاری بھی شروع کردی اور پھر وہ جرائم پیشہ گروہوں اور مافیا پر اپنی کہانیوں کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ ماریو پوزو نے گیارہ ناول لکھے جن میں سب سے زیادہ مقبول ناول گاڈ فادر ہے۔ اسی ناول نے عالمی ادب میں ماریو پوزو کو شناخت دی۔ یہ وہ ناول ہے جس پر مبنی فلم کو تین اکیڈمی ایوارڈ بھی ملے۔ ماریو پوزو نے بحیثیت مدیر بھی کام کیا اور مضمون نگار کے طور پر بھی مشہور ہوئے۔ اس امریکی ادیب کے افسانوں اور ناولوں نے قارئین کو بہت متاثر کیا۔ خاص طور پر وہ جس طرح مافیا کے دھندوں اور تاریک دنیا کی کہانیاں لکھتے تھے، ان میں وہ اپنے تخیل اور قوّتِ مشاہدہ سے بڑا رنگ بھر دیتے ہیں۔ ماریو پوزو کا نام آج بھی عالمی ادب میں ان کے قلم کے اسی وصف کی بدولت زندہ ہے۔
ناول دی گاڈ فادر پر مبنی فلم کی بات کریں تو اس میں مافیا کے سربراہ بِیٹو کورلیون (گاڈ فادر) کو مصنّف نے ایک جہاں دیدہ شخص کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ نیویارک شہر کے پس منظر میں لکھی گئی کہانی ہے جس میں مافیا کے مختلف خاندان علاقہ اور غیرقانونی کاروبار کی دنیا میں اپنا راج برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اس دوران گاڈ فادر یعنی کورلیون فیملی بحران کا شکار ہوجاتی ہے اور اس میں قیادت کی تبدیلی بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ مصنّف کا کمال یہ ہے کہ اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے کرداروں کی ذہنی کشمکش اور ان کے رویے کو بیان کیا ہے اور یہی تفصیل اس کہانی کو مؤثر اور دل چسپ بناتی ہے۔ ناول کے کردار دنیاوی فہم و فراست اور ذہانت سے مالا مال ہیں لیکن مصنّف کی خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنے کرداروں کو فلسفہ بگھارے بغیر حکیمانہ انداز میں مکالمہ کرتے ہوئے پیش کیا ہے۔ اس ناول پر مبنی فلم کے ڈائریکٹر فرانسس فورڈ کپولا تھے اور اس میں مارلن برانڈو نے بھی کردار ادا کیا۔ ناول کے کئی فقرے بھی مشہور ہوئے تھے۔ یہ فلم 1972ء میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔
ایک زمانہ میں ماریو پوزو مالی مسائل کا شکار تھے اور مقروض ہوچکے تھے، جب کہ ان کو اپنی تخلیقات کی اشاعت سے مالی نفع نہیں مل رہا تھا۔ تب انھوں نے گاڈ فادر لکھنا شروع کیا اور حیران کن طور پر اس نے ماریو پازو کو شہرت اور مالی آسودگی بھی دی۔ اس ناول کا متعدد زبانوں میں ترجمہ کیا جاچکا ہے۔
ناول میں ماریو پوزو کے بیٹے کا ایک مضمون بھی شامل ہے جو لائقِ مطالعہ ہے۔ ان کے فرزند نے لکھا کہ والد کے دو ناول ناقدین نے تو پسند کیے مگر مالی فائدہ نہیں ملا۔ وہ مقروض تھے اور انہیں احساس تھا کہ کچھ بڑا کر کے دکھانا ہے۔ اسی جذبے کے تحت انھوں نے ناول گاڈ فادر لکھنا شروع کر دیا، جب بچّے شور کرتے تو ماریو پوزو کہتے، شور مت کرو، میں ایک شاہکار ناول لکھ رہا ہوں۔ اس پر بچّے ہنستے اور مزید شور کرنے لگتے۔ پھر سب نے دیکھا کہ گاڈ فادر واقعی بیسٹ سیلر ثابت ہوا۔ دو برسوں میں اس کی نوّے لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں اور ایک اہم بات یہ بھی کہ اسے نیویارک ٹائمز جیسے جریدے نے بیسٹ سیلر کتاب کی فہرست میں 67 ہفتے تک شامل رکھا۔