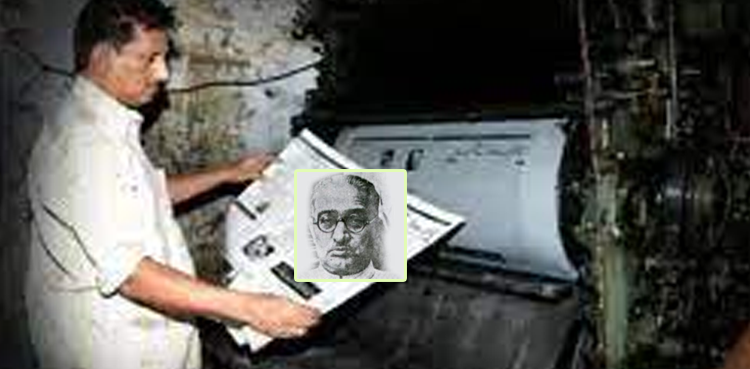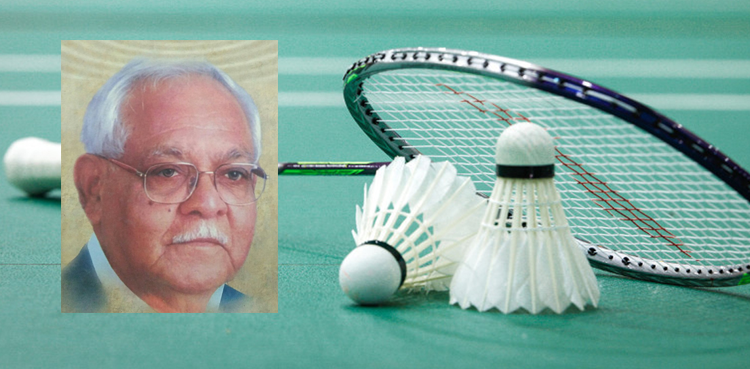منشی برکت علی عشاء کی نماز پڑھ کر چہل قدمی کرتے ہوئے امین آباد پارک تک چلے آئے۔
گرمیوں کی رات، ہوا بند تھی۔ شربت کی چھوٹی چھوٹی دکانوں کے پاس لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ لونڈے چیخ چیخ کر اخبار بیچ رہے تھے، بیلے کے ہار والے ہر بھلے مانس کے پیچھے ہار لے کر لپکتے۔ چوراہے پر تانگہ اور یکہ والوں کی لگاتار پکار جاری تھی۔
’’چوک! ایک سواری چوک! میاں چوک پہنچا دوں!‘‘
’’اے حضور کوئی تانگہ وانگہ چاہیے؟‘‘
’’ہار بیلے کے! گجرے موتیے کے!‘‘
’’کیا ملائی کی برف ہے۔‘‘
منشی جی نے ایک ہار خریدا، شربت پیا اور پان کھا کر پارک کے اندر داخل ہوئے۔ بنچوں پر بالکل جگہ نہ تھی۔ لوگ نیچے گھاس پر لیٹے ہوئے تھے۔ چند بے سُرے گانے کے شوقین ادھر ادھر شور مچا رہے تھے، بعض آدمی چپ بیٹھے دھوتیاں کھسکا کر بڑے اطمینان سے اپنی ٹانگیں اور رانیں کھجانے میں مشغول تھے۔ اسی دوران میں وہ مچھروں پر بھی جھپٹ جھپٹ کر حملے کرتے جاتے تھے۔
منشی جی چونکہ پا جامہ پوش آدمی تھے انھیں اس بد تمیزی پر بہت غصہ آیا۔ اپنے جی میں انھوں نے کہا کہ ان کم بختوں کو کبھی تمیز نہ آئے گی، اتنے میں ایک بنچ پر سے کسی نے انھیں پکارا۔
’’منشی برکت علی!‘‘
منشی جی مڑے۔ ’’اخاہ لالہ جی آپ ہیں، کہیے مزاج تو اچھے ہیں!‘‘
منشی جی جس دفتر میں نوکر تھے لالہ جی اس کے ہیڈ کلرک تھے۔ منشی جی ان کے ماتحت تھے۔ لالہ جی نے جوتے اتار دیے تھے اور بنچ کے بیچوں بیچ پیر اٹھا کر اپنا بھاری بھرکم جسم لیے بیٹھے تھے۔ وہ اپنی توند پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے جاتے اور اپنے ساتھیوں سے جو بنچ کے دونوں کونوں پر ادب سے بیٹھے ہوئے تھے چیخ چیخ کر باتیں کر رہے تھے۔ منشی جی کو جاتے دیکھ کر انھوں نے انھیں بھی پکار لیا۔ منشی جی لالہ صاحب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔
لالہ جی ہنس کے بولے، ’’کہو منشی برکت علی، یہ ہار وار خریدے ہیں کیا، ارادے کیا ہیں؟‘‘ اور یہ کہہ کر زور سے قہقہہ لگا کر اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف داد طلب کرنے کو دیکھا۔ انھوں نے بھی لالہ جی کا منشا دیکھ کر ہنسنا شروع کیا۔
منشی جی بھی روکھی پھیکی ہنسی ہنسے، ’’جی ارادے کیا ہیں، ہم تو آپ جانیے غریب آدمی ٹھہرے، گرمی کے مارے دم نہیں لیا جاتا، راتوں کی نیند حرام ہو گئی، یہ ہار لے لیا شاید دو گھڑی آنکھ لگ جائے۔‘‘
لالہ جی نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہنسے، ’’شوقین آدمی ہو منشی‘‘ کیوں نہ ہو!‘‘ اور یہ کہہ کر پھر اپنے ساتھیوں سے گفتگو میں مشغول ہو گئے۔
منشی جی نے موقع غنیمت جان کر کہا، ’’اچھا لالہ جی چلتے ہیں، آداب عرض ہے۔‘‘ اور یہ کہہ کر آگے بڑھے۔ دل ہی دل میں کہتے تھے کہ دن بھر کی گھس گھس کے بعد یہ لالہ کمبخت سر پڑا۔ پوچھتا ہے ارادے کیا ہیں! ہم کوئی رئیس تعلق دار ہیں کہیں کے کہ رات کو بیٹھ کر مجرا سنیں اور کوٹھوں کی سیر کریں، جیب میں کبھی چونی سے زیادہ ہو بھی سہی، بیوی، بچے، ساٹھ روپیہ مہینہ، اوپر سے آدمی کا کچھ ٹھیک نہیں، آج نہ جانے کیا تھا جو ایک روپیہ مل گیا۔ یہ دیہاتی اہل معاملہ کمبخت روز بروز چالاک ہوتے جاتے ہیں۔ گھنٹوں کی جھک جھک کے بعد جیب سے ٹکا نکالتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ غلام خرید لیا، سیدھے بات نہیں کرتے۔ کمینہ نیچے درجے کے لوگ ان کا سر پھر گیا ہے۔ آفت ہم بیچارے شریف سفید پوشوں کی ہے۔ ایک طرف تو نیچے درجے کے لوگوں کے مزاج نہیں ملتے، دوسری طرف بڑے صاحب اور سرکار کی سختی بڑھتی جاتی ہے۔ ابھی دو مہینے پہلے کا ذکر ہے، بنارس کے ضلع میں دو محرر بیچارے رشوت ستانی کے جرم میں برخواست کر دیے گئے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے غریب بیچارہ پستا ہے، بڑے افسر کا بہت ہوا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ ہو گیا۔
’’منشی جی صاحب۔‘‘ کسی نے بازو سے پکارا۔ جمن چپراسی کی آواز۔
منشی جی نے کہا، ’’اخاہ تم ہو جمن۔‘‘
مگر منشی جی چلتے رہے رکے نہیں۔ پارک سے مڑ کر نظیر آباد میں پہنچ گئے۔ جمن ساتھ ساتھ ہو لیا۔ دبلے پتلے، پستہ قد، مخمل کی کشتی نما ٹوپی پہنے، ہار ہاتھ میں لیے، آگے آگے منشی جی اور ان سے قدم دو قدم پیچھے چپراسی جمن۔
منشی جی نے سوچنا شروع کیا کہ آخر اس وقت جمن کا میرے ساتھ ساتھ چلنے میں کیا مقصد کیا ہے۔
’’کہو بھئی جمن، کیا حال ہے۔ ابھی پارک میں ہڈ کلارک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی وہ بھی گرمی کی شکایت کرتے تھے۔‘‘
’’اجی منشی جی کیا عرض کروں، ایک گرمی صرف تھوڑی ہے مارے ڈالتی ہے، ساڑھے چار پانچ بجے دفتر سے چھٹی ملی۔ اس کے بعد سیدھے وہاں سے بڑے صاحب کے ہاں گھر پر حاضری دینی پڑی۔ اب جا کر وہاں سے چھٹکارا ہوا تو گھر جا رہا ہوں، آپ جانیے کہ دس بجے صبح سے رات کے آٹھ بجے تک دوڑ دھوپ رہتی ہے، کچہری کے بعد تین دفعہ دوڑ دوڑ کر بازار جانا پڑا۔ برف، ترکاری، پھل سب خرید کے لاؤ اور اوپر سے ڈانٹ الگ پڑتی ہے، آج داموں میں ٹکا زیادہ کیوں ہے اور یہ پھل سڑے کیوں ہیں۔ آج جو آم خرید کے لے گیا تھا وہ بیگم صاحب کو پسند نہیں آئے، واپسی کا حکم ہوا۔ میں نے کہا حضور! اب رات کو بھلا یہ واپس کیسے ہوں گے، تو جواب ملا ہم کچھ نہیں جانتے کوڑا تھوڑی خریدنا ہے۔ سو حضور یہ روپیہ کے آم گلے پڑے، آم والے کے ہاں گیا تو ایک تُو تُو میں میں کرنی پڑی، روپیہ آم بارہ آنے میں واپس ہوئے، چونی کو چوٹ پڑی مہینہ کا ختم، اور گھر میں حضور قسم لے لیجیے جو سوکھی روٹی بھی کھانے کو ہو۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں اور کون سا منہ لے کر جورو کے سامنے جاؤں۔‘‘
منشی جی گھرائے آخر جمن کا منشا اس ساری داستان کے بیان کرنے سے کیا تھا۔ کون نہیں جانتا کہ غریب تکلیف اٹھاتے ہیں اور بھوکے مرتے ہیں۔ مگر منشی جی کا اس میں کیا قصور؟ ان کی زندگی خود کون بہت آرام سے کٹتی ہے، منشی جی کا ہاتھ بے ارادہ اپنی جیب کی طرف گیا۔ وہ روپیہ جو آج انھیں اوپر سے ملا تھا صحیح سلامت جیب میں موجود تھا۔
’’ٹھیک کہتے ہو میاں جمن، آج کل کے زمانے میں غریبوں کی مرن جسے دیکھو یہی رونا روتا ہے، کچھ گھر میں کھانے کو نہیں۔ سچ پوچھو تو سارے آثار بتاتے ہیں کہ قیامت قریب ہے۔ دنیا بھر کے جعلیے تو چین سے مزے اڑاتے ہیں اور جو بیچارے اللہ کے نیک بندے ہیں انھیں ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے۔ ‘‘
جمن چپ چاپ منشی جی کی باتیں سنتا ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ منشی جی یہ سب کہتے تو جاتے تھے مگر ان کی گھبراہٹ بھی بڑھتی جاتی تھی۔ معلوم نہیں ان کی باتوں کا جمن پر کیا اثر ہو رہا تھا۔
’’کل جمعہ کی نماز کے بعد مولانا صاحب نے آثارِ قیامت پر وعظ فرمایا، میاں جمن سچ کہتا ہوں، جس جس نے سنا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بھائی دراصل یہ ہم سب کی سیاہ کاریوں کا نتیجہ ہے، خدا کی طرف سے جو کچھ عذاب ہم پر نازل ہو وہ کم ہے۔ کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں؟ اس سے کم قصور پر اللہ نے بنی اسرائیل پر جو جو مصیبیں نازل کیں ان کا خیال کر کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مگر وہ تو تم جانتے ہی ہوگے۔‘‘
جمن بولا، ’’ہم غریب آدمی منشی جی، بھلا یہ سب علم کی باتیں کیا جانیں، قیامت کے بارے میں تو میں نے سنا ہے مگر حضور آخر یہ بنی اسرائیل بیچارے کون تھے۔‘‘
اس سوال کو سن کر منشی جی کو ذرا سکون ہوا۔ خیر غربت اور فاقے سے گزر کر اب قیامت اور بنی اسرائیل تک گفتگو کا سلسلہ پہنچ گیا تھا۔ منشی جی خود کافی طور پر اس قبیلے کی تاریخ سے واقف نہ تھے مگر ان مضمونوں پر گھنٹوں باتیں کر سکتے تھے۔
’’ایں! واہ میاں جمن واہ، تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو اور یہ نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل کس چڑیا کا نام ہے۔ میاں سارا کلام پاک بنی اسرائیل کے ذکر سے تو بھرا پڑا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نام بھی تم نے سنا ہے؟‘‘
’’جی کیا فرمایا آپ نے؟ کلیم اللہ؟‘‘
’’ارے بھئی حضر ت موسیٰ۔ مو۔۔۔ سا۔‘‘
’’موسا۔۔۔ وہی تو نہیں جن پر بجلی گری تھی؟‘‘
منشی جی زور سے ٹھٹھا مار کر ہنسے۔ اب انھیں بالکل اطمینان ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ قیصر باغ کے چوراہے تک بھی آ پہنچے تھے۔ یہاں پر تو ضرور ہی اس بھوکے چپراسی کا ساتھ چھوٹے گا۔ رات کو اطمینان سے جب کوئی کھانا کھا کر نماز پڑھ کر، دم بھر کی دل بستگی کے لیے چہل قدمی کو نکلے، تو ایک غریب بھوکے انسان کا ساتھ ساتھ ہو جانا، جس سے پہلے کی واقفیت بھی ہو، کوئی خوش گوار بات نہیں۔ مگر میاں جی آخر کرتے کیا؟ جمن کو کتّے کی طرح دھتکار تو سکتے نہ تھے کیوں کہ ایک تو کچہری میں روز کا سامنا، دوسرے وہ نیچے درجے کا آدمی ٹھہرا، کیا ٹھیک، کوئی بدتمیزی کر بیٹھے تو سرِ بازار خواہ مخواہ کو اپنی بنی بنائی عزت میں بٹہ لگے۔ بہتر یہی تھا کہ اب اس چوراہے پر پہنچ کر دوسری راہ لی جائے اور یوں اس چھٹکارا ہو۔
’’خیر، بنی اسرائیل اور موسیٰ کا ذکر میں تم سے پھر کبھی پوری طرح کروں گا، اس وقت تو ذرا مجھے ادھر کام سے جانا ہے۔ سلام میاں جمن۔‘‘
یہ کہہ کر منشی جی قیصر باغ کے سینما کی طرف بڑھے۔ منشی جی کو یوں تیز قدم جاتے دیکھ کر پہلے تو جمن ایک لمحہ کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا کا کھڑا رہ گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ آخر کرے تو کیا کرے۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اس کی آنکھیں ایک بے معنی طور پر ادھر ادھر مڑیں۔ تیز بجلی کی روشنی، فوّارہ، سینما کے اشتہار، ہوٹل، دکانیں، موڑ، تانگے، یکے اور سب کے اوپر تاریک آسمان اور جھلملاتے ہوئے ستارے غرض خدا کی ساری بستی۔
دوسرے لمحہ میں جمن منشی جی کی طرف لپکا۔ وہ اب کھڑے سینما کے اشتہار دیکھ رہے تھے اور بے حد خوش تھے کہ جمن سے جان چھوٹی۔
جمن نے ان کے قریب پہنچ کر کہا، ’’منشی جی!‘‘
منشی جی کا کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ ساری مذہبی گفتگو، ساری قیامت کی باتیں، سب بیکار گئیں۔ منشی جی نے جمن کو کچھ جواب نہیں دیا۔
جمن نے کہا، ’’منشی جی اگر آپ اس وقت مجھے ایک روپیہ قرض دے سکتے ہوں تو میں ہمیشہ…‘‘
منشی جی مڑے، ’’میاں جمن میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت تنگی میں ہو مگر تم تو خود جانتے ہو کہ میرا اپنا کیا حال ہے۔ روپیہ تو روپیہ ایک پیسہ تک میں تمہیں نہیں دے سکتا، اگر میرے پاس ہوتا تو بھلا تم سے چھپانا تھوڑا ہی تھا، تمہارے کہنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی پہلے ہی جو کچھ ہوتا تمہیں دے دیتا۔‘‘
باوجود اس کے جمن نے اصرار شروع کیا، ’’منشی جی! قسم لے لیجیے میں ضرور آپ کو تنخواہ ملتے ہی واپس کر دوں گا، سچ کہتا ہوں حضور اس وقت کوئی میری مدد کرنے والا نہیں۔‘‘
منشی جی اس جھک جھک سے بہت گھبراتے تھے۔ انکار چاہے وہ سچا ہی کیوں نہ ہو تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ شروع سے چاہتے تھے کہ یہاں تک نوبت ہی نہ آئے۔
اتنے میں سینما ختم ہوا اور تماشائی اندر سے نکلے۔ ’’ارے میاں برکت، بھئی تم کہاں؟‘‘ کسی نے پہلو سے پکارا۔
منشی جی جمن کی طرف سے ادھر مڑے۔ ایک صاحب موٹے تازے، تیس پینتیس برس کے۔ انگھرکھا اور دوپلی ٹوپی پہنے، پان کھائے، سگریٹ پیتے ہوئے منشی جی کے سامنے کھڑے تھے۔
منشی جی نے کہا، ’’اخاہ تم ہو! برسوں کے بعد ملاقات ہوئی، تم نے لکھنؤ تو چھوڑ ہی دیا؟ مگر بھائی کیا معلوم آتے بھی ہوگے تو ہم غریبوں سے کیوں ملنے لگے!‘‘
یہ منشی جی کے پرانے کالج کے ساتھی تھے۔ روپے، پیسے والے رئیس آدمی، وہ بولے،
’’خیر یہ سب باتیں تو چھوڑو، میں دو دن کے لیے یہاں آیا ہوں، ذرا لکھنؤ میں تفریح کے لیے چلو، اس وقت میرے ساتھ چلو تمہیں وہ مجرا سنواؤں کہ عمر بھر یاد کرو، میری موٹر موجود ہے، اب زیادہ مت سوچو، بس چلے چلو، سنا ہے تم نے کبھی نور جہاں کا گانا؟ اہا ہا ہا کیا گاتی ہے، کیا بتاتی ہے، کیا ناچتی ہے، وہ ادا، وہ پھبن، اس کی کمر کی لچک، اس کے پاؤں کے گھنگھرو کی جھنکار! میرے مکان پر، کھلے صحن میں، تاروں کی چھاؤں میں، محفل ہوگی۔ بھیروی سن کر جلسہ برخاست ہوگا۔ بس اب زیادہ نہ سوچو، چلے ہی چلو۔ کل اتوار ہے۔ بیوی! بیگم صاحبہ کی جوتیوں کا ڈر ہے، اگر ایسا ہی عورت کی غلامی کرنا تھی تو شادی کیوں کی؟ چلو بھی میاں! لطف رہے گا، روٹھی بیگم کو منانے میں بھی تو مزہ ہے۔‘‘
پرانا دوست، موٹر کی سواری، گانا ناچ، جنت نگاہ، فردوس گوش منشی جی لپک کر موٹر میں سوار ہو لیے۔ جمن کی طرف ان کا خیال بھی نہ گیا۔ جب موٹر چلنے لگی تو انھوں نے دیکھا کہ وہ وہاں اسی طرح چپ کھڑا ہے۔
(اس کہانی کے مصنّف ترقی پسند ادیب سجاد ظہیر نام ور فکشن رائٹر اور افسانہ نگار ہیں، انھوں نے اپنی کہانی میں ہندوستانی سماج کی ناہمواری کی بہت باریکی سے عکاسی کی ہے۔ یہ ایک ہی دفتر میں کام کرنے والے دو افراد کی محرومیوں اور بناوٹی زندگی اور دہرے کردار کو سامنے لاتی ہے۔)