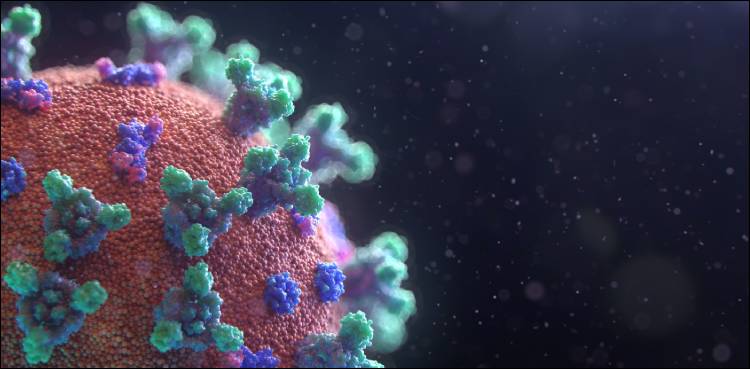کرونا وائرس کی وبا دنیا کے لیے ایک یاد دہانی ہے جس میں فطرت نے ہمیں بھرپور طریقے سے احساس دلایا کہ ترقی کی دوڑ میں ہم اس قدر تیز بھاگ رہے ہیں کہ نفع نقصان کا فرق بھی بھول چکے ہیں۔
ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہماری دہائیوں اور صدیوں کی ترقی اور معیشت کا پہیہ فطرت کے صرف ایک وار سے جھٹکے سے رک گیا اور پوری دنیا کا نظام اتھل پتھل ہوگیا۔
ماہرین کے مطابق جس بے دردی سے ہم زمین کے پائیدار وسائل کو ضائع کر رہے تھے اور صرف یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ زمین صرف انسانوں کے لیے ہے، اس کے ردعمل میں یہ جھٹکا نہایت معمولی ہے، اور اگر ہم اب بھی نہ سنبھلے تو آئندہ جھٹکے اس قدر خطرناک ہوسکتے ہیں کہ پوری نسل انسانیت کو بقا کا خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اب بھی اس وبا سے کچھ سیکھا ہے یا ہم اپنی پرانی روش پر قائم رہیں گے؟
ایک تحقیق کے مطابق اکثر قدرتی آفات اور وباؤں کو دعوت دینے والا خود انسان ہی ہے جو دنیا بھر میں اپنی سرگرمیوں سے فطرت اور ماحول کے سسٹم میں خلل ڈال رہا ہے اور ان میں خرابی پیدا کر رہا ہے۔
ماہرین کا ماننا ہے کہ کرونا وائرس بھی ان وباؤں میں سے ایک ہے جو انسان کی اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے انہیں متاثر کر رہی ہے، یعنی اگر ہم اپنی حدود میں رہتے ہوئے فطرت سے چھیڑ چھاڑ نہ کرتے تو یہ وبا شاید انسانوں تک نہ پہنچتی۔
یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری وہ کون سی سرگرمیاں ہیں جو ہمارے ہی لیے نقصان دہ ثابت ہورہی ہیں، اور ہم خود کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟
انٹر گورنمنٹل سائنس پالیسی پلیٹ فارم آن بائیو ڈائیورسٹی اینڈ ایکو سسٹم سروس (IPBES) کی سنہ 2020 میں جاری کی جانے والی رپورٹ کے مطابق انسانوں میں پھیلنے والے تقریباً ایک تہائی متعدی امراض ایسے ہیں جو جانوروں سے منتقل ہوئے، اس وقت 17 لاکھ وائرسز ایسے ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوسکے اور یہ ممالیہ جانداروں اور پرندوں میں موجود ہیں، ان میں سے نصف ایسے ہیں جو انسانوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
وجہ؟ انسانوں کا جانوروں سے غیر ضروری رابطہ۔ اس کے خطرناک نقصانات کو ماہر ماحولیات سنیتا چوہدری نے نہایت تفصیل سے بتایا، سنیتا چوہدری مختلف ممالک میں ماہر جنگلات کے طور پر کام کرچکی ہیں جبکہ آج کل وہ نیپال کے تحفظ ماحولیات کے ادارے آئی سی موڈ سے بطور ایکو سسٹم سروس اسپیشلسٹ وابستہ ہیں۔
سنیتا چوہدری کہتی ہیں کہ انسانوں کا غیر قانونی شکار اور جانوروں کی تجارت کا جنون انہیں سخت نقصان پہنچا رہا ہے، اس تجارت کے لیے وہ جنگلات میں جانوروں کے مساکن (Habitat) میں مداخلت کرتے ہیں اور یہیں سے وہ متعدد وائرسز اور جراثیموں کا شکار بن سکتے ہیں۔
سنیتا چوہدری کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں بطور غذا یا ادویات کی تیاری میں مختلف جانوروں کا استعمال کیا جارہا ہے، ایک اور وجہ گھروں میں جنگلی جانور پالنے کا انسان کا غیر معمولی شوق ہے جس کے دوران تمام خطرات اور احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کردیا جاتا ہے۔
ایک تحقیق کے مطابق جنگلات کی کٹائی بھی انسانوں میں مختلف بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ جنگلات میں رہنے والے جانور جنگل کٹنے کے بعد انسانی آبادیوں کے ارد گرد رہنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات ہم خود ہی جنگلات یا پہاڑوں کو کاٹ کر وہاں رہائشی آبادیاں بنا کر انسانوں کو بسا دیتے ہیں۔
ان تمام عوامل کے نتیجے میں ہم جانوروں کے جسم میں پلنے والے ان وائرسز، جرثوموں اور بیماریوں کے حصے دار بن جاتے ہیں جو جانوروں میں تو اتنے فعال نہیں ہوتے، لیکن انسانوں پر کاری وار کرسکتے ہیں۔
کیا کلائمٹ چینج بھی وباؤں کو جنم دے سکتا ہے؟
سنہ 2011 میں رشین اکیڈمی آف سائنس سے منسلک ماہرین نے اپنی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا کہ موسمیاتی تغیرات یعنی کلائمٹ چینج کے باعث درجہ حرارت بڑھنے کا عمل (جسے گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے) جہاں ایک طرف تو زمینی حیات کے لیے کئی خطرات کو جنم دے رہا ہے، وہاں وہ ان جراثیم اور وائرسز کو پھر سے زندہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے جنہوں نے کئی صدیوں قبل لاکھوں کروڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔
یہ تحقیق برفانی خطے آرکٹک میں کی گئی تھی جہاں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ٹنوں برف پگھل رہی تھی، ایسے میں برف کے نیچے دبے صدیوں پرانے وائرس اور جراثیم جلد یا بدیر ظاہر ہونے کے قریب تھے۔
اس کی ایک مثال اگست 2016 میں دیکھنے میں آئی جب سائبریا کے ایک دور دراز علاقے میں ایک 12 سالہ لڑکا جانوروں کو ہونے والی ایک بیماری انتھراکس کا شکار ہو کر ہلاک ہوگیا جبکہ 20 کے قریب افراد اس مرض کا شکار ہو کر اسپتال پہنچ گئے۔
ماہرین نے جب اس وبا کے اچانک پھیلاؤ کے عوامل پر تحقیق کی تو انہیں علم ہوا کہ تقریباً 75 سال قبل اس مرض سے متاثر ایک بارہ سنگھا اسی مقام پر ہلاک ہوگیا تھا۔
سال گزرتے گئے اور بارہ سنگھے کے مردہ جسم پر منوں برف کی تہہ جمتی گئی، لیکن سنہ 2016 میں جب گرمی کی شدید لہر یعنی ہیٹ ویو نے سائبیریا کے برفانی خطے کو متاثر کیا اور برف پگھلنا شروع ہوئی تو برف میں دبے ہوئے اس بارہ سنگھے کی باقیات ظاہر ہوگئیں اور اس میں تاحال موجود بیماری کا وائرس پھر سے فعال ہوگیا۔
اس وائرس نے قریب موجود فراہمی آب کے ذرائع اور گھاس پر اپنا ڈیرا جمایا جس سے وہاں چرنے کے لیے آنے والے 2 ہزار کے قریب بارہ سنگھے بھی اس بیماری کا شکار ہوگئے۔
بعد ازاں اس وائرس نے محدود طور پر انسانوں کو بھی متاثر کیا جن میں سے ایک 12 سالہ لڑکا اس کا شکار ہو کر ہلاک ہوگیا۔
یہ صرف ایک مثال تھی، ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی درجہ حرارت بڑھنے کے باعث جیسے جیسے زمین کے مختلف مقامات کی برف پگھلتی جائے گی، ویسے ویسے مزید مہلک اور خطرناک بیماریاں پیدا کرنے والے وائرسز پھر سے نمودار ہو جائیں گے۔
یہاں یہ یاد رہے کہ برف میں جم جانے سے کوئی جسم بغیر کسی نقصان کے صدیوں تک اسی حالت میں موجود رہ سکتا ہے، جبکہ اس طرح جم جانا کسی وائرس یا بیکٹیریا کے لیے بہترین صورتحال ہے کیونکہ وہاں آکسیجن نہیں ہوتی اور ماحول سرد اور اندھیرا ہوتا ہے چنانچہ اس طرح وہ لاکھوں سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا بعید از قیاس نہیں کہ لاکھوں سال پرانے وائرس اور جراثیم، جن کے نام بھی ہم نہ جانتے ہوں گے، ہم پر پھر سے حملہ آور ہوسکتے ہیں۔
گزشتہ برس یورپی یونین کی جانب سے کی گئی ایک تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے بڑھتا ہوا درجہ حرارت یعنی گلوبل وارمنگ اکثر متعدی امراض میں اضافے کا سبب ہے جیسے ملیریا اور زیکا وغیرہ، اور یہ بات اب طے ہوچکی ہے کہ زمین پر کلائمٹ چینج کی وجہ انسان کی بے پناہ صنعتی ترقی اور اس سے خارج ہونے والی مضر گیسز ہیں۔
سنیتا چوہدری کہتی ہیں کہ برف پگھلنے کی صورت میں سامنے آنے والے وائرسز کی تعداد اور خطرناکی لامحدود ہوگی، گلوبل وارمنگ ان وائرسز کو مزید فعال اور طاقتور کردے گی، یوں ہمارے سامنے ان گنت خطرات موجود ہیں۔
کیا ہم بچاؤ کے اقدامات کرسکتے ہیں؟
یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم ان عوامل کو روکنے یا ان کی رفتار دھیمی کرنے کے قابل ہیں؟ اور ایسا کر کے کیا ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟
اس حوالے سے سنیتا چوہدری کہتی ہیں کہ کووڈ 19 ہمارے لیے ایک وارننگ ہے کہ انسانوں کا فطرت سے تعلق نہایت ہی غیر صحت مندانہ ہے، ہم فطرت کو ایک پروڈکٹ کی طرح استعمال کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہمیں اس سے بہتر تعلق قائم کر کے فطرت کو اپنے لیے، اور خود کو فطرت کے لیے فائدہ مند بنانا چاہیئے۔
سنیتا کے مطابق اگر ہم قدرتی ماحول اور فطرت کو احسن اور پائیدار طریقے سے استعمال کریں تو یہ انسانوں اور مختلف وبائی امراض کے درمیان ایک ڈھال کا کردار ادا کر سکتی ہے، ہمیں فطرت کا تحفظ کرنے کی ضرورت ہے اور ضروری ہے کہ انسانوں اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی کا رشتہ ہو۔
سنیتا کے مطابق مندرجہ ذیل اقدامات کی صورت میں ہم نہ صرف ماحول کا بلکہ مختلف خطرات سے اپنا بھی بچاؤ کر سکتے ہیں۔
دنیا بھر میں ایکو سسٹم کی بحالی، فطری حسن اور وہاں کی مقامی جنگلی حیات کا تحفظ
زراعت میں رائج پرانے طریقوں کو چھوڑ کر جدید طریقے اپنانا جو بدلتے موسموں سے مطابقت رکھتے ہوں
جانوروں کے لیے محفوظ علاقوں کا قیام
آبی ذخائر کی بحالی اور ان کا تحفظ
ماہرین کا کہنا ہے کہ فطرت کا تحفظ اب ہمارے لیے ایسی ضرورت بن گئی ہے جو ہماری اپنی بقا کے لیے ضروری ہے، ورنہ ہماری اپنی ترقی ہی ہمارے لیے ناقابل تلافی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔