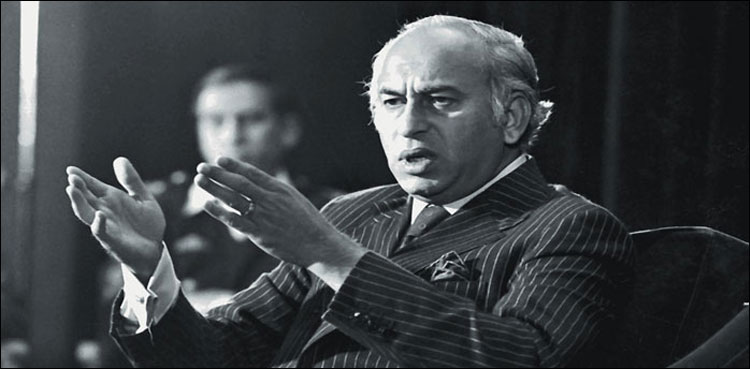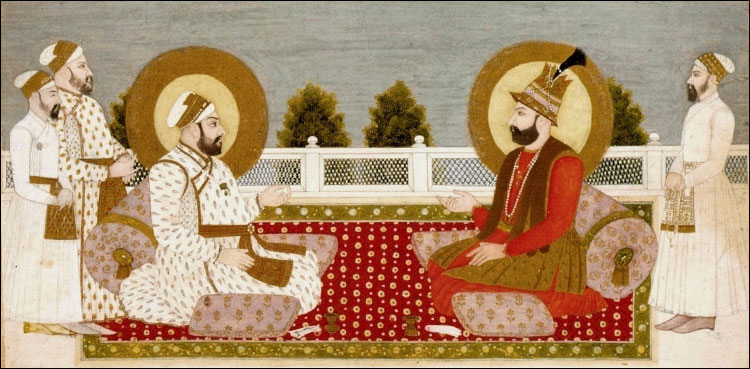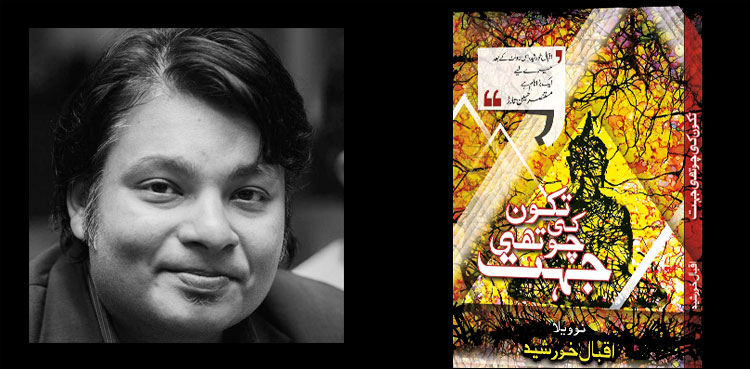خیبرپختونخواہ کا علاقہ جنوبی وزیر ستان ان دنوں ’لشمینیا‘ نامی بیماری کی زد میں ہے ، یہ بیماری ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے اور اس میں متاثرہ جگہ پر زخم ہوجاتے ہیں، ماہرین کے مطابق علاج مہنگا ہے اور ویکسین تاحال دریافت نہیں ہوسکی ہے۔
جنوبی وزیر ستان میں لشمینیا کے لگ بھگ 350 کیسز ریکارڈ ہوچکے ہیں جبکہ اس سے قبل اٹک میں بھی اس حوالے سے دوسو سے زائد کیسز سامنے آئے تھے۔ یہ بیماری چھوٹےبھورے رنگ کے مچھرڈنک مار نے پھیلتی ہے۔ یہ بھورا مچھر دیکھنے میں تو عام مچھروں کی طرح ہی لگتا ہےلیکن انسانی جلد میں اسکا زہر پھیلنے لگتا ہے۔ مچھر کا شکار بننے کے فوری بعد اسکے اثرات سامنے نہیں آتے بلکہ مچھر کے ڈنک مارنے اور دانہ نکلنے کے درمیان دو سے چار مہینے لگتے ہیں۔
ایک بار جب دانہ نمودار ہوجاتا ہے تواس کا حجم بڑھنا شروع ہوجاتا ہے جس کے سبب جلد مسلسل خشک ہوتی رہتی ہے اور اس پر کسی قسم کے مرہم ، لوشن یا کریم کارگر ثابت نہیں ہوتے۔
جنوبی وزیرستان میں ’لشمینیا‘ اس وقت وبائی صورت اختیار کرچکا ہے اور مختلف علاقوں میں موصولہ اطلاعات کے مطابق لشمینیا سے سینکڑوں افراد متاثر ہوئے ہیں تاہم علاج کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو دور دراز کے دیگر اضلاع بھیجا جارہا ہے۔جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں کوٹکائی، بدر، مکین، کانیگرام، کڑامہ، سرا روغہ، شکتوئی، سروکئی اور زغزئی میں لشمینیا بیماری سے سینکڑوں بچے اور نوجوان متاثر ہوئے ہے جبکہ مقامی ہسپتالوں میں انجیکشنز نہ ہونے کی وجہ سے متاثرہ افراد کو ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان بھیجا جارہا ہے۔
مقامی خبر رساں ذرائع کے مطابق جنوبی وزیرستان کے ایڈیشنل سرجن ولی رحمن کا کہنا ہے کہ اب تک لشمینیا کے 370 کے قریب کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں جبکہ انجکشنز 350 کے لگ بھگ ہیں، ہر مریض کو 8 سے 10 انجیکشن لگتے ہیں جو کہ ان مریضوں کےلئے ناکافی ہیں، لہذا مریضوں کو ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان منتقل کیا جارہا ہیں لیکن وہاں پر بھی انجیکشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ مریض پرائیویٹ علاج کروانے پر مجبور ہیں۔
محکمہ صحت ترجمان ڈاکٹرشاہین نے مقامی صحافتی ذرائع کو بتایا ہے کہ لشمینیا سے بچاؤ کی ایک انجیکشن تقریبا ساڑھے تین سو روپے کی ہے اور اس کی کوئی حفاظتی ویکسین فی الحال موجود نہیں۔ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس وائرس سے بچاؤ کیلئےصفائی کا خاص خیال رکھاجائے اور خود کو مچھروں سے بچایا جائے جب کہ گھروں میں مچھر مار اسپرے بھی کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ اس بیماری سے نوجوان بھی متاثر ہوئے ہیں تاہم بچوں کی تعداد کافی زیادہ ہیں۔
دوسری جانب متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ انتظامیہ صحت کے بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوچکی ہے۔ متاثرہ افراد کو ریلیف دینے کےلئے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے اور علاقے میں مچھر مار اسپرے نہ ہونے کے باعث لشمینیا مرض کے ساتھ ساتھ ملیریا اور ٹائیفائیڈ جیسے موضی امراض پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔
متاثرین کا کہنا ہے کہ ہیلتھ ڈائریکٹریٹ قبائلی اضلاع کی جانب سے لشمینیا مرض کے علاج کیلئے محکمہ صحت کو فراہم کردہ 300 گلوکینٹین انجیکشن منظور نظر افراد میں تقسیم کئے گئے ہیں جبکہ باقی لوگ پرائیویٹ علاج کرنے پر مجبور ہیں۔
لشمینیا سے متاثرہ علاقوں کے مشران نے آج 10 اپریل کو پولیٹیکل کمپاؤنڈ میں جرگہ طلب کیا ہے جس میں بیماری سے نبرد آزما ہونے کے لیے حکومت پر زور دیا جائے گا کہ وہ فی الفور متاثرہ علاقوں میں ادویات اور ڈاکٹر بھیجے۔ دوسری جانب خیبر پختونخواہ حکومت کے وزیر صحت نے اعلان کیا ہے کہ حکومت جلد ہی متاثرہ علاقوں میں ریلیف ٹیمیں بھیجے گی ، ساتھ ہی مریضوں کے لیے ادویات اور انجیکشن بھی فراہم کیےجائیں گے۔
لشمینیا کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ اسکن کینسر کی کوئی قسم ہے اور قبائلی علاقہ جات میں ہونے گزشتہ ادوار میں جاری جنگ کے دوران گولہ بارود کے استعمال سے ہورہی ہے۔
اس حوالے سے ایک مقامی سماجی کارکن حیات پریغال کا اپنی فیس بک پوسٹ میں کہنا ہے کہ لشمینیا کی بیماری نہ تو کسی بم بارود سے ہوتی ہے اور نہ ہی کسی دم درود سے ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ بیماری ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے اور اسکا علاج دوائیوں سے ہوتا ہے۔ ایل ڈی باڈیز نامی ٹیسٹ کرانے کے بعد علاج شروع ہوجاتا ہے اورمہینے دو مہینوں میں جسم پر پھیلا ہوا دانہ آہستہ آہستہ سوکھ جاتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جلوزئی کیمپ میں خیبر و باجوڑ ایجنسی کے ہزاروں مریضوں کا علاج اسی طرح کیا ہے۔ کیونکہ جمرود لنڈی کوتل باڑہ اور جلوزئی چراٹ کے علاقوں میں اور بلوچستان و افغانستان کے علاقوں میں یہ مچھر پایا جاتا ہے۔ سراروغہ کوٹکئی اور وانہ، میرعلی کا ماحول اس کی نشونماء کے لئے بہت ہی موزوں ہے۔
حیات نے یہ بھی لکھا کہ ان علاقوں میں پہلے اکا دکا کیس آتے تھے لیکن چونکہ علاقہ ایک عرصے تک بند رہا، جس کے سبب ان مچھروں کو گھروں اورمسجدوں میں نشونماء کا موقع ملا اوراب یہ بیماری پھیلانے میں مصروف ہیں۔