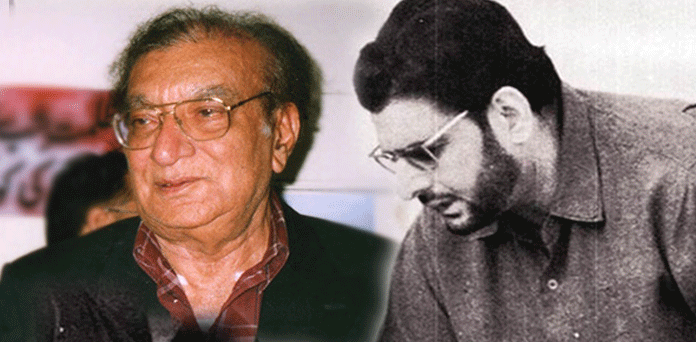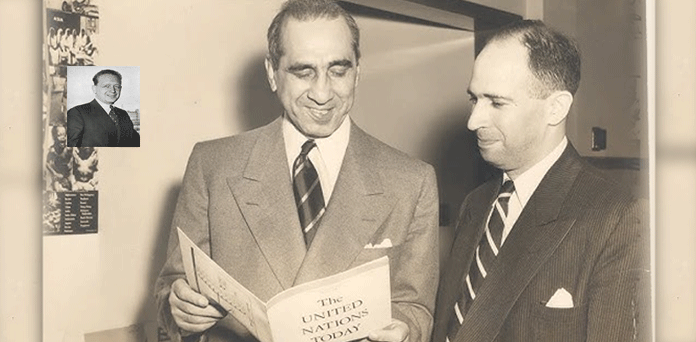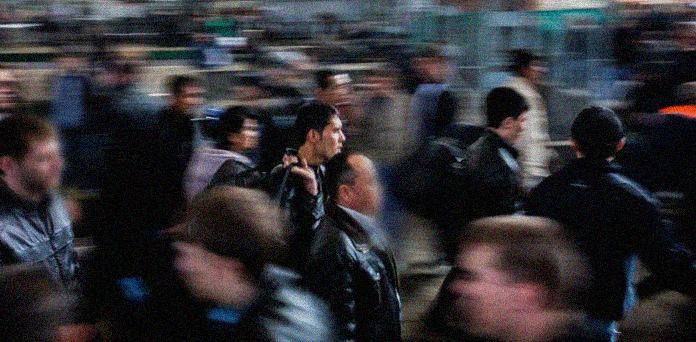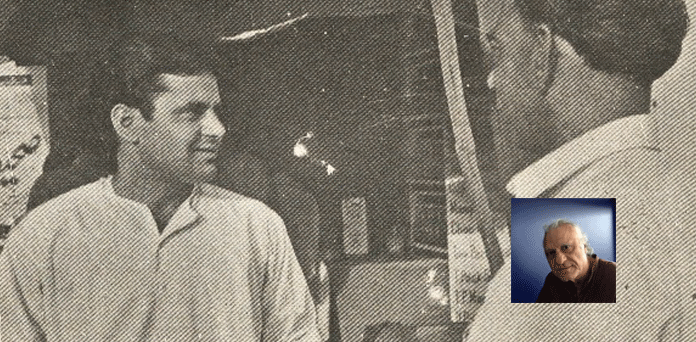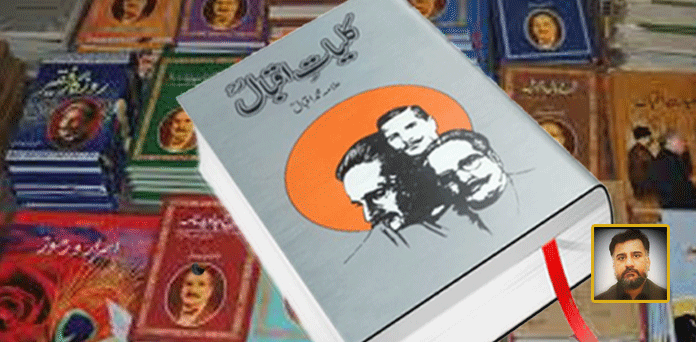کوثر نیازی پاکستان کے نامی گرامی سیاست داں تھے جن کا دور بطور مشیر اور وزیر کئی اعتبار سے ہنگامہ خیز اور متنازع بھی رہا، لیکن وہ صرف سیاست کے میدان میں متحرک نہیں رہے بلکہ ایک عالمِ دین، ادیب و شاعر اور عوام میں ایک زبردست مقرر کے طور بھی پہچانے گئے۔ پاکستان کے مقبول ترین شاعر احمد فراز اس دور میں آمریت کے خلاف اپنی مزاحمتی شاعری کی وجہ سے حکومتوں کے معتوب تھے۔ ان کی مولانا کوثر نیازی سے نہیں بنتی تھی۔
اس زمانے میں سرکاری اداروں اور حکومتی مالی امداد سے مختلف ادبی تنظمیوں کے پلیٹ فارم مشاعروں کا انعقاد کرتے تھے یہ ایک ایسے ہی مشاعرے کا دل چسپ احوال ہے جس میں کوثر نیازی اور احمد فراز نے اپنا کلام سنایا تھا۔ یہ معروف انشا پرداز اور ادیب منشا یاد کی کتاب ’’حسبِ منشا‘‘ سے لیا گیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔
گردیزی صاحب چیئرمین سی ڈی اے اور میں ان کا پی آر اوتھا۔ سی ڈی اے ہر سال یوم آزادی کے سلسلے میں ایک کل پاکستان مشاعرہ منعقد کرتا تھا جس میں فیض احمد فیض، احمد فراز اور حبیب جالب کو مدعو نہیں کیا جاتا تھا اور فراز تو ویسے بھی ان دنوں خود ساختہ جلاوطنی کے بعد لندن میں مقیم تھے۔ تاہم مجھے ان شعرا کی کمی بہت محسوس ہوتی لیکن یہ ایک سرکاری ادارہ تھا، اس لیے ہم حکومتی پالیسی کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے۔
اس مشاعرے میں ان تینوں کے سوا دوسرے شہروں سے تقریباً سبھی اہم شعرا جیسے حفیظ جالندھری، احمد ندیم قاسمی، جمیل الدین عالی، احسان دانش، ظہور نظر، قتیل شفائی، منیر نیازی، وزیر آغا، پروین شاکر، خاطر غزنوی، دلاور فگار، شریف کنجاہی، شہزاد احمد، ظفر اقبال، عارف عبدالمتین، عاصی کرنالی، امجد اسلام امجد، عطاء الحق قاسمی، اسلم انصاری، نوشابہ نرگس، مظفر وارثی، ریاض مجید، ارشد ملتانی، محسن احسان، جوگی جہلمی، جانباز جتوئی، حمایت علی شاعر، چانگ شی شوئن (انتخاب عالم)، نصیر ترابی اور بعض دیگر شعرا شامل ہوتے رہے۔ لیکن فیض، فراز اور حبیب جالب کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ دور اور جنرل ضیاء الحق کے گزر جانے کے بعد جب سی ڈی اے کا مشاعرہ منعقد ہوا اور احمد فراز شہر میں موجود تھے تو میں نے انہیں مشاعرے میں شرکت کے لیے فون کیا۔
انہوں نے صدر اور مہمانِ خصوصی وغیرہ کے بارے میں استفسار کیا تو میں نے بتایا کہ سید ضمیر جعفری صدارت کریں گے اور مولانا کوثر نیازی مہمانِ خصوصی ہوں گے۔ اس پر فراز صاحب نے مشاعرے میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی۔میں نے بہت اصرار کیا مگر وہ نہ مانے۔ میں نے اپنے افسران کو بتا دیا کہ فراز نہیں مان رہے۔ لیکن مولانا اسلام آباد سے سینیٹر تھے اور سی ڈی اے کے کچھ مالی مفادات ان سے وابستہ تھے اس لیے انہیں نظرانداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔
ادھر احمد فراز کے بغیر مشاعرے کا کچھ لطف نہ آتا۔ ان دنوں ناصر زیدی، احمد فراز کے بہت قریب تھے اور یوں بھی وہ مشاعروں کے انتظامات اور رابطوں کے ماہر تصور کئے جاتے تھے۔ میں نے ان سے سفارش کرائی مگر فراز پھر بھی نہ مانے۔ جب میں نے بہت مجبور کیا تو اس شرط پر راضی ہوئے کہ وہ مولانا کے ساتھ اسٹیج پر نہیں بیٹھیں گے۔ ان کو پڑھوانے کا الگ انتظام کیا جائے۔ میں نے ان کی یہ شرط مان لی اور وہ آگئے۔ یہ مشاعرہ مقامی ہوٹل کے سوئمنگ پول کے کنارے ہو رہا تھا۔ میں خود انتظامی امور میں مصروف تھا اس لیے میں نے پروین شاکر سے نظامت کے لیے کہا۔ مگر وہ دیر سے آئیں اور میں نے ایک ایک کر کے شعرا کو اسٹیج پر بلایا اور مشاعرہ شروع کرا دیا۔ احمد فراز حسبِ وعدہ سامعین میں بیٹھ گئے۔ میں نے اشاروں سے ان کی منت سماجت کی کہ وہ اسٹیج پر آجائیں مگر وہ نہ مانے۔
تھوڑی دیر میں پروین شاکر آگئیں تو میں نے نظامت ان کے حوالے کی اور ان سے کہا کہ وہ فراز صاحب سے کہیں کہ اسٹیج پر آجائیں کیوں کہ لوگ انہیں اسٹیج پر نہ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے بلکہ چہ میگوئیاں کر رہے تھے۔ پروین نے بھی انہیں اشاروں سے اسٹیج پر آنے کے لیے اصرار کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اس کی بات نہیں ٹالیں گے مگر احمد فراز اپنی ضد پر قائم رہے۔ پھر جب ان کی باری آئی تو روسٹرم اسٹیج سے نیچے لایا گیا اور انہوں نے ’’سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں…‘‘ والی غزل پہلی بار اس مشاعرے میں سنائی جو بعد میں بہت مشہور ہوئی۔
لطف کی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اس پر داد دیتے اور سر ہلاتے رہے لیکن جب مولانا صاحب کے پڑھنے کی باری آئی تو احمد فراز سگریٹ سلگا کر منہ سے دھواں نکالتے ہوئے مشاعرے سے اٹھ کر چلے گئے اور ان کے پڑھ لینے کے بعد اسی طرح منہ سے دھواں نکالتے کہیں سے نمودار ہو گئے۔