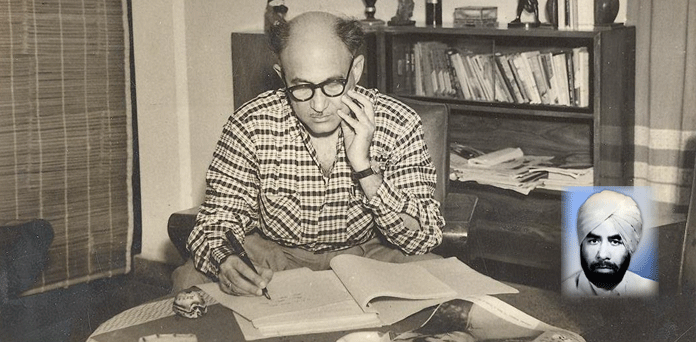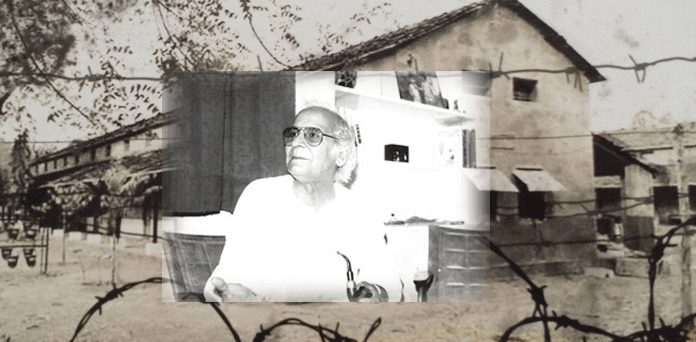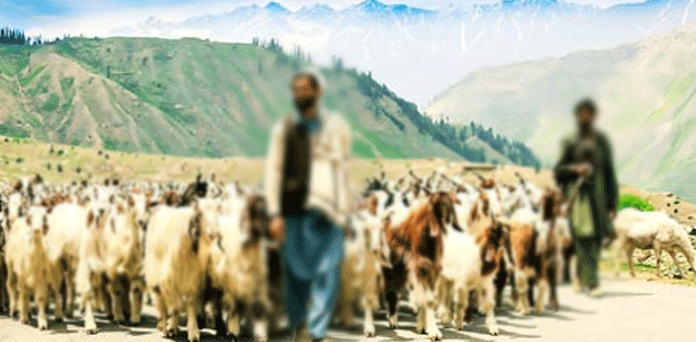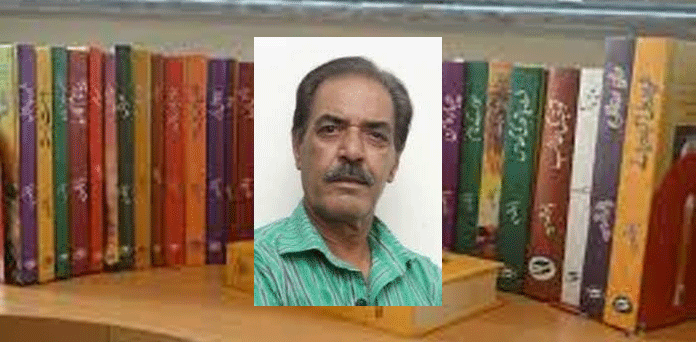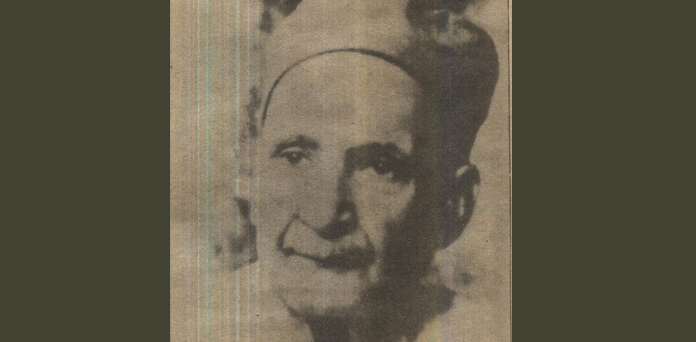مائیکل انجلو کو دنیا اطالوی مصور اور مجسمہ ساز کے طور پر پہچانتی ہے جس کے فن پارے بڑی بڑی آرٹ گیلریوں کی زینت ہیں۔ مائیکل انجلو کے فن اور شخصیت پر کئی کتابیں لکھی جاچکی ہیں اور ناقدین نے اس کے فن کو اپنا موضوع بنایا ہے۔
پروفیسر احمد عقیل روبی کو ہم بحیثیت قلم کار جہاں متعدد حیثیتوں میں جانتے ہیں، وہیں وہ ایک ایسے سوانح نگار اور مضمون نویس بھی تھے جس نے مشاہیرِ عالم پر کئی معلومات افزا مضامین رقم کیے اور ان کے حالاتِ زندگی ترجمہ کرتے ہوئے نہایت اسے اپنے دل چسپ اور پُرلطف اسلوب میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ مائیکل اینجلو کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں۔ مؤرخین نے اس کی تاریخِ وفات 18 فروری 1564ء لکھی ہے۔ آج اس مصور اور مجسمہ ساز کے یومِ وفات کی مناسبت سے احمد عقیل روبی کی یہ تحریر ملاحظہ کیجیے۔
پادری دوست نے ایک بار اس سے بڑے افسوس ناک لہجے میں کہا:’’کاش تم نے شادی کی ہوتی، تمہارے بھی دو چار بچے ہوتے۔‘‘
اس نے پوچھا:’’ تو پھر کیا ہوتا؟‘‘
’’کم از کم آنے والی نسلوں تک تمہارا نام تو پہنچتا۔ تمہاری نسل تو پھلتی پھولتی۔‘‘
’’یہ دونوں چیزیں میرے فن میں موجود ہیں جو ہر پل مجھے سرگرمِ عمل رکھتی ہیں۔ میں جو فن چھوڑ کر جاؤں گا، یہی میرے بچّے ہیں۔ اگرچہ یہ فن اس قابل نہیں لیکن میں اسی حوالے سے آنے والی نسلوں میں زندہ رہوں گا۔‘‘
اس نے اپنے فن کے بارے میں کم اندازہ لگایا۔ وہ اپنے اس عظیم فنی ورثے کے حوالے سے آج بھی زندہ ہے اور جب تک فنی باریکیوں کو سمجھنے والے زندہ ہیں وہ زندہ رہے گا۔ صدیوں سے دلوں میں زندہ رہنے والا یہ شخص مائیکل اینجلو ہے جو 1475ء میں کیپرس (Caprese) کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ اس قصبے کا مشیر تھا جسے پوڈیسٹا کہا جاتا تھا۔ مائیکل ابھی سات سال کا ہی تھا کہ اس کی ماں فوت ہوگئی۔ مائیکل اینجلو کو ایک سنگ تراش اور اس کی بیوی کے ساتھ رہنا پڑا جہاں اس کے باپ کی پتھر کی فیکٹری تھی۔ اس کے والد نے 13 سال کی عمر میں اسے پڑھنے کے لئے فلورنس بھیجا مگر اسے پڑھائی لکھائی سے کوئی دل چسپی نہ تھی۔ اس نے تحریر کے مقابلے میں ڈرائنگ، سنگ تراشی اور مجسمہ سازی کو اہمیت دی اور مصوری سے اسے بہتر تصور کیا۔
مائیکل اینجلو کی نظر میں فطرت نے ایک ظلم یہ کیا ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ شاہکار پتھروں میں قید کر دیے ہیں، اس کے نزدیک مجسمہ ساز کا یہ کام ہے کہ وہ انہیں تراش کے پتھروں کی قید سے رہائی دلائے۔ اس کا خیال تھا کہ ہر پتھر میں ایک مجسمہ ہے۔ مجسمہ ساز غیر ضروری پتھر الگ کر کے نقش و نگار نمایاں کرتا ہے۔
سقراط نے برسوں پہلے یہی بات کہی تھی کہ پتھر میں ایک شکل موجود ہوتی ہے۔ مجسمہ ساز اسے پتھر سے باہر نکالتا ہے۔ مائیکل اینجلو نے اسی بات کی تائید کی ہے۔ اردو کا ایک نامعلوم شاعر اس بات کو اپنے شعر میں کچھ یوں لکھتا ہے:
جب کسی سنگ سے ٹھوکر کھائی
نا تراشیدہ ضنم یاد آئے
( احمد عقیل روبی کی کتاب ’’علم و دانش کے معمار‘‘ سے اقتباس)