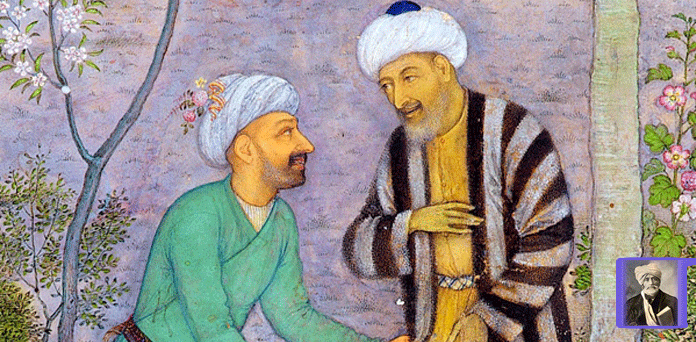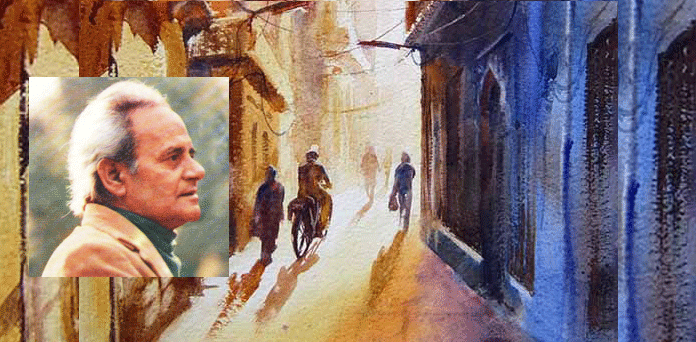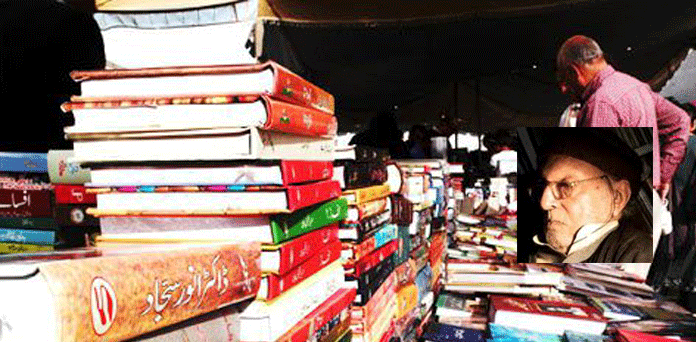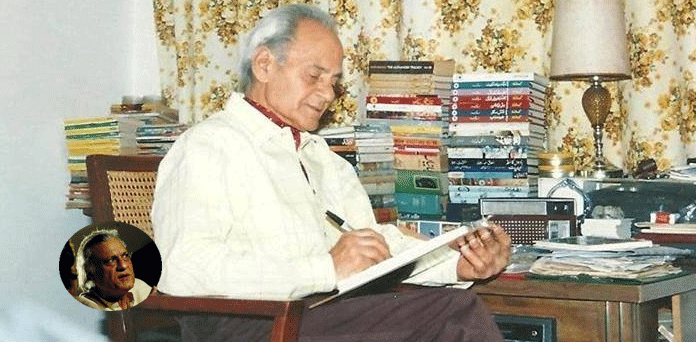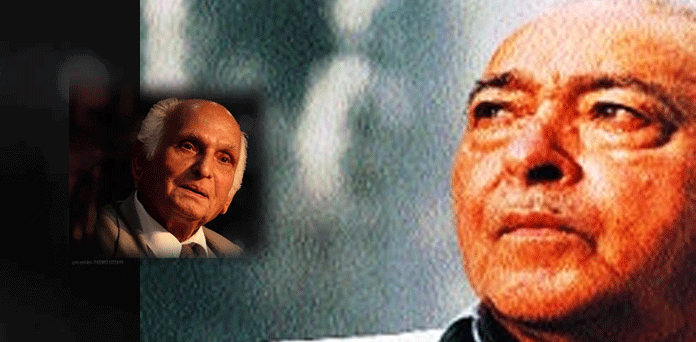ترقی یافتہ قوموں کے بڑے بڑے ادیبوں اور فلاسفروں کے سفرنامے اور سوانح عمریاں ہی ایسی بیش بہا چیزیں سمجھی جاتی ہیں کہ جن کی روشنی گذشتہ اور آئندہ منزلوں پر پر چومک کا کام دیتی ہے اور جو آنے والی نسلوں کے سدھارنے کے لیے بہت کچھ مدد دیتی ہے۔
اپنے بزرگوں کے وطن کی سیر کا کانٹا جس ذوق و شوق سے مولانا کے پہلو میں کھٹکتا تھا اکثر تحریروں میں لہو ہو ہو کر ٹپکا ہے مگر وقت کی مجبوری اور واقعات کی مصلحت ہندوستان کا دامن نہ چھوڑنے دیتی تھی۔ اگرچہ علمی و ادبی تحقیقات کے غنچے چٹکیاں لیے جاتے تھے۔ آخر وہ مبارک گھڑی آہی گئی اور مولانا نے بصد اشتیاق و آرزو ایران کے سفر کے لیے کمر کَسی۔ علمِِ تاریخ کے متوالے جانتے ہیں کہ جس طرح آج ہر ایک علم و فن ایجاد و اختراع کا منبع ولایتِ انگلینڈ ہے، اِسی طرح ایک زمانہ میں ایران سمجھا جاتا تھا۔ خاص کر ہمارے مشرقی علوم تو اِسی رستے بہہ کر ہم تک پہونچے تھے۔ ایسی حالت میں ہر علم دوست طبیعت کی یہی آرزو ہوتی تھی کہ ایک دفعہ ضرور ان آنکھوں کو ولایتِ ایران کی زیارت سے روشن کرے۔ سیاحتِ ایران کے بعد مولانا نے ہندوستان واپس آ کر سخندانِ فارس کو ترتیب دیا۔
ہمارے بعد کے اردو بولنے والے کیا جانیں گے کہ آزاد نے کس طرح کا سفر کیا تھا اور اس میں ہمارے لیے کیا کچھ کیا تھا۔ میں نے ہر چند تلاش کیا مگر ان کے سفر کا کوئی روزنامچہ یا سفر نامہ ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا نہ ملا۔ فقط ایک پھٹا پرانا رفیق ہند اخبار کا پرچہ ہاتھ آیا ہے جس میں ایک لیکچر سفر ایران کے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ چند چھوٹے چھوٹے کاغذوں کا ایک گٹھا سا ملا جس میں نوٹ لکھے ہیں جن کا پڑھنا دشوار اور ترتیب دینا ناممکن تھا پھر بھی جس قدر ممکن ہوسکا موزوں کر کے روزنامچہ کے نام سے چھپوا دیا ہے۔
اس طول و طویل سفر سے مولانا جولائی ١٨٨٦ء میں واپس تشریف لائے تھے۔
یہ سطور طاہرؔ نبیرہ آزاد نے اس کتابچہ کے ابتدائیہ کے لیے لکھی تھیں جو انشا پرداز، ادیب شاعر اور صحافی مولانا محمد حسین آزاد کے ایران کی سیر کا کچھ کچھ احوال سناتا ہے۔ آگے سیرِ ایران کے دوران شیراز جیسے نامی گرامی اور مشہور شہر میں آزاد کے قیام اور ملاقاتوں کا حال آزاد کے قلم سے کچھ یوں ہے۔ ملاحظہ کیجیے:
شیراز کو دیکھنے کا ارمان تھا۔ ایک عمر کے بعد خدا نے پورا کیا۔ اللہ اللہ! خواجہ حافظ اور شیخ سعدی کا پیارا وطن جس پر وہ لوگ تعریفوں اور دعاؤں کے پھول چڑھائیں۔ اس کو دیکھنے کا ارمان کیوں نہ ہو، میں نے دیکھا اور تعجب کے ساتھ دیکھا، کیونکہ جس شیراز پر نورانی بزرگوں نے نور برسائے تھے اُس کی رونق و آبادی ان کے ساتھ ہی رحلت کر گئی۔ اب بڑی بڑی وسیع اور بلند پرانی مسجدیں اور کہنہ مدرسے گرے پڑے کھڑے ہیں اور بنانے والوں کی ہمتوں پر دلائل پیش کر رہے ہیں۔ اُن میں نوجوان لڑکے صرف، نحو، بلاغت، فقہ، اصول کی کتابیں سامنے رکھے بے مدد کتاب کے مسائلِ کتابی پر بحث کرتے ہیں۔ علما کتب علمیہ کی تدریس سے پرانی ہڈیوں پر آبِ حیات چھڑکتے ہیں۔ یہ بات جاننے کے قابل ہے کہ وہاں ہندوستان کی طرح طلباء فقرہ بہ فقرہ نہیں پڑھتے۔ استاد کتاب سامنے رکھے بیٹھا ہے، طلبا اپنی کتاب کھولے خاموش بیٹھے ہیں۔ استاد کتاب کو دیکھتا ہے اور اُس کے مطالب کو نہایت توضیح اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جاتا ہے۔ طلبا سنتے جاتے ہیں۔ جتنی جس کے دامن میں وسعت ہو پھل پھول بھر لے۔
غرض شہر شیراز کا اب یہ حال ہے کہ وہ عالی شان اور سیدھا بازار اور بلند اور فراخ مسجد جو کریم خان ژند نے سو برس پہلے بنائی ہے۔ اگر وہاں سے اٹھا لیں تو اصل شیراز ایک معمولی قصبہ رہ جاتا ہے۔ چند سال ہوئے مشیر الملک نے بھی رفیع الشان مسجد اور کارواں سرائے سے پرانے شہر کو نیا کیا ہے۔
نواب مرزا علی خان صدر ایک امیر خاندانی کی زندگانی شیراز کے لیے سرمایۂ آبا دانی ہے اور اُن کی مہمان نوازی اُس پاک مٹی کے لیے قدیمی قبالہ ہے۔ مجھے بھی دو دن مہمان رکھا۔ باوجود دستگاہِ امارت اور پیرانہ سالی کے، جب دیکھو گرد کتابیں چُنی ہیں۔ ایک دو مُلّا پاس بیٹھے ہیں۔ بیچ میں آپ مطالعہ میں مصروف ہیں۔ تصحیح کرتے ہیں۔ حواشی لکھتے ہیں۔ ایک خوشنویس کاتب ناقص کتابوں کی تکمیل کررہا ہے۔ مُصور نقَّاشی کررہا ہے۔ کھانے کا وقت ہوا، وہیں پہلو میں دسترخوان بچھا۔ اٹھے پہلے سجدہ شکرانہ بجا لائے۔ ایک روٹی کو اٹھا کر آنکوں سے لگایا۔ پھر سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ یہ بھی گویا ایک فرض تھا کہ ادا کیا۔ پھر کتابوں کے حلقے میں جا بیٹھے۔
اِن کے والد مرحوم کی تصنیفات سے بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں۔ بعض ان میں سے میں نے بازار سے خریدیں۔ ان میں سے اِس رسالہ کا پیش کرنا واجب ہے جو کہ انہوں نے حرکتِ زمین کے اثبات میں لکھا تھا۔ نواب ممدوح نے خود اس کی نقل مجھے عنایت فرمائی ہے۔ آج سے چالیس برس پہلے ایشیائی تعلیم میں ایسے خیالات کا پیدا کرنا خاکِ پارس کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔
اسی سلسلے میں حکیمِ حاذق حاجی مرزا حسن کا ذکر بھی واجب ہے۔ انہوں نے ایک مفصل تاریخ شیراز کی لکھ کر پارس نامہ نام رکھا ہے اور ان کا علو خاندان مجھے کتابوں سے حد ثبوت کو پہنچا معلوم ہوا۔ ساتویں پشت میں خواجہ شاہ منصور اور چوتھی پشت میں سید علی خان بلاغت کی اولاد ہیں۔ سید علی خان کی تصنیفات شہرۂ آفاق ہیں۔ ان کی تفصیل اپنے سفرنامے کے لیے امانت رکھتا ہوں۔
حکیم صاحب خبر سن کر نواب صدر کے ہاں آئے۔ باوجودیکہ میری روانگی میں ایک شب باقی تھی۔ شام ہو گئی تھی۔ بوندیں پڑ رہی تھیں۔ بااصرار اجازت لے کر اپنے گھر لے گئے۔ رات بھر اپنی کتاب سناتے رہے۔ مطالب پر مشورہ کرتے رہے۔ میری کتاب یاداشت نے بھی اُس کے اکثر مطالب سے سرمایہ حاصل کیا۔
یہ اہلِ ایران میں عام دستور ہے کہ اشراف سفید پوش کے مکان کے ساتھ ایک مردانہ مکان ہوتا ہے۔ وہ حرم سرائے سے زیادہ آراستہ ہوتا ہے اور ضروریات کے سامان موجود ہوتے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے کہ موافق طبع دوست صبح ملاقات کو آیا۔ ظہر کی نماز پڑھ کر رخصت ہوا۔ یا رات کو رہا، صبح ناشتا کر کے رخصت ہوا۔
شیراز کے لوگ اب تک لباس و اوضاع میں اپنے بزرگوں کی تصویر ہیں۔ علما اور ثقہ لوگ عمامہ باندھتے ہیں۔ عبا پہنتے ہیں۔ خاندانی ترک کلاہ پوست برہ کی پہنتے ہیں۔ طہران کے اوضاع جدید ابھی تک وہاں لذیذ نہیں ہوئے ۔
شیراز میں چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بکتی دیکھیں کہ ان سے لوگ سر اور داڑھیاں دھوتے تھے۔ وہ ایک قسم کی مٹی ہے جس کی کان شہر کے پاس ہے۔ اس میں خوشبو کے اٹھانے کی قدرتی تاثیر ہے۔ اُسے پھولوں میں بسا کر صاف کرتے ہیں اور ٹکیاں بنا کر بیچتے ہیں۔ شہروں میں تحفہ لے جاتے ہیں گِلِ گُل اس کا نام ہے۔ مجھے گلستان کا سبق یاد آیا۔ ع
گلِ خوشبوئے در حمام روزے
جن دنوں ہم نے پڑھا تھا تو خدا جانے کیا سمجھے تھے۔ پھر ایک خیال شاعرانہ سمجھتے رہے۔ اب معلوم ہوا کہ شیراز کا اصلی تحفہ ہے۔
جاڑے کا موسم کوہ برف لیے سر پر چلا آتا تھا۔ بڑھاپے نے خوف کے لحاف میں دبک کر کہا کہ شیراز تو دیکھ لیا۔ اب اصفہان کو دیکھو اور آگے بڑھو کہ تلاش کی منزل ابھی دور ہے۔ شیراز کے دوست بہت روکتے اور رستہ کے جاڑے سے ڈراتے رہے، مگر جب کارواں چلا۔ مجھے اشتیاق نے اٹھا کر کجاوہ میں بٹھا دیا۔ چار چار پانچ پانچ کوس پر شاہ عباسی سرائیں آباد موجود تھیں۔ جن کی پختگی اور وسعت قلعوں کو ٹکر مارتی تھی۔ ان سراؤں میں مسافر اگر روپیہ رکھتا ہو تو خاطر خواہ سامان آسائش کا ملتا ہے، چار پانچ آنہ کو مرغ اور پیسے کے دو دو انڈے، ہر قسم کے تر و خشک میوے نہایت اعلٰی اور نہایت ارزاں ملتے ہیں۔
رستہ آبِ رواں سے سبز اور آبادیوں سے معمور تھا۔ جہاں منزل کرتا، گاؤں میں جا کر پوچھتا اور جو اہل علم ہوتا اس سے ملاقات کرتا۔ چھوٹی سے چھوٹی آبادی میں بھی ایک دو عالم اور بعضے صاحب اجتہاد ہوتے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر تعجب آتا تھا۔ مثلاً کھیت سے گائے کے لیے گھاس کندھے پر لیے آتے ہیں۔ یا نہر پر کپڑے دھو رہے ہیں۔ لڑکا گھر کی دیوار چُن رہا ہے۔ جب فارغ ہوئے تو اسے شرع لمعہ یا قوانین الاصول کا سبق پڑھانے لگے۔ جب اُن سے پوچھتا کہ کسی شہر میں جا کر ترویج علم کیوں نہیں کرتے؟ کہ رواجِ کار بھی ہو۔ تو کہتے کہ وہاں خلوت کا لطف نہیں رہتا، حضورِ قلب میں خلل آتا ہے۔ دنیا چند روز ہے۔ گزار دیں گے اور گزر جائیں گے۔ یہ علمی روشنی کل مملکتِ ایران میں عام ہے کہ شاہانِ سلف کی پھیلائی ہوئی ہے۔
میں اُن سے کہتا تھا کہ ہماری تمہاری تو جس طرح گزر ی گزر گئی۔ لڑکوں کو طہران بھیجو اور دار الفنون پڑھواؤ کہ زمانہ کی ہوا پھر گئی ہے۔ اکثر ہنس دیتے اور میرے ساتھ ہم داستان ہو کر کہتے۔ انہی کو کہو کہ ان کا معاملہ ہے۔ بعضے بحثنے لگتے اور آخر اتفاقِ رائے کرتے۔
میرے پاس کھانے پکانے کا سامان نہ تھا۔ وہیں بیٹھ کر کسی گھر سے روٹی مول لیتا۔ کہیں سے انڈے کہیں سے گھی۔ اشکنہ یعنی انڈوں کا قلیہ پکاتا۔ اس میں روٹی ڈبوتا، کھاتا اور شکر الہیٰ بجا لاتا۔ اس میں بہت باتوں اور تحقیقاتوں کے موقع ملتے تھے اور وہ لوگ ان کاموں میں میری مدد کرنی مہمان نوازی کا جزو سمجھتے تھے جو کہ حقیقت میں فرض مذہبی ہے۔
غرض بارہ دن کے بعد اصفہان میں جا اترا۔