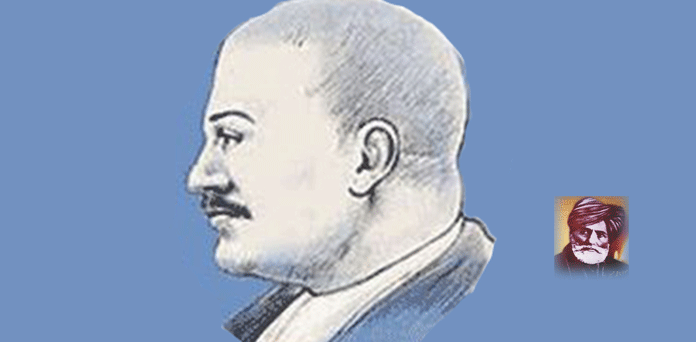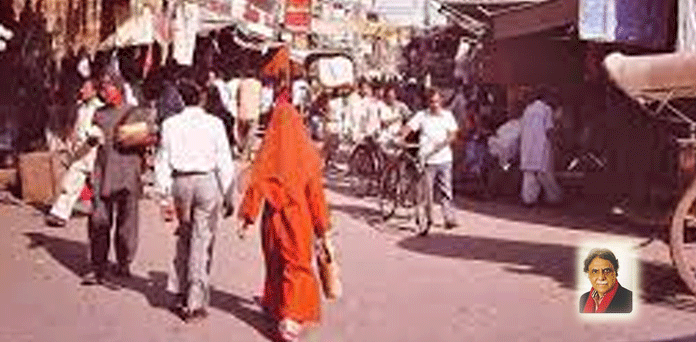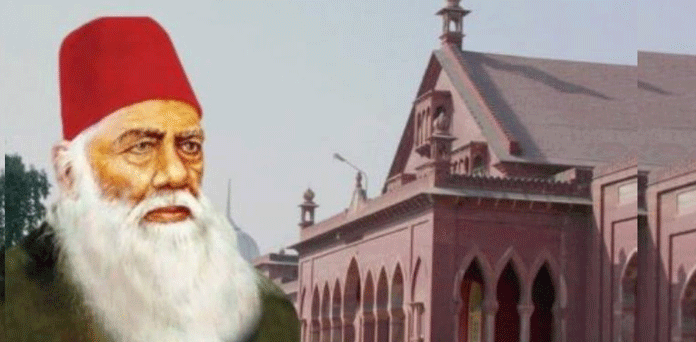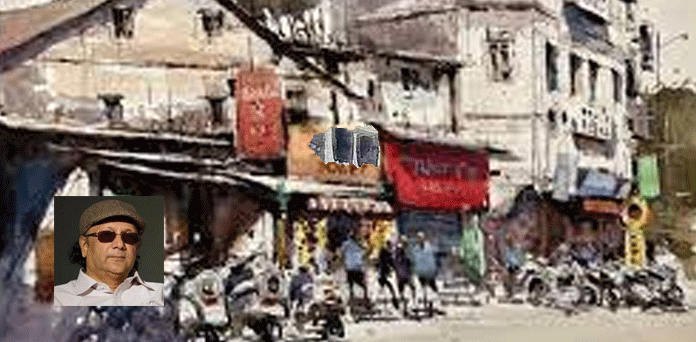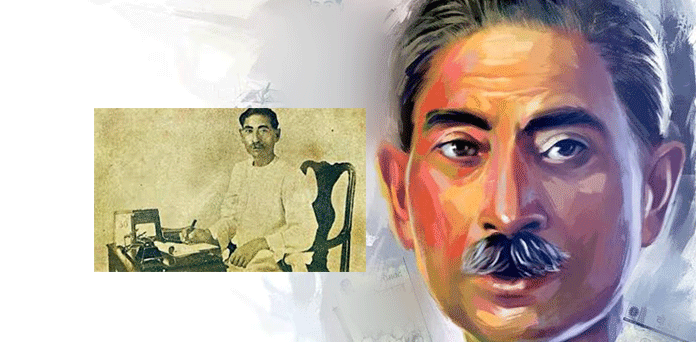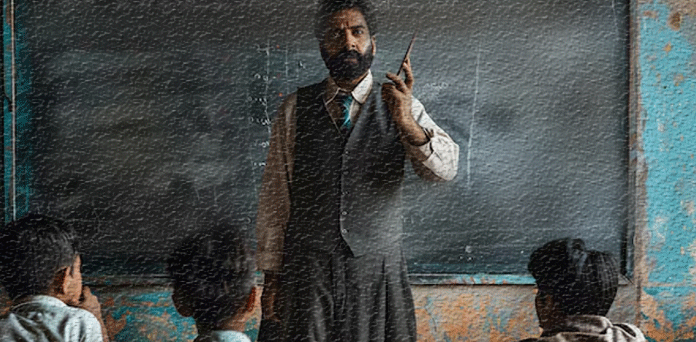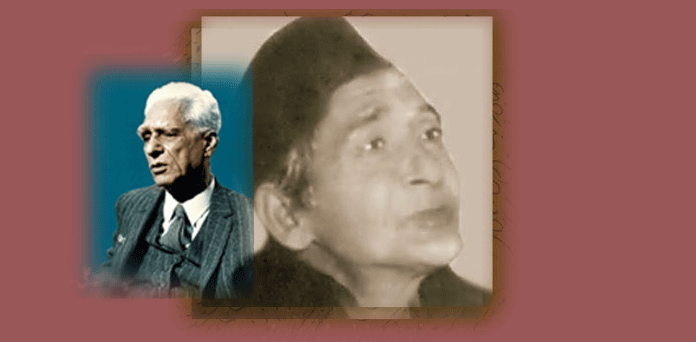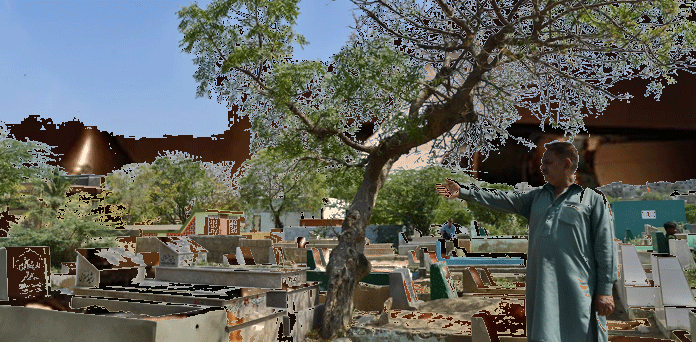اس رات اتفاق سے میں نے شیطان کو خواب میں دیکھ لیا۔ خواہ مخواہ خواب نظر آگیا۔ رات کو اچھا بھلا سویا تھا، نہ شیطان کے متعلق کچھ سوچا نہ کوئی ذکر ہوا۔ نجانے کیوں ساری رات شیطان سے باتیں ہوتی رہیں اور شیطان نے خود اپنا تعارف نہیں کرایا کہ خاکسار کو شیطان کہتے ہیں۔
یہ فقط ذہنی تصویر تھی جس سے شبہ ہوا کہ یہ شیطان ہے۔ چھوٹے چھوٹے نوک دار کان، ذرا ذرا سے سینگ، دبلا پتلا بانس جیسا لمبا قد۔ ایک لمبی دم جس کی نوک تیر کی طرح تیز تھی۔ دُم کا سرا شیطان کے ہاتھ میں تھا۔ میں ڈرتا ہی رہا کہ کہیں یہ چبھو نہ دے۔ نرالی بات یہ تھی کہ شیطان نے عینک لگا رکھی تھی۔ رات بھر ہم دونوں نہ جانے کس کس موضوع پر بحث کرتے رہے۔
اس صبح چائے کی میز پر بیٹھتے ہیں تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ روفی کی شکل بالکل شیطان سے ملتی تھی۔ شکل کیا حرکتیں بھی وہیں تھیں۔ ویسا ہی قد، وہی چھوٹا سا چہرہ، لمبی گردن، ویسی ہی عینک، وہی مکار سی مسکراہٹ۔ مجھ سے نہ رہا گیا۔ چپکے سے رضیہ کے کان میں کہہ دیا کہ روفی شیطان سے ملتے ہیں۔ وہ بولی۔ آپ کو کیا پتہ؟ کہا کہ ابھی ابھی تو میں نے اصلی شیطان کو خواب میں دیکھا ہے۔ حکومت آپا رضیہ کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے جو ہمیں سرگوشی کرتے دیکھا تو بس بے قابو ہوگئیں۔ فوراً پوچھا۔۔۔ کیا ہے۔۔۔؟ رضیہ نے بتا دیا۔
حکومت آپا کو تو ایسا موقع خدا دے۔ بس میز کے گرد جو بیٹھا تھا اسے معلوم ہوگیا کہ روفی کا نیا نام رکھا جا رہا ہے۔ لیکن محض خواب دیکھنے پر تو نام نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ ویسے روفی نے ہمیں تنگ بہت کر رکھا تھا۔ بچوں تک کی خواہش تھی کہ ان کا نام رکھا جائے۔
ہم چائے ختم کرنے والے تھے۔ مجھے دوسرے آملیٹ کا انتظار تھا اور رضیہ کو پتہ نہیں کس چیز کا۔۔۔ کالج میں ابھی آدھ گھنٹہ باقی تھا، اس لیے مزے مزے سے ناشتہ کر رہے تھے۔ اتنے میں ننھا حامد بھاگا بھاگا آیا۔ اس کے اسکول کا وقت ہوگیا تھا اس لیے جلدی میں تھا۔ وہ روفی کے برابر بیٹھ گیا۔ حامد کو بخار ہو گیا تھا۔ تبھی اس کی حجامت ذرا باریک کروائی گئی تھی۔ روفی نے بڑی للچائی ہوئی نگاہوں سے حامد کے سر کو دیکھا۔ جونہی حامد نے ٹوسٹ کھانا شروع کیا روفی نے ایک ہلکا سا تھپڑ حامد کے سر پر جما دیا، اور میں نے فوراً رضیہ سے کہہ دیا کہ سچ مچ روفی شیطان ہی ہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی ننگے سر کھائے تو شیطان دھول مارتا ہے۔ حکومت آپا چونک کر ہماری جانب متوجہ ہوئیں۔ ان کو پتہ چلنا تھا کہ سارے کنبے کو معلوم ہوگیا کہ آج سے روفی شیطان کہلائے جائیں گے۔
یہ تھا وہ واقعہ جس کے بعد روفی شیطان مشہور ہوگئے۔ چند ہی دنوں میں ہر ایک کی زبان پر یہ نام چڑھ گیا۔ یہاں تک کہ خود روفی نے اس نام کو بہت پسند کیا۔ روفی اور میں بچپن کے دوست تھے اور مجھے ان کی سب کہانیاں یاد تھیں۔ جب ہم بالکل چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک دن روفی کو ان کی نانی جان تاریخ پڑھا رہی تھیں۔ جب پتھر اور دھات کے زمانے کا ذکر آیا تو روفی پوچھنے لگے، ’’نانی جان آپ پتھر کے زمانے میں کتنی بڑی تھیں؟‘‘ پھر کہیں سقراط اور بقراط کا ذکر ہوا۔ یہ بولے، ’’نانی جان سقراط اور بقراط کیسے تھے؟‘‘
’’کیا مطلب؟‘‘ انہوں نے پوچھا۔
’’آپ نے تو دیکھے ہوں گے۔‘‘ جواب ملا۔ ہر وقت روفی کو کچھ نہ کچھ سوجھتی رہتی تھی۔
لیکن جب ہماری جماعت میں انسپکٹر صاحب معائنہ کرنے آئے تو وہ روفی سے بہت خوش ہوئے اور انعام دے کر گئے۔ انہوں نے پوچھا، ’’اگر پانی کو ٹھنڈا کیا جائے تو کیا بن جائے گا؟‘‘ ہم نے سوچا کہ روفی کہہ دیں گے کہ برف بن جائے گا۔
روفی نے پوچھا، ’’کتنا ٹھنڈا کیا جائے؟‘‘
وہ بولے، ’’بہت ٹھنڈا کیا جائے۔‘‘
روفی سوچ کر بولے، ’’تو وہ بہت ٹھنڈا ہو جائے گا۔‘‘ (بہت پر زور دے کر)
’’اگر اور بھی ٹھنڈا کیا جائے؟‘‘
’’تو پھر وہ اور بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔‘‘ روفی بولے۔
’’اور اگر اسے بے حد ٹھنڈا کیا جائے؟‘‘
’’تو وہ بے حد ٹھنڈا ہو جائے گا۔‘‘ انسپکٹر صاحب مسکرانے لگے اور پوچھا، ’’اچھا اگر پانی کو گرم کیا جائے تب؟‘‘
’’تب وہ گرم ہو جائے گا۔‘‘
’’نہیں، اگر ہم اسے بہت گرم کریں اور دیر تک گرم کرتے رہیں پھر؟‘‘
روفی کچھ دیر سوچتے رہے، یکایک اچھل کر بولے، ’’پھر۔۔۔ چائے بن جائے گی۔‘‘ اور انسپکٹر صاحب نے ایک عظیم الشان قہقہہ لگایا۔ ماسٹر صاحبان نے کوشش کی کہ انہیں کہیں ادھر ادھر لے جائیں، لیکن وہ وہیں کھڑے رہے اور روفی سے بولے، ’’بلّی کی کتنی ٹانگیں ہوتیں ہیں؟‘‘
’’تقریباً چار!‘‘
’’اور آنکھیں؟‘‘
’’کم از کم دو۔۔۔!‘‘
’’اور دُمیں؟‘‘
’’زیادہ سے زیادہ ایک!‘‘
’’اور کان؟‘‘ انہوں نے پوچھا۔
’’تو کیا سچ مچ آپ نے اب تک بلّی نہیں دیکھی؟‘‘ روفی منہ بنا کر بولے اور انسپکٹر صاحب ہنستے ہنستے بے حال ہوگئے۔ ان دنوں سے میں اور روفی دوست تھے۔
(پاکستان کے معروف طنز و مزاح نگار اور افسانہ نویس شفیق الرحمان کے ایک مضمون سے اقتباسات)