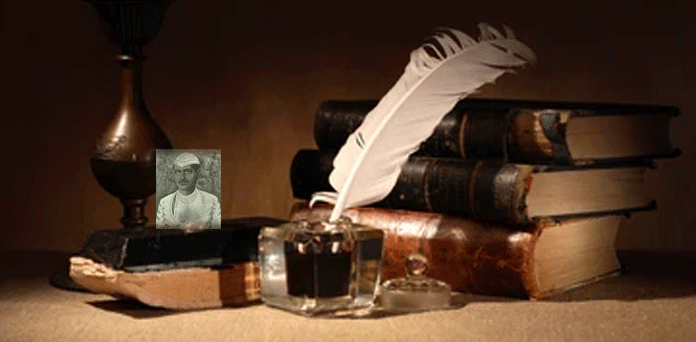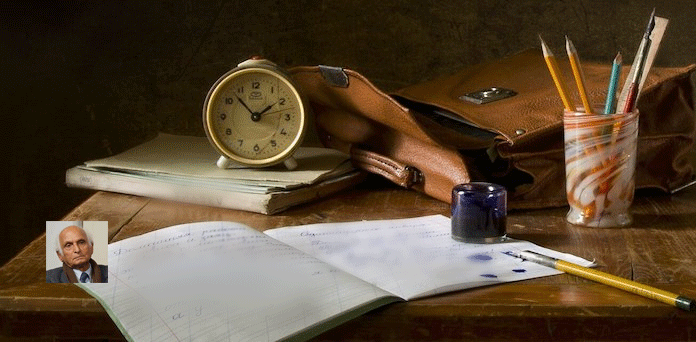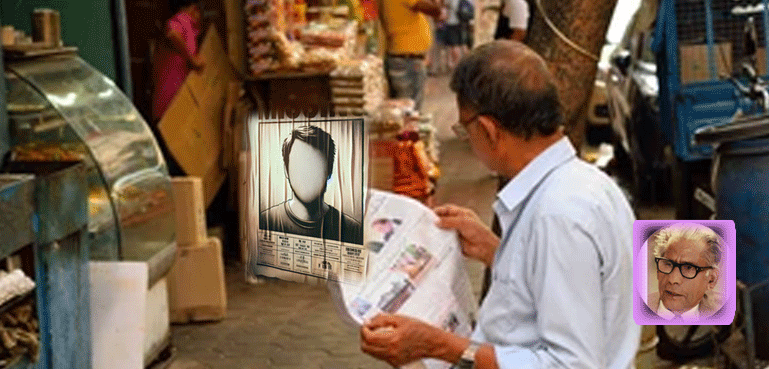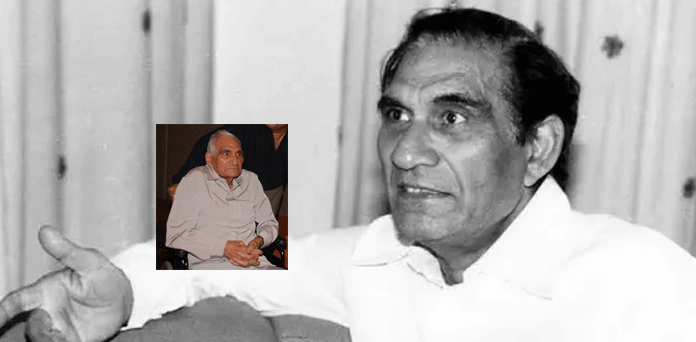یہ اشتہار میں اپنے گم شدہ بھائی چنتا منی کے متعلق دے رہا ہوں۔ موصوف ایک مرتبہ پہلے بھی گم ہوگئے تھے، لیکن اس وقت میں نے اشتہار نہیں دیا تھا۔
کیونکہ میرا خیال تھا کہ موصوف خود دار آدمی ہے، اس لیے اس نے ضرور کنوئیں میں چھلانگ لگا دی ہوگی۔ لیکن چھٹے دن وہ میلی چکٹ پتلون کے ساتھ گھر لوٹ آیا اور بقول ہمارے چچا کے ’’آخر تو ہمارا ہی خون تھا، کیوں نہ لوٹتا، خون نے جوش مارا ہوگا۔‘‘
ہمیشہ اجلی پتلون پہننے والا کب تک گھر سے باہر رہ سکتا تھا۔ خودی چاہے کتنی ہی بلند ہو جائے پتلون کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔ مگر اس بار مجھے یقین ہے کہ موصوف لوٹ کر نہیں آئے گا۔ کیونکہ وہ گھر سے دو سو روپے اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس لیے اب اس کی رگوں میں ہمارا خون جوش نہیں مارے گا۔ اشتہار دینے کی ایک اور وجہ والدہ محترمہ ہیں، جو موصوف کو ابھی تک ’’نادان لڑکا‘‘ گردان رہی ہیں۔ میں نے لاکھ کہا کہ مادر مہربان! چنتا منی اب بیس برس کا ہوچکا ہے نادان نہیں رہا۔ وہ چہرے مہرے سے ہی گدھا دکھائی دیتا ہے مگر اندر سے کافی کائیاں ہوچکا ہے۔ مگر والدہ محترمہ جس نے اس گدھے کو جنم دیا، اپنی تخلیق پر زیادہ مستند رائے رکھتی ہیں، اس نے مجھے طعنہ دیا، ’’دراصل تم چھوٹے بھائی کی غیرحاضری میں ساری آبائی جائیداد کو تنہا ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔‘‘
ہماری آبائی جائیداد دو کمروں والا ایک مکان ہے جو ہم نے کرائے پر لے رکھا ہے یا پھر والد محترم کے قبضہ میں ایک بہی کھاتا ہے جس میں درج ہے کہ ہمارے خاندان کے پاس ڈیڑھ سو ایکڑ زمین ہے جس پر آج کل ایک دریا بہہ رہا ہے۔ والد محترم گزشتہ گیارہ برس سے اس دریا کے سوکھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔
اگرچہ والدہ محترمہ کے طعنہ کی بنیادیں دریا برد ہوچکی ہیں لیکن پھر بھی ایک فرماں بردار فرزند کے طور پر میں یہ اشتہار دینے پر مجبور ہوا ہوں۔
برادر عزیز چنتا منی کی تصویر مجھے نہیں مل سکی ورنہ اس اشتہار کے ساتھ ضرور چھپواتا۔ دراصل اس کے جتنے فوٹو تھے وہ اس نے اپنی وقتاً فوقتاً قسم کی محبوباؤں میں بانٹ دیے تھے۔ پوچھنے پر چنتا منی کی ہر محبوبہ نے جواب دیا کہ اس کے پاس چنتا منی کی فوٹو تھی، وہ اس نے رسوائی کے خوف سے ضائع کر دی ہے۔ ایک محبوبہ تو اتنی صاف گو نکلی کہ اس نے تنک کر جواب دیا، ’’میں نے شادی ہوتے ہی چنتا منی کی وہ فوٹو لوٹا دی تھی اور آج کل بٹوے میں اپنے خاوند کا فوٹو رکھتی ہوں۔‘‘
چنانچہ فوٹو دستیاب نہ ہونے کے باعث مجبوراً میں اپنا ہی فوٹو اس اشتہار کے ساتھ شائع کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود گم شدہ میرے بھائی کو سمجھا جائے، مجھے نہیں۔
والد اور والدہ محترمہ دونوں کی متفقہ رائے ہے کہ چنتا منی کی ناک تم سے ملتی ہے، اس لیے پہچاننے میں آسانی رہے گی۔ ہمارے نانا مرحوم کی ناک بھی تم دونوں نواسوں سے ملتی تھی اور وہ بھی گھر سے بھاگ گئے تھے (عجیب ناک ہے، نانا کے وقت سے کٹ رہی ہے) بہرکیف فوٹو میں میری ناک حاضر ہے۔ ناک کے علاوہ میرے جتنے اعضا ہیں وہ میرے ذاتی ہیں۔ برادر عزیز چنتا منی کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔
برادر موصوف چنتا منی کے باقی ناک نقشہ کے متعلق پوزیشن یہ ہے کہ اس کا رنگ بچپن میں دودھ کی طرح گورا تھا (ان دنوں وہ صرف ماں کا دودھ پیا کرتا تھا) لڑکپن میں وہ دودھیا رنگ گندمی ہوتا گیا، کیونکہ اس نے گندم کھانا شروع کردی تھی۔ جوان ہوتے ہی رنگ کا میلان سیاہی کی طرف ہوگیا، نہ جانے جوانی میں چوری چھپے اس نے کیا کھانا شروع کردیا تھا۔ البتہ جب والد محترم اسے ہیبت ناک قسم کی گالیاں اور بھبکیاں دیا کرتے تو لمحہ بھر کے لیے اس کا رنگ پیلا بھی پڑ جاتا تھا۔ گویا چنتا منی بڑا رنگا رنگ آدمی تھا (خدا اسے ہر رنگ میں خوش رکھے۔)
آنکھیں بڑی بڑی مگر گونگی قسم کی، جیسے کوئی حسینہ بغیر بیاہ کے بیوہ ہو گئی ہو۔ کئی بار میں نے اسے مشورہ دیا، ’’ارے پگلے! ان پر کالا چشمہ لگالے، بات بن جائے گی۔‘‘ مگر وہ نہیں مانا۔ ایک بار میں نے اپنی بیوی کی آنکھ بچا کر اپنا چشمہ اسے دے بھی دیا مگر وہ اس نے ایک دوست کو دے دیا۔ دوست نوازی میں تو وہ بے مثال تھا۔
والد محترم اسے دوست نوازی پر ہمیشہ چھڑی سے پیٹا کرتے تھے اور اس پٹائی کو وہ کمال صبر و شکر سے سہ لیتا تھا۔ صبر و شکر میں بھی بے مثال تھا۔ والد محترم نہایت فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی شریف اور صابر لڑکا پیدا کیا ہے اور وہ چنتا منی ہے۔ بزرگوں کے سامنے چوں تک نہیں کرتا۔ آہ اس کے بھاگنے کے بعد اب ان بزرگوار کی چھڑی کسی کام نہیں آرہی۔
چنتا منی کی پیشانی پر ایک داغ ہے۔ ایک بار وہ چھت پر کھڑا ایک لڑکی کو گھور رہا تھا۔ لڑکی مذکورہ نے جواباً ایک اینٹ دے ماری۔ اگرچہ چنتا منی نے اس خشت محبت کا ذکر کسی سے نہیں کیا مگر بعد میں اس ناشائستہ لڑکی نے اپنی سہیلیوں سے ذکر کردیا تو بات پھیل گئی اور اس ڈاکٹر تک بھی جاپہنچی جس نے علاج کا بل ایک دم یہ کہہ کر بڑھا دیا کہ اینٹ کا زخم زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔
چنتا منی کے جسم کے باقی حصے صحیح سلامت ہیں۔ وہ ایک مضبوط الجثہ نوجوان ہے۔ غلہ کی بوری اٹھا کر تین میل تک چل سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ اس وقت بھی کسی غلہ منڈی میں بوریاں اٹھانے کا کام کر رہا ہو اور منڈی کے بیوپاری اسے نہایت قلیل اجرت دے رہے ہوں۔ کیونکہ چنتا منی کو بھاؤ تاؤ کرنا نہیں آتا۔ اسے کچھ بھی نہیں آتا۔ سوائے خاموش رہنے کے۔ سوائے ستم سہنے کے۔ مگر میں بیوپاریوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ اس ستم پسندی کا زیادہ استحصال نہ کریں، ورنہ وہ ان کے ہاں سے بھی بھاگ جائے گا۔ کیونکہ بھاگنے کے لیے اس کے پاس پاؤں موجود ہیں۔ چنتا منی کی زبان کام نہیں کرتی، پاؤں کام کرتے ہیں۔
چنتا منی کیوں بھاگا؟ اس کے متعلق مؤرخین کی آراء میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ والد محترم یعنی ابوالچنتا منی کا خیال ہے کہ لڑکا شادی کا خواہش مند تھا مگر اسے دور دور تک شادی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ مگر عم الچنتا منی یعنی چچا جان اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔۔۔ وہ کہتے ہیں کہ چنتا سرے سے شادی سسٹم کے ہی خلاف تھا اور برہم چریہ میں یقین رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک ذمہ دارانہ سوجھ بوجھ کا مالک تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی دو بہنیں ابھی تک کنواری بیٹھی ہیں۔ یعنی برہم چریہ کے لیے اس کے پاس ٹھوس وجہ موجود تھی۔۔۔ تیسرے مؤرخ ام الچنتا منی یعنی والدہ محترمہ کی رائے چچا جان سے کسی حد تک ملتی ہے، صرف اس ترمیم کے ساتھ کہ بہو (یعنی میری زوجہ) نے ہی اسے یہاں سے فرار ہونے میں مدد دی ہے۔
خود بہو بھی اس قسم کی ایک الگ رائے رکھتی ہے۔ یعنی جو ساس کہے اس کے الٹ۔
قارئین! مجھے انتہائی افسوس ہے کہ چنتا منی کی خاطر مجھے اپنے کنبہ کی اندرونی حالت ظاہر کرنا پڑی اور باعزت کنبے کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لیکن پورا پس منظر دیے بغیر چنتا منی کی تلاش ناممکن ہے، بہرکیف مؤرخین کے ان شدید اختلافات کی موجودگی میں وثوق سے کہنا ناممکن ہے کہ چنتامنی کیوں بھاگا؟ بیکاری، بیزاری، کنوارپن، کند ذہنی، پٹائی، ڈیموکریسی، صنعتی ارتقا، برہم چریہ، قربانی، بے وقوفی۔۔۔ ان میں سے کوئی ایک وجہ بھی ہوسکتی ہے یا ساری وجہیں بھی ہوسکتی ہیں۔ شاید چنتا منی ان تمام وجہوں کو اپنے ذہن میں پالتا رہا، پالتا رہا اور اس دن یہ تمام وجہیں منزل مقصود کو پہنچ گئیں جب اچانک دو سو رپے اس کے ہاتھ لگ گئے۔
یہ دو سورپے میرے ایک دوست کی امانت تھے اور اب اس نے مجھ پر مقدمہ کر رکھا ہے۔
عزیز چنتا منی کی تلاش میں ہم نے کوئی کسر نہیں اٹھارکھی۔ ریلوے اسٹیشنوں پر ڈھونڈا، جیل خانے چھانے، جوئے خانوں میں گئے، فلم کمپنیوں سے پوچھا۔ میری ماں درختوں سے پوچھتی پھری۔ والد محترم نے مختلف ریل گاڑیوں پر سفر کیا لیکن چنتا منی جیسے ایک خدا تھا کہ کہیں نہیں ملا۔
(ممتاز اردو ادیب اور معروف مزاح نگار فکر تونسوی کی ایک شگفتہ تحریر)