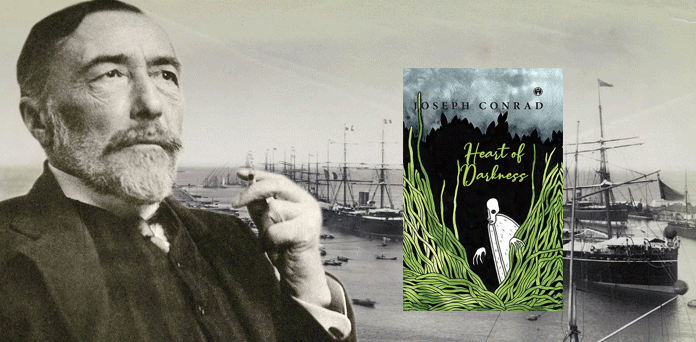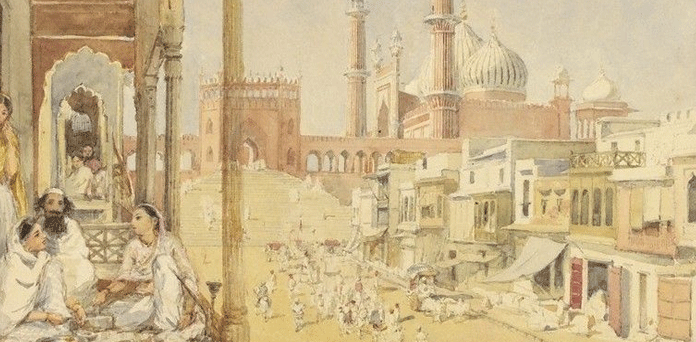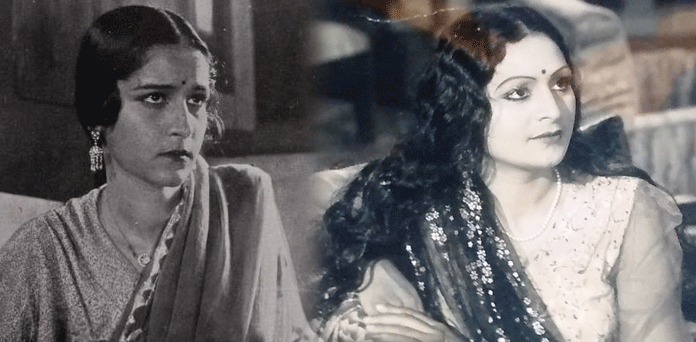اگر کسی اسٹوڈیو میں آپ کو کسی مرد کی بلند آواز سنائی دے، اگر آپ سے کوئی بار بار ہونٹوں پر اپنی زبان پھیرتے ہوئے بڑے اونچے سُروں میں بات کرے، یا کسی محفل میں کوئی اس انداز سے بول رہے ہوں جیسے وہ سانڈے کا تیل بیچ رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ حکیم احمد شجاع صاحب کے فرزندِ نیک اختر مسٹر انور کمال پاشا ہیں۔
انور کمال پاشا کی شخصیت منفرد ہے۔ گو انور پاشا کی آنکھوں کا بھیڑیا پن نہیں تو ان میں ایک ہلکی سی چمک ضرور ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ وہ دوسروں پر چھا جانے کی قوت رکھتے ہیں۔ جسمانی قوّت تو خیر ان میں اسی قدر ہوگی جتنی میرے جسمِ ناتواں میں ہے مگر وہ میری طرح دھونس جما کر اس کمی کو پورا کر ہی لیتے ہیں۔ فلمی دنیا میں دراصل بلند بانگ دعوے ہی بااثر ثابت ہوتے ہیں۔ ایک محاورہ ہے ’’پدرم سلطان بود‘‘ لیکن اس کے برعکس انور کمال پاشا ہمیشہ یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ میرا باپ سلطان نہیں گڈریا تھا، سلطان تو میں ہوں۔
اس میں شعبدہ بازی کے جراثیم موجود ہیں۔ جس طرح مداری اپنے منہ سے فٹ بال کی جسامت کے بڑے بڑے گولے نکالتا ہے اسی طرح وہ بھی کوئی اس قسم کا اسٹنٹ کر سکتا ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہے اور یہ حیرت اس لیے کہ وہ چالاک نہیں، عیار نہیں، دغا باز نہیں لیکن پھر بھی جب لوگ اس کے منہ سے فٹ بال جتنے گولے باہر نکلتے دیکھتے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے اس کی ساحری سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔
ہو سکتا ہے، بعد میں وہ اپنی حماقت پر افسوس کریں کہ یہ تو محض فریبِ نظر تھا، یا گولے نکالنے میں کوئی خاص ترکیب استعمال کی گئی مگر اس سے کیا ہوتا ہے۔ انور کمال پاشا اس دوران میں کوئی اور شعبدہ ایجاد کر لیتا ہے۔ اس وقت اپنا دوسرا فلم بنانے کے لیے سرمایہ داروں سے، بہت ممکن ہے یہ کہہ رہا ہو کہ میں اب کے ایسا فلم بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں جو ہالی ووڈ بھی نہیں بنا سکتا۔ اس میں کوئی ایکٹر ہو گا نہ ایکٹریس۔ صرف کٹھ پتلیاں ہوں گی جو بولیں گی۔ گانا گائیں گی اور ناچیں گی بھی۔ اور کلائمکس اس کا یہ ہوگا کہ وہ گوشت پوست کی بن جائیں گی۔
انور کمال پاشا پڑھا لکھا ہے۔ ایم اے ہے۔ انگریزی ادب سے اسے کافی شغف رہا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ اپنے فلموں کی کہانی اسی سے مستعار لیتا ہے اور حسبِ ضرورت یا حسبِ لیاقت اردو زبان میں ڈھال دیتا ہے۔ اس کے فلموں کے کردار ہمیشہ ڈرامائی انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ خواہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ خود ڈرامائی انداز میں گفتگو کرنے کا عادی ہے۔ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ اس کے والد محترم جناب حکیم احمد شجاع صاحب کسی زمانے میں اچھے خاصے ڈرامہ نگار تھے۔ ان کا لکھا ہوا ڈرامہ’’باپ کا گناہ‘‘ بہت مشہور ہے۔
انور کمال پاشا بہرحال بڑی دل چسپ شخصیت کا مالک ہے۔ وہ اتنا بولتا، اتنا بولتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی نہیں بول سکتا۔ اصل میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ اپنی آواز خود سننا چاہتا ہے اور دل ہی دل میں داد دیتا ہے کہ انور کمال پاشا تُو نے آج کمال کر دیا۔ تیرے مقابلے میں اور کوئی اتنا زبردست مقرر نہیں ہوسکتا۔ اگر آپ نفسیات کے متعلق کچھ جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض انسانوں کو یہ مرض ہوتا ہے کہ وہ ریکارڈ بن جائیں اور اسے گرامو فون کی سوئی تلے رکھ کر ہر وقت سنتے رہیں۔ انور کمال پاشا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔
اس کے پاس اپنی گفتگوؤں کے کئی ریکارڈ ہیں جو اپنی زبان کی سوئی کے نیچے رکھ کر بجانا شروع کر دیتا ہے اور جب سارے ریکارڈ بج چکتے ہیں تو وہ ریڈیو کے فرمائشی پروگرام سننے والے بچوں کے مانند خوش ہو کر محفل سے چلا جاتا ہے۔
اس نے اب تک مندرجہ ذیل فلم بنائے ہیں جن میں سے کچھ کامیاب رہے اور کچھ ناکام۔
’دو آنسو‘، ’دلبر‘، ’غلام‘، ’گھبرو‘، ’گمنام‘۔ اگر آپ نے یہ فلم دیکھے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان میں کتنے فلموں میں دریا آتا ہے جس میں کہانیوں کے کردار گرے ہیں لیکن وہ موت کا قائل نہیں۔ وہ ان کو دریا میں گراتا ضرور ہے مگر بعد میں بتاتا ہے کہ وہ ڈوبا نہیں تھا یعنی مر نہیں گیا تھا، کسی نہ کسی ذریعے سے ( انور کمال پاشا کے اپنے دماغ کی عجیب و غریب تخلیق ہوتا ہے) زندہ رہا تھا۔
معلوم نہیں، میں کہاں تک صحیح ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انور کمال پاشا کی زندگی بھی شاید ڈوب ڈوب کر زندہ رہنے سے دوچار رہی ہے۔
اس نے اپنی زندگی میں کئی ندیاں پار کی ہیں۔ ایک تو وہ تھی جو سہرے جلوے کی بیاہی ہوئی تھی۔ اس کو پار کرنے میں تو خیر اس کو کوئی دقّت محسوس نہ ہوئی ہوگی مگر جب اس کے سامنے وہ ندی جس کا نام شمیم تھا، بمبئی سے بہتی ہوئی لاہور آئی تو اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ ماہر تیراک کے مانند اسے بھی پار کر گیا۔ اس کو بہت دیر سے فلم بینی کا شوق تھا۔ بعد میں یہ شوق اس دھن میں تبدیل ہوگیا کہ وہ ایک فلم بنائے۔ جب شمیم سے اس کی راہ و رسم ہوئی تو اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور لاؤڈ اسپیکر بن کر ہر طرف گونجنے لگا کہ ’’آؤ میں فلم بنانا چاہتا ہوں۔ ہے کوئی سخی ایسا جو مجھے سرمایہ دے۔‘‘
اس کی مسلسل صدا پر آخر کار اسے سرمایہ مل گیا۔ شمیم بمبئی میں ایک ایسی ندی تھی جس کا پانی بہت صاف ستھرا تھا۔ اس میں کئی غواص تیر چکے تھے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ پانی پتھر کی طرح ٹھہر گیا اس لیے کہ تیراکوں کے لیے وہ دل چسپی کا سامان نہ رہی۔ یہی وجہ ہے اسے اپنے وطن لاہور میں واپس آنا پڑا۔ خیر اس قصے کو چھوڑیے۔ یہ کوئی اصول اور لگا بندھا قاعدہ تو نہیں لیکن عام طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے۔ فلم ڈائریکٹر، عورت کے ذریعے ہی سے آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے بھی اس کی وجہ سے ہٹتے ہیں اور ایسے ہٹتے ہیں یا ہٹائے جاتے ہیں کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔
پاشا نے تھوڑی دیر کے بعد شمیم سے شادی کر لی جو اپنا تنگ ماتھا، چوڑا کرنے کے لیے قریب قریب ہر روز اپنے بال موچنے سے نوچتی رہتی تھی۔ پاشا نے اس کی خوشنودی کی خاطر ضرور مصنوعی طور پر اپنے سارے پر و بال نوچ کے اس کے سامنے پلیٹ میں ڈال کر رکھ دیے ہوں گے۔ میں اب لمبے مضمون کو مختصر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں انور کمال پاشا کی طرح طوالت پسند ہونا نہیں چاہتا۔ وہ بہت دل چسپ شخصیت کا مالک ہے اور اس شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ وہ ہٹ دھرم بھی ہے اور تلون مزاج بھی، بکواسی بھی اور بعض اوقات سنجیدہ مزاج بھی۔
میں آپ کو اختتامی طور پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں آج سے کچھ عرصہ پہلے شاہ نور اسٹوڈیو میں تھا، جہاں انور کمال پاشا اپنے فلم ’’گمنام‘‘ کی شوٹنگ میں مصروف تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، میں اپنے کمرے کے باہر کرسی پر بیٹھا ٹائپ رائٹر میزپر رکھے کچھ سوچ رہا تھا کہ پاشا اپنی کار سے اترا اور میرے پاس والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ علیک سلیک ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھ سے کہا:
’’منٹو صاحب! میں ایک سخت الجھن میں گرفتار ہوں۔‘‘
میں نے اپنے خیالات جھٹک کر پوچھا، ’’کیا الجھن ہے آپ کو؟‘‘
اس نے کہا، ’’یہ فلم جو میں بنا رہا ہوں، اس میں ایک مقام پر اٹک گیا ہوں، آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں، ممکن ہے آپ مشکل کشائی کرسکیں۔‘‘ میں نے اس سے کہا، ’’میں حاضر ہوں فرمائیے! آپ کہاں اٹکے ہوئے ہیں؟‘‘ اس نے مجھے اپنے فلم کی کہانی سنانا شروع کردی۔ دو سین تفصیل سے اس انداز میں سنائے جیسے پولیس جیپ میں بیٹھی لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے راہ چلتے لوگوں کو ہدایت کررہی ہے کہ انہیں بائیں ہاتھ چلنا چاہیے۔ میں اپنی زندگی میں ہمیشہ الٹے ہاتھ چلا ہوں اس لیے میں نے پاشا سے کہا، ’’آپ کو ساری کہانی سنانے کی ضرورت نہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کس گڑھے میں پھنسے ہوئے ہیں۔‘‘ پاشا نے حیرت آمیز لہجے میں مجھ سے پوچھا،’’آپ کیسے سمجھ گئے؟‘‘ میں نے اس کوسمجھا دیا اور اس کی مشکل کا حل بھی بتا دیا۔ جب اس نے میری تجویز سنی تو اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیا اور اس کے بعد کہا،’’ہاں کچھ ٹھیک ہی معلوم ہوتا ہے۔‘‘
میں ذرا چڑ سا گیا، ’’حضرت! اس سے بہتر حل آپ کو اور کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ مصیبت یہ ہے کہ میں فوری طور پر سوچنے کا عادی ہوں۔ اگر میں نے یہی حل آپ کو دس بارہ روز کے بعد پیش کیا ہوتا تو آپ نے کہا ہوتا سبحان اللہ۔ مگر اب کہ میں نے چند منٹوں میں آپ کی مشکل حل کر دی ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں کچھ ٹھیک ہی معلوم ہوتا ہے۔ آپ کو شاید اس مشورے کی قیمت معلوم نہیں۔‘‘ پاشا نے فوراً اپنے پروڈکشن منیجر کو بلایا۔ اس سے چیک بک لی اور اس پر کچھ لکھا۔ چیک پھاڑ کر بڑے خلوص سے مجھے دیا، ’’آپ یہ قبول فرمائیں۔‘‘ اس کے اصرار پر میں نے یہ چیک لے لیا جو پانچ سو روپے کا تھا۔ یہ میری زیادتی تھی۔ اگر میں آسودہ حال ہوتا تو یقیناً میں نے یہ چیک پھاڑ دیا ہوتا لیکن انسان بھی کتنا ذلیل ہے یا اس کے حالات زندگی کتنے افسوس ناک ہیں کہ وہ گراوٹ پر مجبور ہو جاتا ہے۔۔۔!
(فلم انڈسٹری کے بے مثل ہدایت کار، اور فلم ساز انور کمال پاشا کے شخصی خاکے سے اقتباسات جس کے مصنّف سعادت حسن منٹو ہیں اور یہ خاکہ مصنّف کی 1955ء میں شائع ہونے والی کتاب میں شامل ہے)

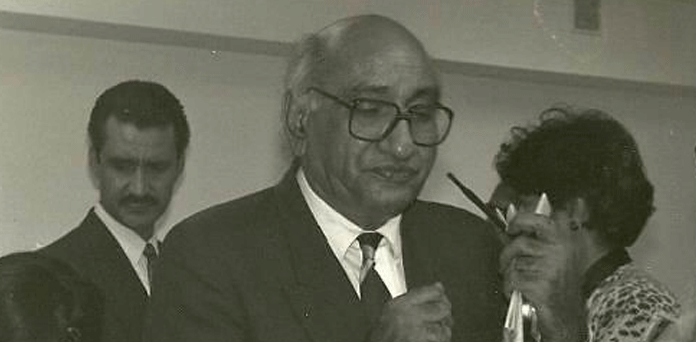


 اس فلم کی کہانی کا مرکزی خیال ایک باپ بیٹے کے تعلق کے گرد گھومتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں کم بات کرتے ہیں جب کہ باپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹے کو خیال سوجھتا ہے کہ باپ کو تنہائی اور فراغت سے بچانے کے لیے ویڈیو گیم کھیلنا سکھائے جو جاپان میں بے حد مقبول ہے۔ اس ویڈیو گیم کو کھیلتے کھیلتے باپ بیٹے میں جذباتی فاصلہ کم ہونے لگتا ہے، روزمرہ کی زندگی کے معاملات اور الجھنوں کو اس گیم کے ذریعے دونوں باپ بیٹے سلجھانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ان کی زندگی پر بھی خوشگوار اثرات پڑتے ہیں۔ اسی فلم کو کراچی میں این ای ڈی یونیورسٹی میں بھی دکھایا گیا، جہاں طلبا نے اسے بے حد پسند کیا۔ اس فلم اسکریننگ کے موقع پر جاپان کے ڈپٹی قونصل جنرل جناب ناکاگاوایا سوشی نے اساتذہ و طلبا سے خطاب بھی کیا۔
اس فلم کی کہانی کا مرکزی خیال ایک باپ بیٹے کے تعلق کے گرد گھومتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں کم بات کرتے ہیں جب کہ باپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹے کو خیال سوجھتا ہے کہ باپ کو تنہائی اور فراغت سے بچانے کے لیے ویڈیو گیم کھیلنا سکھائے جو جاپان میں بے حد مقبول ہے۔ اس ویڈیو گیم کو کھیلتے کھیلتے باپ بیٹے میں جذباتی فاصلہ کم ہونے لگتا ہے، روزمرہ کی زندگی کے معاملات اور الجھنوں کو اس گیم کے ذریعے دونوں باپ بیٹے سلجھانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ان کی زندگی پر بھی خوشگوار اثرات پڑتے ہیں۔ اسی فلم کو کراچی میں این ای ڈی یونیورسٹی میں بھی دکھایا گیا، جہاں طلبا نے اسے بے حد پسند کیا۔ اس فلم اسکریننگ کے موقع پر جاپان کے ڈپٹی قونصل جنرل جناب ناکاگاوایا سوشی نے اساتذہ و طلبا سے خطاب بھی کیا۔