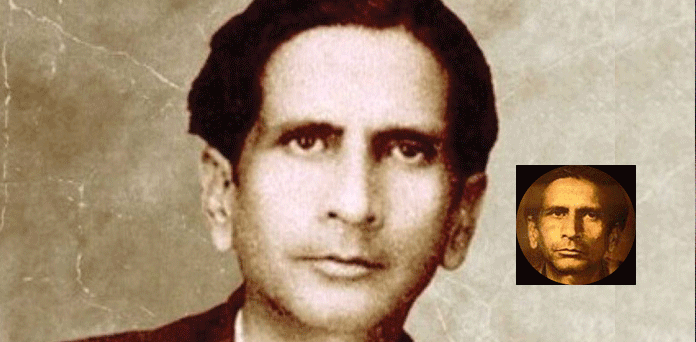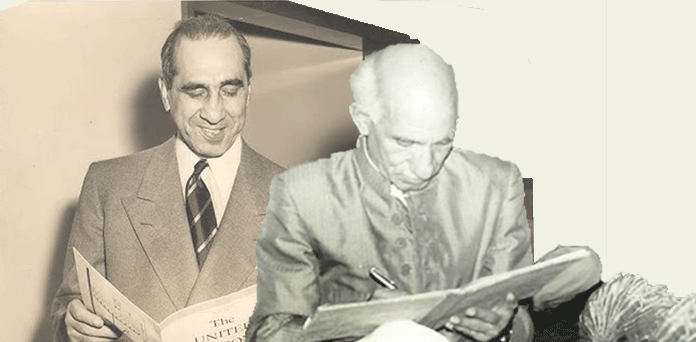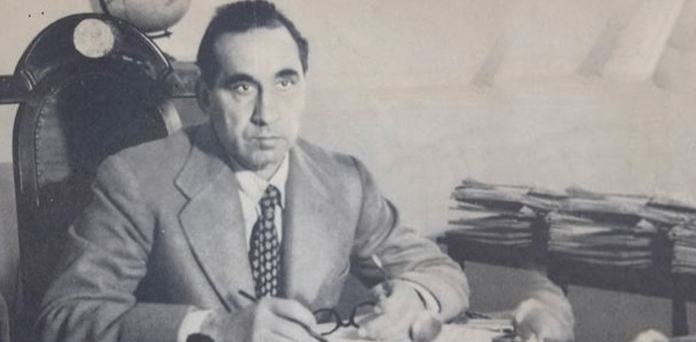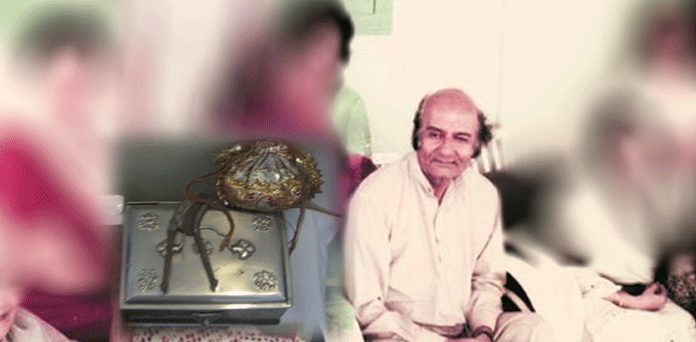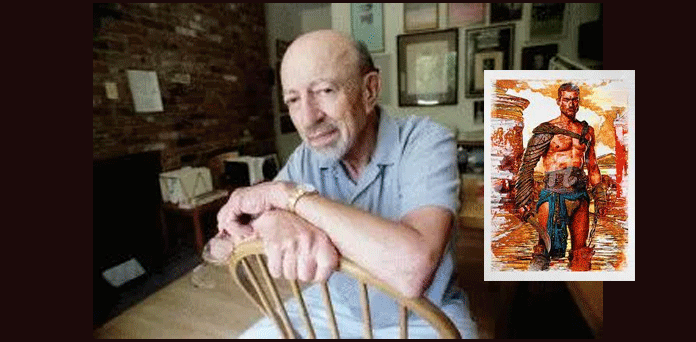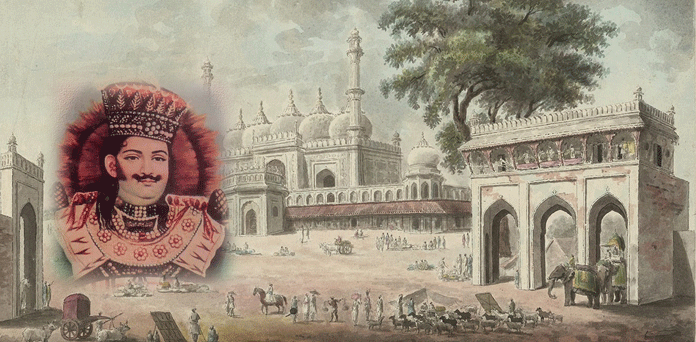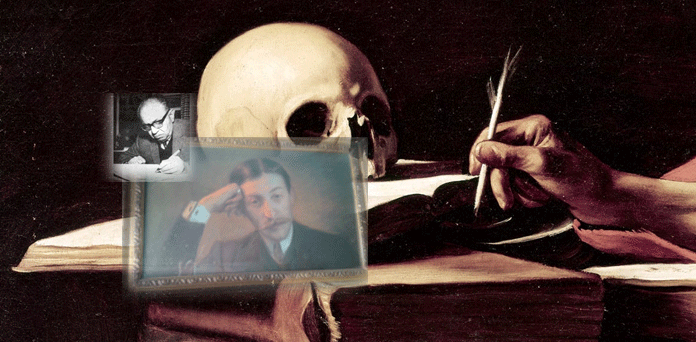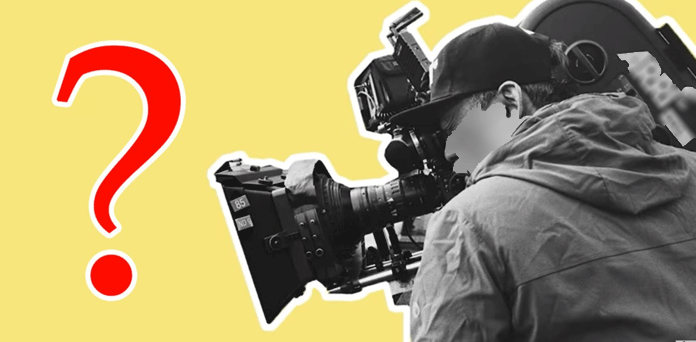یہ مجازؔ کا تذکرہ ہے، وہ مجاز جس کا کلام ہندوستان بھر میں مقبول تھا اور خاص طور پر نوجوان لڑکے لڑکیاں جس کے اشعار جھوم جھوم کر پڑھا کرتے تھے۔ مجاز کی نظموں میں جذبات کی شدّت اور ایسا والہانہ پن تھا جس نے ہر خاص و عام کو متاثر کیا۔ شاعر اسرارُ الحق مجازؔ کی نظم ’آوارہ‘ نے اپنے دور میں سبھی کو چونکا دیا تھا۔ یہ نظم بہت مقبول ہوئی اور ہر باذوق کی زبان پر جاری ہوگئی تھی۔ مجاز کو شراب نے اتنا خراب کیا کہ عین جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔ وہ اردو شاعری کے آسمان پر گویا لمحوں کے لیے چمکے اور پھر ہمیشہ کے لیے سب کی نظروں سے اوجھل ہوگئے۔
معروف ادیب مجتبیٰ حسین کی مجاز سے آخری ملاقات کراچی میں ہوئی جہاں مجاز مشاعرہ پڑھنے آئے تھے۔ اس وقت وہ ہڈیوں کا ڈھانچا ہوگئے تھے۔ شراب نے انھیں برباد کردیا تھا۔ لکھنؤ میں انتقال کرنے والے مجاز کا خاکہ مجبتیٰ حسین کی کتاب نیم رُخ میں شامل ہے۔ مجبتیٰ حسین لکھتے ہیں:
بارے مجاز ڈائس پر آئے۔ انہوں نے "اعتراف” سنانی شروع کی۔ وہ پڑھ نہیں پا رہے تھے۔ ان کی سانس بار بار ٹوٹ جاتی اور وہ رک جاتے۔ انہیں مستقل کھانسی آ رہی تھی اور وہ ہر جھٹکے کے ساتھ سینہ تھام لیتے۔ طلبہ کا مجمع کچھ بے چین اور بے کیف ہوا جا رہا تھا۔ بعض گوشوں سے ہوٹنگ بھی شروع ہو چکی تھی۔ مگر مجاز سامعین کی اکتاہٹ سے بے خبر ہو کر پڑھے جا رہے تھے:
خاک میں آہ ملائی ہے جوانی میں نے
شعلہ زاروں میں جلائی ہے جوانی میں نے
شہر خوباں میں گنوائی ہے جوانی میں نے
خواب گاہوں میں جگائی ہے جوانی میں نے
ان کی آواز میں ایک عجیب حزن آ گیا تھا۔ مجاز اپنی بربادی کا مرقع بنے ہوئے نظم پڑھ رہے تھے۔ ان کی لے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹتا نہیں تھا، بیچ میں ٹوٹ ٹوٹ جاتی تھی۔ مگر اس ٹوٹ جانے میں بھی ایک کیفیت تھی۔ ایک عظیم شکست و ریخت کا تاثر تھا۔ رفتہ رفتہ مجمع کی ہنسی رک گئی۔ اور خاموشی چھا گئی۔ دفعتاً میرے پاس بیٹھے ہوئے ایک طالب علم نے دوسرے سے پوچھا ’یہ کون شاعر ہے۔‘
معلوم نہیں اس نے کیا جواب دیا۔ کیا جانے اسے بھی معلوم ہو یا نہ رہا ہو۔ میں اس سوال کے بعد کچھ اور نہیں سن سکا۔ زمانہ اتنا بدل گیا ہے، اس کا احساس مجھے اس وقت ہوا۔ جس مجاز کے نام پر بقول عصمت چغتائی، لڑکیاں قرعے ڈالتی تھیں۔ جس کے نام کی قسمیں کھائی جاتی تھیں۔ آج اسے ایک درس گاہ کی ادبی محفل میں طالب علم جانتے بھی نہیں۔ اس کے بعد میں مجاز سے کبھی نہیں مل سکا۔