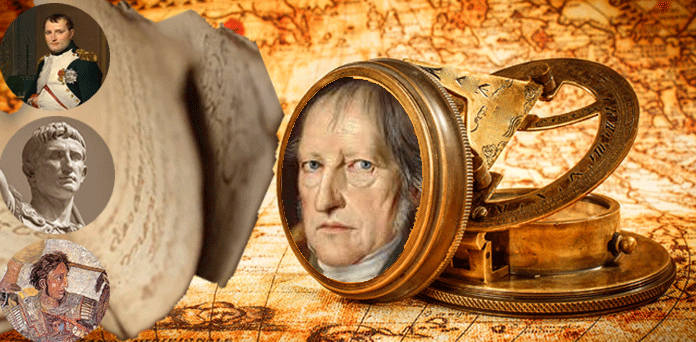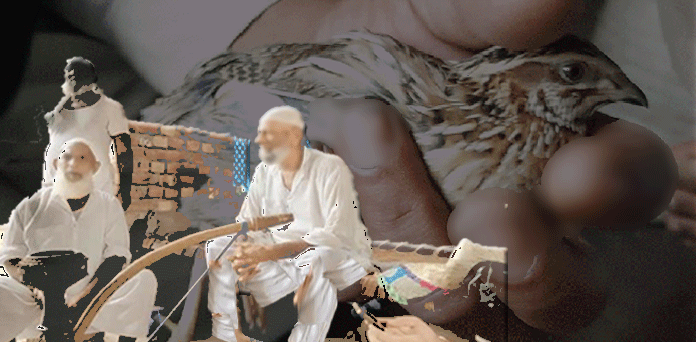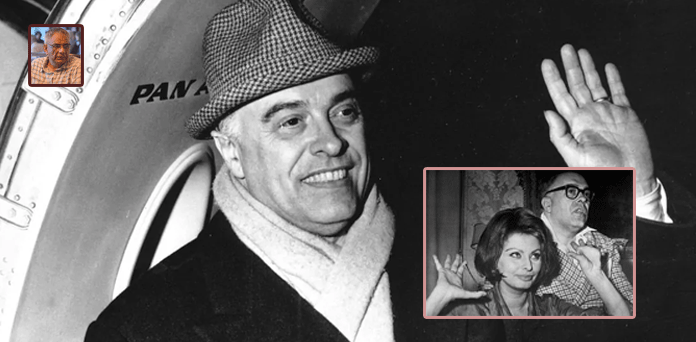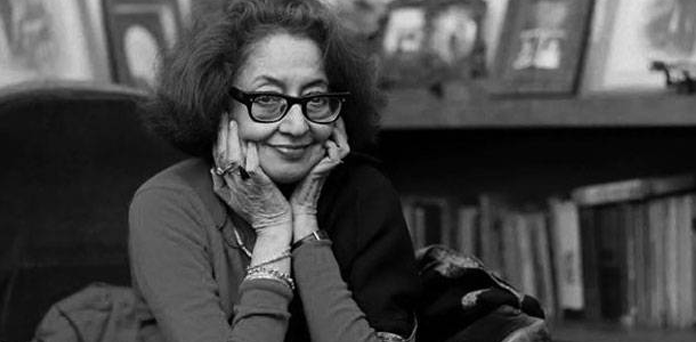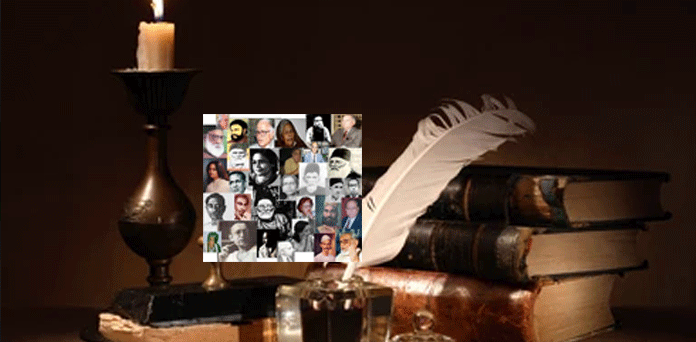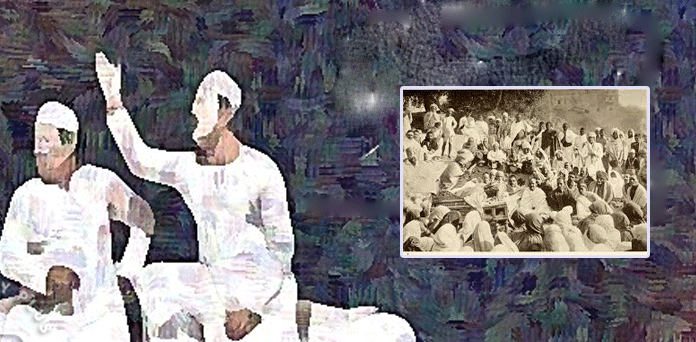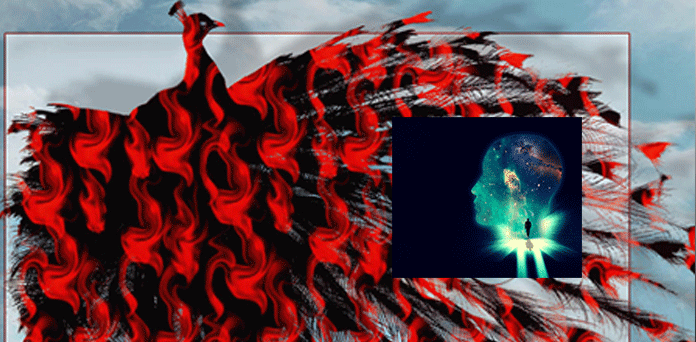پریم چند ایک بڑے افسانہ نگار اور مصنّف تھے جنھوں نے عام معاشرتی برائیوں اور لوگوں میں رائج بعض غلط تصورات، مخرب الاخلاق باتوں اور بھونڈے انسانی رویوں کی نشان دہی بھی کی اور بغرضِ اصلاح ان پر مضامین بھی لکھے۔ اردو ادب میں ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ یہ پریم چند کی ایک ایسی تحریر ہے جس میں انھوں نے بھارتی سماج میں گالی اور بدکلامی کی عادت کو موضوع بنایا ہے۔
پریم چند لکھتے ہیں، "گالی ہمارا قومی خمیر ہوگئی ہے۔ کسی یکہ پر بیٹھ جائیے اور سنیے کہ یکہ بان اپنے گھوڑے کو کیسی گالیاں دیتا ہے۔ ایسی فحش کہ طبیعت مالش کرنے لگے۔ اس غریب گھوڑے کی ذات خاص اور اس کی مادرِ مہربان اور اس کے پدرِ بزرگوار اور اس کے جدِ ناہنجار سب اس نیک بخت اولاد کی بدولت گالیاں پاتے ہیں۔”
"ہندوستان ہی تو ہے۔ یہاں کے جانوروں کو بھی گالیوں سے لگاؤ تھا ہی۔ سرکار فیض مدار نے آج کل گالیاں بکنے کے لیے ایک محکمہ قائم کر رکھا ہے۔ اس محکمہ میں شریف زادے اور رئیس زادے لیے جاتے ہیں۔ انہیں بیش قرار مشاہرے دیے جاتے ہیں اور رعایا کے امن و امان کا بار ان پر رکھا جاتا ہے۔ اس محکمہ کے لوگ گالیوں سے بات کرتے ہیں۔ ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے، مغلظ نجاست میں ڈوبی ہوئی، یہ لوگ گالیاں بکنا حکومت کی علامت اور اپنے منصب کی شان سمجھتے ہیں۔”
"یہ بھی ہماری کج فہمی کی ایک مثال ہے کہ ہم گالی بکنے کو امارت کی شان خیال کرتے ہیں۔ اور ملکوں میں زبان کی پاکیزگی اور شیریں بیانی، بشرہ کی متانت اور بردباری، شرافت اور امارت کے ارکان سمجھے جاتے ہیں۔ اور بھارت ورش میں زبان کی غلاظت اور بشرہ کا جھلا پن حکومت کا جزو خیال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے فربہ اندام زمیندار اپنے اسامی کو کیسی گالیاں دیتا ہے۔ جناب تحصیل دار صاحب اپنے باورچی کو کیسی صلواتیں سنا رہے ہیں، اور سیٹھ جی اپنے کہار پر کن نجس الفاظ میں گرم ہوتے ہیں۔ غصہ سے نہیں صرف شان تحکم جتانے کے لیے۔ گالی بکنا ہمارے یہاں ریاست اور شرافت میں داخل ہے۔ واہ رے ہم!”
"ان پھٹکل گالیوں سے طبیعت آسودہ نہ ہوتی دیکھ کر ہمارے بزرگوں نے ہولیؔ نام کا ایک تہوار نکالا کہ ایک ہفتہ تک ہر خاص و عام خوب دل کھول کر گالیاں دیتے ہیں۔ یہ تہوار ہماری زندہ دلی کا تہوار ہے۔ ہولی کے دنوں میں ہماری طبیعتیں خوب جولانی پر ہوتی ہیں اور ہفتہ بھر تک زبانی نجاست کا ایک غبار سا ہمارے دل و دماغ پر چھایا رہتا ہے۔ جس نے ہولی کے دن دو چار کبیر نہ گائے اور دو چار درجن مغلظات زبان سے نہ نکالے وہ کہے گا کہ ہم آدمی ہیں۔ زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے۔”
"سخن تکیہ کے طور پر بھی گالیاں بکنے کا رواج ہے۔ اور اس مرض میں زیادہ تر نیم تعلیم یافتہ لوگ گرفتار پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کوئی منتخب گالی چن لیتے ہیں اور دوران گفتگو میں اسے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ان کا سخن تکیہ ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات ان کے منہ سے بے اختیار طور پر نکل پڑتی ہے۔ یہ نہات شرم ناک عادت ہے۔ اس سے اخلاقی کمزوری کا پتہ چلتا ہے اور اس سے گفتگو کی متانت بالکل خاک میں مل جاتی ہے۔ جن لوگوں کی ایسی عادت پڑ گئی ہو انہیں طبیعت پر زور ڈال کر زبان میں پاکیزگی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔”
"القصہ ہم چاہے کسی اور بات میں شیر نہ ہوں، بد زبانی میں ہم یگانہ روزگار ہیں۔ کوئی قوم اس میدان میں ہم کو نیچا نہیں دکھا سکتی۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے ہی ایسے اصحاب ہیں جن کی زبان کی پاکیزگی پر کوئی حرف نہیں رکھا جاسکتا ہے۔ مگر قومی حیثیت سے ہم اس زبردست کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں۔ قوم کی پستی یا بلندی چند منتخب افراد قوم کی ذاتی کمالات پر منحصر نہیں ہوسکتی۔”
"حق تو یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے رہنماؤں نے اس وبائے عام کی بیخ کنی کرنے کی سرگرم کوشش نہیں کی۔ تعلیم کی سست رفتار پر اس کی اصلاح چھوڑ دی اور عام تعلیم جیسی کچھ ترقی کر رہی ہے، اظہر من الشمس ہے۔ اس امر کے اعادہ کی ضرورت نہیں کہ گالیوں کا اثر ہمارے اخلاق پر بہت خراب پڑتا ہے۔ گالیاں ہمارے نفس کو مشتعل کرتی ہیں۔ اور خود داری و پاسِ عزت کا احساس دلوں سے کم کرتی ہیں جو ہم کو دوسری قوموں کی نگاہوں میں وقیع بنانے کے لیے ضروری ہیں۔”
(ماخذ: مضامینِ پریم چند، بعنوان گالیاں)