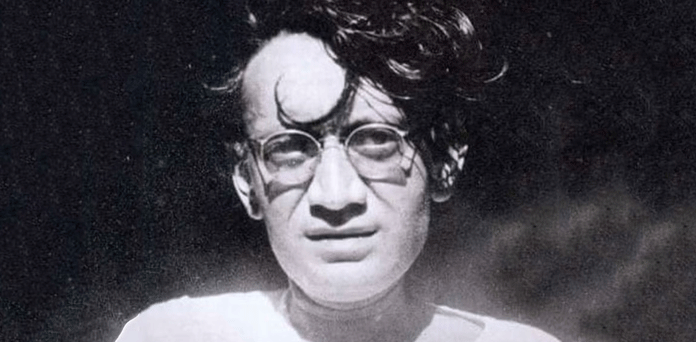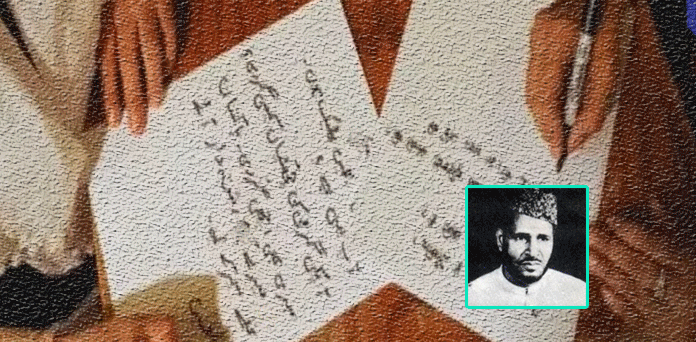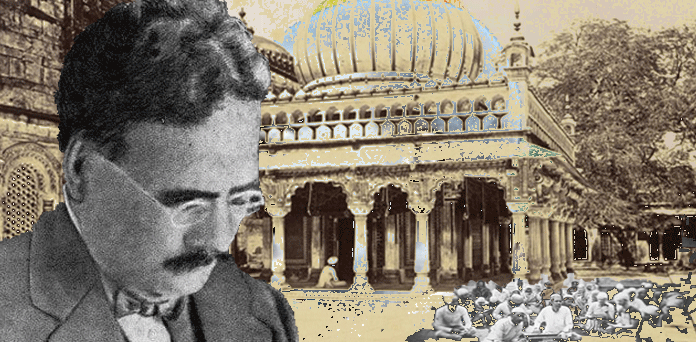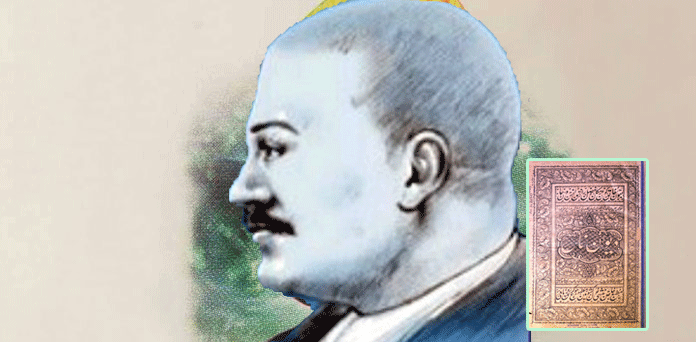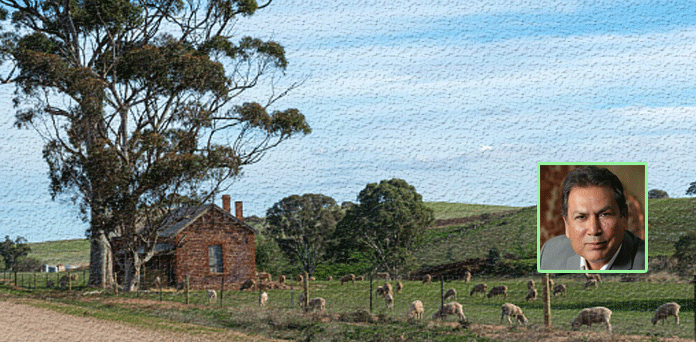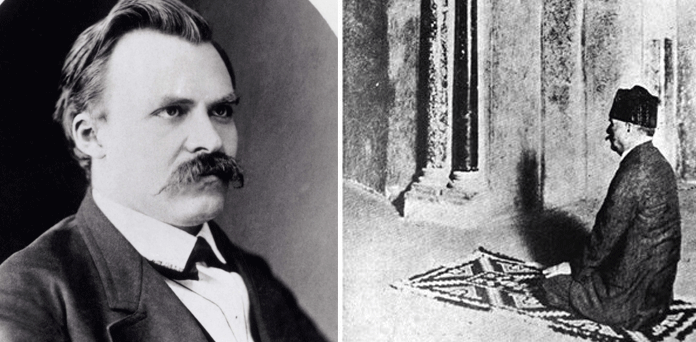برصغیر کے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب ہمہ گیر شخصیت کے حامل تھے، اس دور کے مروجہ علوم پر انھیں مکمل عبور حاصل تھا۔ تاہم ان کی وجہِ شہرت شاعری تھی جو دو صدیاں گزرنے کے بعد بھی کم نہیں ہوئی۔
شعر و ادب کے ساتھ غالب کی شخصیت خصوصاً ان کا شاعرانہ مزاج بھی ہمیشہ لوگوں کی دلچسپی کا مرکز رہا۔ اس شاعرانہ بلکہ شاہانہ مزاج کی بدولت وہ تاحیات زیر بار قرض رہے مگر اپنی روش نہیں بدلی۔ ان کا اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا بس انگریز سرکار سے ملنے والی خاندانی پنشن پر گزارا تھا۔ یہ پنشن غالب کے گھریلو اور ”ذاتی“ اخراجات کے لیے ناکافی تھی۔ لہذا مرزا تا حیات قرض پہ قرض لیتے رہے۔ قرض کی نا دہندگی کی وجہ سے اکثر مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا بلکہ قید و بند کے مراحل سے بھی گزرنا پڑا۔ اس دور میں انگریز سرکار کا قانون تھا کہ دیوانی مقدمات میں ملوث ملزمان کو گھر سے باہر اور دن کے وقت ہی حراست میں لے سکتے تھے۔ لہٰذا جب گرفتاری کا خدشہ ہوتا تو ان دنوں غالب دن کے اجالے میں گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ اگر کہیں جانا ہوتا تو رات کے وقت جاتے۔
قرض خواہوں کو تسلی دینے اور اپنی آمدنی میں اضافے کی غالب کے پاس ایک ہی امید تھی کہ ان کی پنشن میں اضافہ ہو جائے اور یہ اضافہ بھی ان کی پیدائش کے وقت سے ہو تاکہ انھیں یکمشت ایک خطیر رقم حاصل ہو جائے۔ اس امید پر مرزا نے عمر گزار دی۔ قریباً تیس برس اسی تگ و دو میں گزرے۔ ان گنت درخواستیں دائر کیں جو مقامی افسران سے لے کر گورنر جنرل اور ملکہ برطانیہ تک کو ارسال کی گئیں۔
انگریز افسروں کے روبرو اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے غالب نے متعدد سفر کیے جس میں کان پور، فیروز پور جھرکا اور فرحت پور شامل ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا طویل ترین سفر دہلی سے کلکتے کا تھا اور یہی غالب کی زندگی کا سب سے لمبا سفر تھا۔ تقریباً تین برس پر محیط اس سفر نے غالب کے مشاہدات و تجربات اور علم و فکر میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔
اس سے قبل کہ مرزا غالب کے سفر کی روداد بیان کی جائے اس سفر کی وجہ یعنی انھیں ملنے والی پنشن اور ان کے خاندانی پس منظر کا مختصر جائزہ لے لیتے ہیں۔ غالب 1797 ء میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ابھی چار برس کے تھے کہ ان کے والد مرزا عبداللہ انتقال کر گئے۔ لہذا غالب کے خاندان کے سرپرست ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ قرار پائے۔ نصر اللہ بیگ مرہٹوں کی فوج میں شامل تھے اور آگرہ کی حفاظت پر مامور تھے۔ جب انگریزوں نے آگرہ حملہ کیا تو نصر اللہ بیگ نے بغیر مزاحمت کے آگرہ انگریزوں کے کمان دار لارڈ لیک کے حوالے کر دیا۔ اس کے بدلے میں انگریزوں نے نصر اللہ بیگ کو آگرہ کے قلعے کا قلعہ دار بنا دیا۔ علاوہ ازیں انھیں جاگیر اور انعام و کرام سے بھی نوازا۔ لیکن یہ انعام و کرام اور جاگیریں تا دیر نصر اللہ بیگ کے کام نہ آئیں اور 1806 ء میں ہاتھی سے گر کر انتقال کر گئے۔ ان کے بیوی بچے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ جیسا کہ انگریزوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے وفاداروں کو نسل در نسل نوازتے تھے، سرکار نے پس ماندگان کے لیے پنشن مقرر کر دی جس کے نگران نصر اللہ بیگ کے سالے نواب احمد بخش قرار پائے۔ ان کے بقول یہ رقم پانچ ہزار روپے سالانہ تھی۔ جس کی تقسیم کچھ یوں ہوئی (1) خواجہ حاجی دو ہزار روپے سالانہ (2) نصر اللہ بیگ کی والدہ اور تین بہنیں ڈیڑھ ہزار روپے سالانہ (3) مرزا غالب اور ان کے بھائی مرزا یوسف ڈیڑھ ہزار روپے سالانہ۔ غالب اس میں سے چھ سو سالانہ بھائی مرزا یوسف کو دیتے تھے۔ جبکہ بقیہ نو میں سے چار سو اپنی زوجہ امراؤ جان کو دینے کا حکم تھا کیونکہ امراؤ جان نواب احمد بخش کی بھتیجی تھی۔ مرزا غالب اور امراؤ جان کا عقد 1810 ء میں ہوا تھا اس وقت غالب کی عمر تیرہ اور امراؤ جان کی دس برس تھی۔ اسی برس غالب آگرہ سے دہلی منتقل ہو گئے۔ دہلی میں وہ کرائے کے مختلف مکانات میں فروکش رہے ان میں سے آخری بلی ماراں والا مکان تھا۔
مرزا غالب نے ہوش سنبھالا تو انھیں علم ہوا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ان کے اعتراضات یہ تھے۔ (اول) پنشن کی اصل رقم پانچ نہیں دس ہزار روپے سالانہ ہے۔ (دوئم) خواجہ حاجی ان کے برائے نام رشتہ دار تھے اس لیے ان کو دی جانے والی رقم غالب اور ان کے بھائی کو ملنی چاہیے۔ مرزا غالب نے جب یہ معاملہ نواب احمد بخش کے سامنے اٹھایا تو بقول غالب انھوں نے پنشن کی رقم دس ہزار تو تسلیم نہیں کی، لیکن خواجہ حاجی کو حصہ دینے کی غلطی تسلیم کی اور وعدہ کیا کہ خواجہ حاجی کے انتقال کے بعد ان کا حصہ غالب اور ان کے بھائی کو ملے گا۔
لیکن 1823 ء میں خواجہ حاجی کے انتقال کے بعد یہ رقم ان کے بیٹوں کو ملنے لگی۔ یہیں سے غالب کی شکایت میں شدت پیدا ہوئی۔ انھوں نے اس نا انصافی پر آواز اٹھائی لیکن کہیں شنوائی نہیں ہوئی۔ نواب احمد بخش سے مایوس ہو کر غالب نے دلی میں تعینات انگریز ریذیڈنٹ سے ملاقات کی کوشش شروع کر دی مگر بوجوہ یہ ملاقات نہ ہو سکی یا احمد بخش نے نہ ہونے دی۔ 1825 ء تک غالب کی مالی حالت انتہائی دگرگوں ہو چکی تھی۔ وہ ننھیال اور ددھیال کی تمام موروثی جائیداد بیچ کر کھا چکے تھے اس پر مستزاد بیس ہزار روپے کے مقروض ہو چکے تھے۔
اس وقت غالب کی عمر صرف اٹھائیس برس تھی۔ اس سے غالب کی شاہ خرچی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ آمدنی جتنی بھی ہو ان کا طرز حیات نہیں بدلا۔ ایک مرتبہ متھرا داس مہاجن نے عدم ادائیگی قرض پر غالب پر مقدمہ کر دیا۔ غالب مفتی صدر الدین آزردہ کی عدالت میں پیش ہوئے جو خود اچھے شاعر اور غالب کے مداح تھے۔ انھوں نے غالب سے پوچھا ”مرزا نوشہ یہ آپ اس قدر قرض کیوں لیا کرتے ہیں“ غالب نے برجستہ جواب میں یہ شعر سنایا:
قرض کی پیتے تھے مے لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں
رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن
مفتی صدر الدین ہنس پڑے۔ انھوں نے فیصلہ تو مدعی کے حق میں دیا لیکن غالب کا زر ڈگری ایک دوست کی حیثیت سے خود ادا کر دیا۔
مرزا غالب کا بال بال قرضے میں جکڑا تھا مگر اس معاملے میں وہ خوش قسمت بھی تھے کہ کسی نہ کسی سے مزید قرض لے لیتے تھے۔ حالانکہ قرض دینے والوں کو بھی علم تھا کہ اس کی واپسی تقریباً نا ممکن ہے۔ جیسا کہ متھرا داس مہاجن غالب کے گھر قرض کی واپسی کا تقاضا کرنے گئے، الٹا دو ہزار روپے مزید دے کر لوٹے۔ ان معاملات کے باوجود غالب کی شاعری اور ان کی شخصیت کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ حتٰی کہ ان کے مخالفین بھی ان کی شاعری کے معترف تھے۔
ویسے بھی وہ فن شاعری کی قدرو منزلت کا دور تھا۔ مشاعروں میں ہزاروں کا مجمع ہوتا۔ جہاں چار پڑھے لکھے افراد جمع ہوتے شعر و شاعری کا تذکرہ لازمی ہوتا۔ غالب کی شاعری نوجوانی میں ہی سند قبولیت حاصل کر چکی تھی۔ ابھی ان کا دیوان شائع نہیں ہوا تھا کہ ان کے اشعار زبان زد عام ہو چکے تھے۔ کوٹھے کی مغنیہ ہو یا گلی میں پھرتے بنجارے ہر ایک کی زبان پر غالب کے اشعار ہوتے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں زندگی شاعری کے بل بوتے نہیں گزرتی، اس کے تقاضے اور بھی ہیں۔
جب دہلی میں شنوائی نہیں ہوئی تو غالب نے کلکتہ جا کر گورنر جنرل سے ملنے کا ارادہ کر لیا۔ اس دور میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے بھی ویسی ہی تیاری کرنی پڑتی تھی جیسے پردیس جا رہے ہوں۔ اکتوبر 1826ء میں غالب براستہ کانپور لکھنؤ پہنچے۔ دوران سفر وہ بیمار پڑ گئے وہ بھی ایسے کہ صحت یاب ہوکے نہیں دیتے تھے۔ اگرچہ اس وقت وہ نوجوان تھے مگر انھیں کئی بیماریاں لاحق تھیں۔ اودھ میں مرزا کے قریبی دوست امام بخش ناسخ رہتے تھے ان کی بدولت غالب کا علاج جاری رہا۔
ان دنوں اودھ پایہ تخت دہلی سے آزاد ایک خود مختار ریاست تھی۔ غازی الدین حیدر اس کے بادشاہ تھے معتمد الدولہ آغا میر وزیر اعظم تھے۔ آغا میر شعر و شاعری کے قدردان تھے اور شعرا کی سرپرستی کرتے رہتے تھے۔ انھوں نے غالب سے ملنے خواہش ظاہر کی۔ غالب کو خلعت اور انعام کرام ملنے کی امید پیدا ہوئی۔ انھوں نے اپنے دوست امام بخش ناسخ کے مشورے پر آغا میر کے لیے ایک سو دس اشعار پر مشتمل قصیدہ لکھا۔ مگر اپنی افتادِ طبع کے مطابق تین شرائط بھی رکھ دیں۔
پہلی شرط یہ کہ معتمد الدولہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں گے۔ دوسری شرط، ان سے معانقہ کریں گے اور تیسری شرط، غالب کو نذر پیش کرنے سے معافی دی جائے۔ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ وزیر اعظم نے غالب کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا اور غالب نے ملاقات سے معذرت کر لی۔ غریب الوطنی اور مالی مجبوریوں کے باوجود حاکم وقت کے آگے ایسی شرائط رکھنا اور پھر ملنے سے انکار کرنا، بظاہر نادانی لگتی ہے مگر وہ غالب تھے۔ ایسے لوگ دماغ سے نہیں دل سے سوچتے ہیں۔ ان کی طبیعت کا غنا انھیں کسی کے آگے سر جھکانے نہیں دیتا۔ انھی کا مشہور شعر ہے۔
بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب
تماشائے اہلِ کرم دیکھتے ہیں
شاہ میر غالب کے خلاف ہو گیا اور اس نے انھیں شاہ اودھ سے بھی ملنے نہیں دیا۔ غالب نو ماہ تک لکھنؤ میں مقیم رہے۔ ان کی بیماری میں افاقہ نہیں ہوا۔ مجبوراً اسی حالت میں انھوں نے رخت سفر باندھا اور اکیس جون 1827 ء کو لکھنؤ سے روانہ ہو گئے۔ اس دور کی مشکلات سفر کا اندازہ لگائیے کہ لکھنؤ سے کانپور کے درمیان تقریباً سو کلومیٹر کا فاصلہ پانچ دن میں طے ہوا۔ یہ سفر یکے پر کیا گیا۔ کان پور سے غالب باندہ پہنچے جہاں کے نواب ذوالفقار بہادر علی غالب کے عزیز اور شاگرد تھے۔
انھوں نے غالب کی خوب مدارت کی اور علاج بھی کروایا جس سے انھیں کچھ افاقہ ہوا۔ غالب کلکتہ جانا چاہتے تھے مگر زاد سفر کے نام پر ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ مناسب موقع پا کر انھوں نے نواب ذوالفقار علی سے دو ہزار روپے قرض مانگ لیا۔ غالب کے بقول انھوں نے براہ راست تو یہ رقم نہیں دی کہ شاید میں واپس نہ کر سکوں لیکن ایک مہاجن سیٹھ امی کرن سے دو ہزار روپے قرض دلوا دیے۔ غالب کا مسئلہ وقتی طور پر حل ہو گیا اور وہ دو ہزار روپے لے کر باندے سے بذریعہ بیل گاڑی روانہ ہو گئے۔
راستے میں انھوں نے ایک گھوڑا خرید لیا۔ جمنا کنارے پہنچے تو کشتی کرائے پر لی اور گھوڑے سمیت اس پر سوار ہو گئے۔ ستائیس نومبر 1827ء وہ الہ آباد پہنچے۔ غالب کا ارادہ یہاں چند ہفتے قیام کرنے کا تھا مگر پہلی ہی شام ایک ادبی تقریب میں ان کی مولوی امام شہید سے تلخ کلامی ہو گئی۔ مولوی شہید، قتیل کے شاگرد تھے جس سے غالب شدید متنفر تھے۔ اس واقعہ سے غالب اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ اگلے ہی روز بنارس روانہ ہو گئے۔ اپنے خطوط میں غالب نے الہ آباد کے باسیوں کو آداب محفل سے نا آشنا اور اجڈ قرار دیا۔ انھیں یہ شہر، شہر نہیں ویرانہ لگا۔ آگے کا سفر بھی غالب نے جمنا کی لہروں پر ڈولتی کشتی میں کیا اور وہ بنارس پہنچ گئے۔
بنارس شہر غالب کو خوب بھایا۔ جمنا کے کنارے بسا یہ شہر، اس کے سر سبز نظارے، صبح دم مندروں کی گھنٹیوں کی صدا، سر شام جمنا کے پانیوں کو چھوتی ہوا اور اس کا غارت ایماں حسن غالب کے دل میں گھر کر گیا۔ ان کا دل چاہا کہ ہمیشہ کے لیے اس شہر میں بس جائیں۔ حالانکہ دیگر شہروں کی نسبت بنارس میں ان کا کوئی قریبی دوست نہیں تھا۔ ان کا مزاج بھی ایسا نہیں تھا کہ احباب کے بغیر تنہا خوش رہیں۔ آثار سے لگتا ہے کہ کسی غارت گر کے عشق نے غالب کے قدم روک دیے تھے۔
دوسرا یہ معجزہ بھی ہوا کہ اس شہر کی آب و ہوا غالب کو راس آئی اور ان کی صحت بحال ہو گئی۔ بہرحال انھوں نے چار ہفتے بنارس میں قیام کیا۔ غالب جہاں جہاں قیام کرتے رہے وہاں کے احباب سے سفارشی خطوط بھی لکھوا کر ساتھ رکھتے رہے تاکہ کلکتہ جا کر انھیں استعمال کر سکیں۔ جیسے باندہ کے سول جج نواب محمد علی خان غالب کے دوست بن گئے تھے انھوں نے کلکتے کے ایک معزز نواب اکبر علی خان کے نام رقعہ لکھ دیا۔
دہلی سے کلکتہ کا ایک ہزار میل کا یہ سفر غالب نے 17 ماہ میں طے کیا۔ یوں تو یہ سفر حصول پنشن کی غرض سے تھا مگر مرزا غالب نے اسے سیاحتی، تفریحی اور تہذیبی سفر بھی بنا دیا۔ جس شہر میں جاتے وہاں طویل قیام کرتے، ادبی اور سماجی حلقوں سے رابطے ہوتے اور شعر و شاعری کے جھنڈے گاڑ کر داد و تحسین وصول کرتے۔ اگرچہ زاد سفر قرض لے کر نکلے تھے مگر کہیں تنگ چشمی سے کام نہیں لیا اور دریا دلی سے خرچ کرتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو دو ہزار روپے باندہ سے قرض لے کر نکلے تھے کلکتہ پہنچنے تک اس میں سے چھ صد روپے باقی بچے تھے۔ حالانکہ اس دور میں روپے کی قدر اتنی تھی کہ کلکتہ پہنچ کر انھوں نے جو مکان کرائے پر لیا اس کا ماہانہ کرایہ چھ روپے تھا۔ مکان خاصا بڑا تھا اور اس میں گھوڑا رکھنے کی بھی گنجائش تھی۔
کلکتہ میں ابتدا ہی میں غالب کو اس وقت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب وہ باندے کے نواب محمد علی خان کا تعارفی خط لے کر اور کشتی کرائے پر لے کر نواب اکبر علی خان کے گھر پہنچے جو کلکتہ کے مضافاتی علاقے بگلی میں واقع تھا۔ انھیں معلوم ہوا تھا کہ نواب اکبر علی خان کے انگریز کلکٹر سے دوستانہ روابط ہیں۔ مگر جب غالب گئے تو نواب صاحب نے بتایا کہ کلکٹر صاحب سے ان کے تعلقات اب کشیدہ ہو چکے ہیں اور وہ کسی قسم کی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔
اودھ حکومت کے سفیر منشی عاشق علی سے غالب کو کافی امید تھی اور ان کے نام بھی سفارشی خط لکھو اکر لائے تھے۔ مگر شومئی قسمت سے غالب کے پہنچنے تک منشی عاشق علی کو لکھنؤ واپس بلا لیا گیا۔ گویا ہر جانب مایوسی اور ناکامی کا سامنا تھا۔ جہاں تک ادبی پذیرائی کا تعلق ہے کلکتہ میں بھی غالب کے پرستار موجود تھے مگر ان کی تعداد مٹھی بھر تھی۔ اس کی ایک وجہ تو دہلی سے دوری اور رسل و رسائل کی کمی تھی۔ ویسے بھی یہاں بنگالی زبان بولی جاتی تھی اور اردو کا چلن عام نہیں تھا۔
دوسری وجہ مرزا محمد حسین قتیل (1759۔ 1818) کی مقبولیت تھی۔ مرزا قتیل اپنے عہد کے ممتاز فارسی داں تھے اور فارسی میں ہی شاعری کرتے تھے۔ انھوں نے فارسی قواعد کی چند کتب لکھی تھیں جن میں چہار شربت اور نہر الفصاحت مشہور ہیں۔ اگرچہ ان کا تعلق لکھنؤ سے تھا مگر وہ کلکتہ میں بھی خاصے مقبول تھے۔ جب غالب کلکتہ گئے تو ان کا انتقال ہوئے دس برس گزر چکے تھے لیکن ان کی مقبولیت برقرار تھی۔ دوسری جانب غالب بزعم خود اپنے دور کے سب سے بڑے فارسی دان تھے اور اپنے مقابل کسی کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔
یہ تو سب جانتے ہیں کہ جو غالب کے دل میں ہوتا تھا اسے زبان پر لانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ لہذا قتیل سے ان کی نفرت پوشیدہ نہ رہ سکی۔ دوسری جانب قتیل کے شیدائیوں اور چاہنے والوں کی بڑی تعداد کلکتہ میں تھی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھے۔ ایک مشاعرے میں غالب نے فارسی اشعار سنائے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اعتراض اٹھا دیا کہ اس میں قواعد گرائمر کی غلطی ہے۔ بس پھر کیا تھا غالب کے خلاف شور مچ گیا اور محفل درہم برہم ہو گئی۔ اگلے دن پورے شہر میں اس واقعے کا چرچا تھا۔
غالب کو یہ بھی فکر تھی کہ میں تو واپس دلّی چلا جاؤں گا مگر اس شہر کے لوگ کہیں گے کہ ایک شر پسند اور فسادی شخص آیا تھا فساد برپا کر کے چلا گیا۔ لہذا انھوں نے تحریری معذرت کی اور قتیل کی کچھ توصیف بھی کی۔ بہرحال مرزا غالب کو کلکتے میں وہ پذیرائی حاصل نہ ہو سکی جس کے وہ مستحق تھے۔ اب اسی کلکتے میں اس گلی کا نام غالب سے موسوم ہے جس میں ان کا قیام تھا جس طرح دہلی میں غالب میوزیم اور غالب اکیڈمی موجود ہیں۔ لیکن جانے والے کو اب کیا فائدہ۔ حیات انسانی کے دیگر بے شمار موضوعات کے ساتھ اس موضوع پر بھی غالب کا شعر موجود ہے۔ :
کی مرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ
ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا
کلکتے میں غالب کے مخالفین میں مرزا افضل بیگ نمایاں تھے۔ وہ حاجی جان کے بیٹوں کے ماموں اور ان کے وکیل تھے۔ خاندان مغلیہ کا شاہی وکیل ہونے کے وجہ سے انگریز سرکار سے ان کے قریبی روابط تھے۔ مرزا افضل بیگ نے سرکاری حلقوں اور عوام الناس میں غالب کے خلاف خوب زہر بھرا۔ انھوں نے ہی یہ مشہور کیا تھا کہ غالب قتیل کو برا بھلا کہتے ہیں۔ غالب کو ملحد اور زندیق مشہور کر دیا گیا اور یہ کہ وہ بار بار نام بدلتے رہتے ہیں۔ مجبوراً نام کے معاملے میں غالب کو تحریری صفائی دینی پڑی۔ یوں غالب کے خلاف ہر جانب محاذ کھڑا کیا گیا۔
مارچ 1828ء میں گورنر جنرل کا دربار لگنا تھا۔ درخواست کی جانچ پڑتال اور اس کا انگریزی ترجمہ کرنے کی ذمہ داری William Frazer کی تھی۔ غالب نے اپنی درخواست میں تین استدعا کی تھیں (1) حکومت نصر اللہ بیگ کے ورثا کا تعین خود کرے اور ہر وارث کو الگ پنشن دی جائے (2) دوئم یہ کہ جو رقم نواب احمد بخش نے حکومت سے لی اور ورثا میں تقسیم نہیں کی وہ اس کی جائیداد ضبط کر کے وصول کی جائے اور ورثا میں تقسیم کی جائے (3) آئندہ پنشن براہ راست سرکار کے خزانے سے ادا کی جائے۔
درخواست داخل کرنے کے لیے غالب ولیم فریزر سے ملاقات کے لیے گئے تو انھیں اپنے مقام و مرتبے کا بھی احساس تھا مگر وہ مطمئن لوٹے کیونکہ ولیم فریزر نے کھڑے ہو کر ان کا سلام قبول کیا اور عطر اور پان سے ان کی تواضع کی۔ ولیم فریزر نے یہ بھی بتایا کہ درخواست دہلی ریذیڈنٹ ایڈیٹر کے توسط سے پیش کرنی چاہیے تھی۔ تاہم اس نے درخواست گورنر کے سامنے پیش کرنے کی منظوری دے دی۔ گورنر جنرل نے اس دن دس درخواستیں نمٹانی تھیں۔ غالب کا ان میں آخری اور دسواں نمبر تھا۔
افضل بیگ وکیل نے جوابی دعویٰ پیش کیا اور غالب پر دروغ گوئی اور مکاری کا الزام عائد کیا کہ موقع کی مناسبت سے یہ شخص اپنا نام بدلتا رہتا ہے کبھی نوشہ، کبھی اسد، کبھی غالب اور کبھی نام کے ساتھ بیگ اور خان بھی لکھتا ہے۔ گویا غالب کی افتاد طبع کو ان کی دھوکا دہی اور نوسر بازی کا نام دے دیا گیا۔ گورنر جنرل نے غالب کی درخواست یہ کہہ کر مسترد کردی کہ اسے دہلی کے ریذیڈنٹ ایڈیٹر کے توسط سے آنا چاہیے تھا۔ یہ غالب کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ سالوں سے جو بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور تین برسوں سے گھر سے بے گھر مسافر بنے ہوئے تھے، وہ ساری محنت اکارت گئی تھی۔ انھیں بے نیل مرام واپس لوٹنا پڑا۔
پنشن تو بحال نہ ہوئی مگر دلّی واپس جانے کے لیے غالب کو ڈیڑھ ہزار روپوں کی ضرورت تھی۔ گھوڑا وہ پہلے ہی ڈیڑھ سو روپے میں فروخت کرچکے تھے۔ باندے والے دوست محمد علی خان دو مرتبہ دو دو سو روپے بھجوا چکے تھے۔ آگرہ سے والدہ نے 475 روپے بھجوائے۔ غالب نے کلکتہ کے ایک بڑے مہاجن راؤ شیو رام سے بھی ملاقاتیں کیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انھیں کتنا قرض ملا۔ کلکتہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا الٹا قرض کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ غالب کو یہ بھی فکر تھی اب قرض خواہوں کا سامنا کیسے کریں گے۔
وہ اس لیے بھی دلّی جلد لوٹنا چاہتے تھے کہ گورنر جنرل دلّی کے دورے پر آرہے تھے۔ غالب ان سے پہلے پہنچ کر اپنی درخواست ریذیڈنٹ کے ایڈیٹر کے توسط سے انھیں پیش کرنا چاہتے تھے۔ وہ 20 اگست 1829ء کو کلکتہ سے روانہ ہو کر 8 نومبر 1829ء کو دہلی پہنچے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ دہلی پہنچ کر انھیں علم ہوا کہ گورنر جنرل نے بنارس پہنچ کر اپنا ارادہ بدل دیا اور دلی آنے کے بجائے کلکتہ واپس لوٹ گئے۔
1835ء میں نواب شمس الدین کو ولیم فریزر کے قتل کی سزا میں پھانسی ہو گئی اور ان کی جائیداد ضبط ہو گئی۔ موقع غنیمت جان کر غالب نے آگرہ پریزیڈنسی میں ایک اور درخواست بھجوائی کہ مرزا نصر اللہ بیگ کا وارث ہونے کی حیثیت سے اس جائیداد کا ایک حصہ انھیں ملنا چاہیے تاکہ وہ قرض سے نجات پا سکیں۔ گورنر جنرل نے یہ درخواست بھی رد کردی اور یہ فائل ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر غالب نے گورنر جنرل کے توسط سے ہی ایک درخواست لندن میں ملکہ وکٹوریہ کو بھیجی جس کا جواب کبھی نہیں آیا۔ مرزا غالب نے 1823ء سے 1860ء تک تقریباً 37 برس تک پنشن میں اضافے کے لیے مسلسل جدوجہد کی مگر انھیں کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ ان کا یہ شعر ان پر صادق آتا ہے۔
یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا
اگر اور جیتے رہتے، یہی انتظار ہوتا
(آسٹریلیا میں مقیم افسانہ نگار، کالم نویس اور متعدد کتابوں کے مصنّف طارق مرزا کی تحریر)