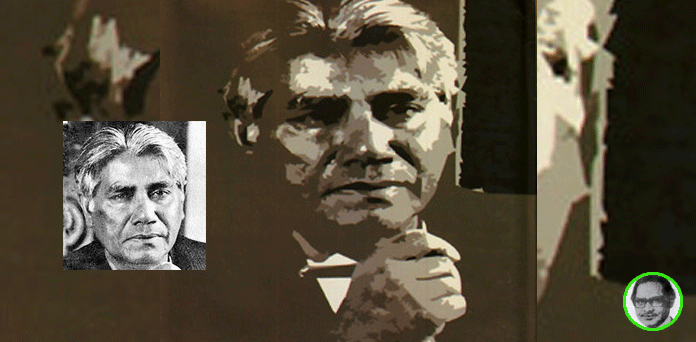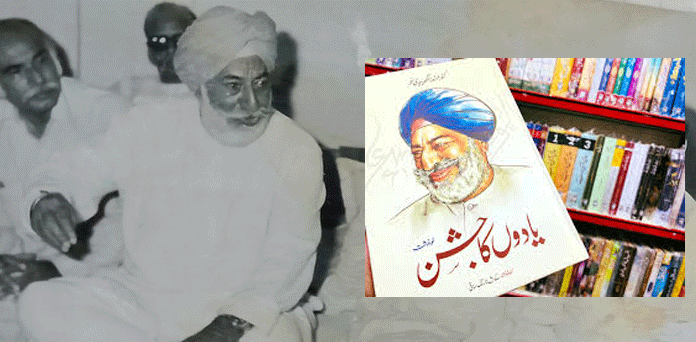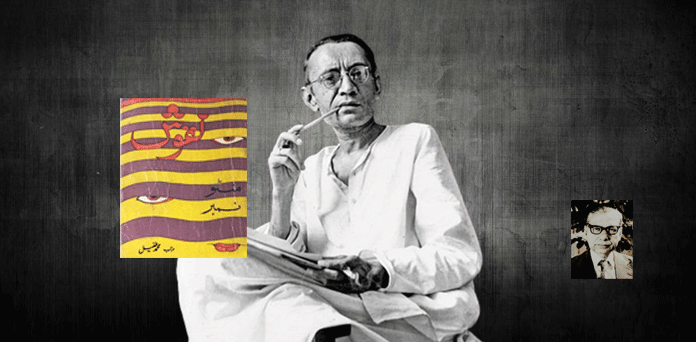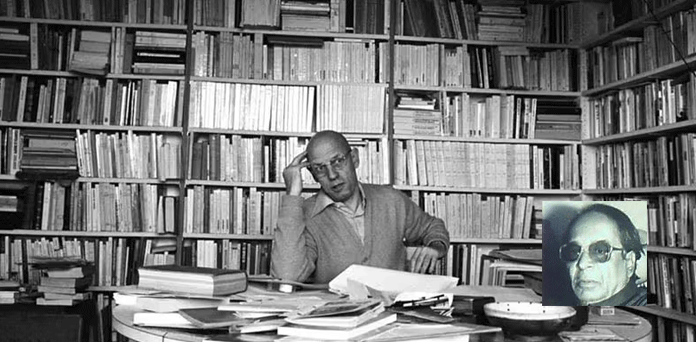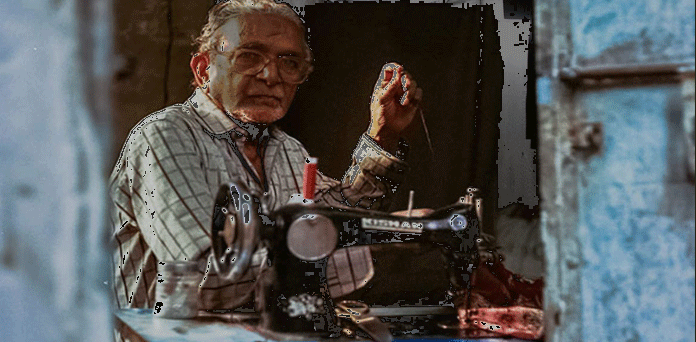برادرم! السلام علیکم
مجھے یہاں آئے ہوئے ساڑھے تین مہینے گزر چکے ہیں، لیکن میں تمہیں خیریت کا خط تک نہ لکھ سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماحول میرے لئے نیا تھا۔ بہرحال اس ماحول سے یقیناً بہتر ہے جس میں، مَیں نے 42 برس تک جھک ماری تھی۔
وہاں جب تک رہا، سولی پر لٹکتا رہا۔ جب سے یہاں آیا ہوں، نہ صفیہ نے مجھ سے کوئی فرمائش کی ہے اور نہ ہی نگہت، نزہت اور نصرت میں سے کسی نے، ورنہ اکثر یہ ہوتا تھا:
ابا فلاں چیز لا دو ، فلاں چیز لا دو۔
تمہیں تو علم ہے کہ مجھے اپنی بچیوں سے بے انتہا محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی فرمائش اپنی تنگدستی کی بنا پر پوری نہ کر پاتا تھا تو خون کے آنسو رویا کرتا تھا۔ حتی کہ بعض منحوس سال ایسے بھی آئے تھے کہ بچی کی سالگرہ تھی اور جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں۔ ایسے ماحول میں، مَیں کب تک رہ سکتا تھا؟ قدرت تو مجھے ایسے انسان کش ماحول میں اور رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن میں نے خود ایسے وسائل اختیار کر لئے تھے کہ آپ کے جہنم زار سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔
میں جب تک وہاں رہا، آپ لوگوں ہی کے غموں میں گھلتا رہا۔ نہ صرف گھلتا رہا بلکہ آہستہ آہستہ معدوم ہی ہو رہا تھا۔ میں بھی تمہارے دکھوں اور غموں کو اس لئے رقم کر آیا ہوں تاکہ آنے والی نسلیں تم سب کو مظلوم کی حیثیت سے یاد رکھ سکیں۔
میں یہاں ہر وقت یہی دعا کیا کرتا ہوں کہ یہ زندگی میرے تمام ہمعصر افسانہ نگاروں کو جلد نصیب ہو۔ اس لیے کہ وہاں پر رہ کر میں نے جیسی ان کی زندگی بسر ہوتے دیکھی تھی، وہ تو مجھ سے بھی بدتر تھی۔ جب مجھی کو وہاں سے آنا پڑا تو نہ جانے وہ کیوں ٹکے ہوئے ہیں؟ آپ کے تمام لکھنے والوں سے تعلقات ہیں، جو لاہور میں موجود ہیں۔ ان سے زبانی کہہ دیں، جو لاہور سے باہر ہیں، انہیں بذریعہ خط مطلع کر دیں کہ وہ سب کے سب بیوی بچوں سمیت میرے پاس آ جائیں۔ میں نے یہاں تمام ابتدائی معاملات طے کر لئے ہیں۔ اس لئے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔
زمانے نے نہ میری قدر کی اور نہ دوسرے اہلِ قلم کی۔ تمہیں علم ہے؟ اگر ہم لوگ تمہارے ہاں نہ ہوتے تو سوائے علم، ادب اور آرٹ کے، سب کچھ ہوتا۔ یہاں جو بھی پہنچ گیا ہے، مزے میں ہے۔ اکثر قلم کاروں سے ملاقات رہتی ہے۔ سب میری ہی طرح پھولے بیٹھے ہیں۔ بعض نے تو تمہارے نمائش آباد کی شان میں ایسی ایسی ہجویات سپردِ قلم کی ہیں کہ جب تک کلیجہ کو دونوں ہاتھوں سے نہ تھام لیا جائے سنی ہی نہیں جا سکتیں۔ اگر وہ چھپ گئیں تو تمہارے ہاں کے بعض سر پھرے سرِ بازار پٹیں گے۔ بہرحال ہجویات کا وہ مجموعہ جب بھی شائع ہوا ، تمہیں اس کا ایک نسخہ ضرور بھیجوں گا۔ نقوش میں اس کا تبصرہ کر دینا۔
تمہارے ہاں کے ادیب اور تمہارے پڑوسی ملک کے ادیب اپنے اپنے نا خداؤں سے جو بڑی خوشگوار قسم کی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں، وہ سراسر حماقت ہے۔ ان خوشگوار قسم کی امیدوں کے پیٹ میں تو صرف بہن خوش فہمی لمبی تانے سو رہی ہے۔ تمہارے ہاں کی سیاست تو بڑی دھڑن تختہ قسم کی ہے۔ آج کوئی وزیر ہے تو کل جیل میں ہے۔ اگر کوئی چند دن پہلے جیل میں تھا اور ساتھ ہی غدارِ وطن بھی، تو آناً فاناً وزیر ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میرے احباب جب تمہارے ہاں کی سیاست کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو یقین جاننا میں مارے شرم کے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔
تمہیں علم ہے کہ مجھ پر آپ کے ہاں پانچ مقدمے صرف فحاشی کے جرم میں چلے تھے۔ حالانکہ میں نے کوئی فحش تحریر نہیں لکھی تھی۔ اس ضمن میں مجھ پر کیا کیا ستم نہیں ڈھائے گئے تھے۔ کبھی وارنٹ نکلے، کبھی گرفتار ہوا، کبھی دوستوں سے ادھار مانگ کر جرمانہ ادا کیا۔ اس کے باوجود میں نے "انصاف زندہ باد” کا نعرہ لگایا تھا۔ اگر میں کچھ دن اور وہاں رہ جاتا تو بہت ممکن تھا، مجھ پر قتل، ڈاکہ زنی، اور زنا بالجبر کے جھوٹے مقدمے بنا دیے جاتے۔ جہاں ناکردہ گناہوں کی سزا ملتی ہو، وہاں کون مسخرہ رہے۔
اگر حکومت کے عتاب سے بچ جائیں تو نقاد پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ساری عمر نقادوں سے دور بھاگا ہوں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ بعض نقاد بھی مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ وہ ہیں جو بگڑے ہوئے افسانہ نویس اور بگڑے ہوئے شاعر ہوتے ہیں یہ لوگ جب تخلیق کی قوت سے محروم ہوتے ہیں، تو تنقید میں علامہ بن جاتے ہیں۔ مجھے ان سب سے خدا واسطے کا بیر رہا ہے۔ اس لئے کہ جب یہ قلم ہاتھ میں لے کر بیٹھتے ہیں تو اچھی بھلی چیز میں سو سو عیب نکالتے ہیں۔ لیکن ان حضرات کو اپنی تحریر کے عیوب کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ خدا کے لئے مجھے ان بے تحاشا لکھے پڑھوں سے بچانا۔ ایسا نہ ہو کہ میرے موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اپنے قلم کو تیز کر لیں اور میرے فن کی دوشیزگی کا جھٹکا کر دیں۔
آج ادب جبھی ترقی کرے گا کہ جو نقاد کہے۔ اس کا الٹا کیا جائے، نقادوں کا منشا بھی یہی ہوتا ہے، لیکن اسے میرے سوا سمجھا کوئی نہیں ہے۔
کاش مجھے یہاں کوئی نقاد مل جائے تاکہ میں اس سے تنقیدی بحث کر سکوں۔ تنقیدی بحث کرتے ہوئے اگر کسی نے ان تینوں لفظوں کا صحیح استعمال کر لیا تو سمجھ لیجئے بازی لے گیا۔ وہ تین الفاظ یہ ہیں: اگر، مگر اور لیکن۔
جب تک نقاد تخلیق کی قوتوں سے مالا مال نہ ہوں گے۔ ان کی تحریروں میں نہ توازن پیدا ہوگا اور نہ واقعیت کے ساتھ خلوص۔ جب فن کار کے دل کے ساتھ نقاد کا بھی دل دھڑکے گا تو پھر جو کچھ لکھا جائے گا، اس پر ایمان لانا ہی پڑے گا۔
یہاں شرابِ طہور عام ہے، پانی نہ پیجئے۔ شرابِ طہور نوش کر لیجئے۔ تمہارے ہاں تو بڑی تھرڈ کلاس قسم کی شراب ملتی تھی اور اس جگر پاش شراب کے لئے بھی مجھے کیا کیا جتن نہیں کرنے پڑتے تھے۔ بعض اوقات اس نامراد کے لئے ذلیل تک ہوا، دوستوں میں میری عزت نہ رہی۔ جدھر جاتا تھا، احباب منہ موڑ لیتے تھے۔ راستہ تک چھوڑ کر انجان بن جاتے تھے۔ اگر کسی سے مڈبھیڑ ہو جاتی تو وہ میرے منہ پر جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا کہ میری جیب میں دھیلا تک نہیں ہے۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس کی جیب میں دھیلا چھوڑ اتنے روپے ہیں کہ وہ مجھے اس خانہ خراب کی کئی بوتلیں خرید کر دے سکتا ہے۔ میں نے شراب کو خانہ خراب اس لئے کہا ہے کہ اس کی بنا پر کئی بار خانہ میں خرابی پید اہوئی تھی۔
ایک بڑی خطرناک مگر راز کی بات کہتا ہوں، اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، ورنہ پٹو گے، یہاں جتنی لڑکیاں ہیں وہ سب ہزاروں برس پرانی ہیں۔ لیکن ان کمبختوں کا جسم اور بانکپن تقدس توڑ ہے۔ اس مسئلہ پر تم سے بات کرنا قطعی حماقت ہے۔ اس لئے کہ تم اس مسئلے میں نرے چغد واقع ہوئے ہو۔ تمہاری چغدیت کا احترام کرنے کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ان سب میں ایسی پروقار کشش اور سپردگی سی پائی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں کی لڑکیاں ان کے سامنے بالکل بکواس ہیں۔
یہاں ایسے ایسے جمال آور لڑکے بھی ہیں کہ تمہارے ہاں کا کوئی شاعر اور ادیب دیکھ لے تو اس کمبخت کے بے ہوش ہونے کے قطعی امکانات موجود ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ جانبر ہی نہ ہوسکے۔
میں ساری عمر ادبی تخلیقات کے سلسلے میں اپنے ہم عصروں سے شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ اس لئے بھی کہ میرے مقابلہ ہی کا کون تھا؟ لیکن یہاں آیا تو غالب نے بڑا پریشان کیا، بڑا پھبتی باز ہے۔ کہنے لگا: تُو تو میرا چور ہے۔ میرے شعروں سے تو نے اپنے افسانوں کے عنوان چنے۔ کتابوں کے نام تک جب نہ سوجھے تو میرے شعروں کو دھر رگڑا اور محسن کشی ایسی کی کہ میرے بارے میں جو فلمی کہانی لکھی، اس میں بجائے میری شکر گزاری کے اظہار کے میری کسی خوبی کا ذکر تک نہیں کیا۔ بلکہ الٹی میری کمزوریاں گنوا کے رکھ دیں کہ میں بڑا وہ تھا، عورت باز تھا، جوا کھیلتا تھا، اور اس کی پاداش میں جیل تک ہو گئی تھی۔ وغیرہ وغیرہ
تمہیں علم ہے کہ میں تمام لکھنے والوں میں صرف غالب ہی کو تو مانتا تھا۔ جب اس نے بھی مجھ سے ایسی ایسی باتیں کیں تو میں نے دل میں کہا: لعنت ہو سعادت حسن منٹو تمہاری حقیقت نگاری پر۔ لیکن غالب ہے بڑا زندہ دل قسم کا انسان، میری اتنی زیادتی کے باوجود گاڑھی چھنتی ہے۔ ہم اکثر ایک ساتھ پیتے ہیں، اور پیتے ہی میں جب ہم حقیقت آشنا ہو جاتے ہیں اور ہماری انا بیدار ہوتی ہے تو غالب کہتا ہے: میں تم سے بڑا افسانہ نگار ہو سکتا تھا۔ لیکن میں نے اسے فضول چیز سمجھ کر ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا۔
اور میں اس سے کہتا ہوں: شعر کہنا کون سا کمال ہے مرزا صاحب، میری تو نثر کی ہر ہر سطر میں ایک شعر کیا پوری غزل کی غزل پنہاں ہوتی ہے۔
بات دونوں کی غلط ہے، اس کا علم اسے بھی ہے اور مجھے بھی۔ لیکن ہم اپنی اپنی انا کا کیا کریں۔
چچا سام کا دبدبہ تو تمہارے ہاں دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، مبارک ہو!
بڑوں کی عزت ضرور کرنی چاہئے۔ لیکن سعادت مندی کے معنی یہ بالکل نہیں ہیں کہ تم اپنی ننھی سی جان بھی خطرے میں ڈال دو۔ میں نے یہ خبر بد بھی سنی ہے کہ اب تو تمہارے ہاں کا سارا کا سارا کام وہی کرتے ہیں۔ اور تم سب الوؤں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے اندھیرے کے منتظر ہو۔ اتنی تن آسانی اچھی نہیں، ورنہ پچھتاؤ گے۔ حتی کہ تم لوگوں نے اپنی خودداری تک کو قفل لگا کے الماریوں میں رکھ دیا ہے۔
مصیبت یہ ہے کہ میں یہاں سے چچا سام کے نام کوئی خط نہیں لکھ سکتا۔ ورنہ میں اس سے اپنی حدود میں رہنے کی درخواست ضرور کرتا۔ دعا کرو کہ وہ خود ہی میرے پاس جلد سے جلد آجائیں تاکہ تمہاری جان چھوٹے، میں تو ان سے نمٹ ہی لوں گا۔ فراڈ کو فراڈ ہی پچھاڑ سکتا ہے۔
میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب سے یہاں آیا ہوں، تمہارے ہاں میرا بڑا سوگ منایا گیا۔ خدا کی قسم، یہ سنتے ہی میرا دل کباب ہو گیا۔ اس لئے کہ جب تک میں وہاں رہا، سب نے مل جل کر مجھے اپنے ہاں سے دور کرنا چاہا۔ جب یہاں کچھ دوسروں کی اور کچھ اپنی مرضی سے آ گیا ہوں۔ تو ریڈیو پر اس ناچیز کی گمشدگی کے اعلانات کیوں کیے جاتے ہیں۔ یہ وہی ریڈیو والے ہیں جو مجھے اپنے ہاں ناک تک صاف نہیں کرنے دیتے تھے۔ رسالے اور اخبارات بھی میرے روپوش ہونے پر خصوصی ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا بھی میرے ساتھ یوسف کے بھائیوں جیسا سلوک تھا۔ ان حالات میں تمہیں اپنے اس منافقانہ رویہ پر شرم آنی چاہئے۔
یہاں میرے کچھ قدر دان پیدا ہو گئے ہیں۔ اور پچھلے دنوں انہوں نے میرے ذمہ یہ کام کیا تھا کہ میں یہاں کے بارے میں اپنی سہ ماہی رپورٹ پیش کروں۔ یہ فریضہ میرے سپرد اس لئے ہوا تھا کہ ان کے خیال کے مطابق مجھ جیسا حقیقت نگار یہاں کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اس میں اپنے ایک دوست کی خوب ڈٹ کر مخالفت بھی کی ہے۔ اور اس کا جو معاشقہ اندر ہی اندر چل رہا تھا، اس کا بھی کچا چٹھا لکھ دیا ہے۔
حتی کہ میں نے رپورٹ میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہاں جو داڑھی نہ منڈوانے کا دستور ہے وہ بعض نستعلیق قسم کی طبیعتوں پر گراں گزرتا ہے۔ اس لئے اس کی اجازت ہونی چاہئے کہ جس کا دل چاہے داڑھی رکھے جس کا دل نہ چاہے نہ رکھے۔
اتنے بڑے حاکم کے سامنے اتنا کہہ دینا اور کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کرنا، خالہ جی کا گھر نہ تھا، تمہارے ہاں ایسی کوئی کھری بات کہہ دیتا تو میری زبان گدی سے نکلوا دی جاتی۔
اطلاعاً عرض ہے۔ یہاں میری کتاب "گنجے فرشتے” کافی پسند کی گئی ہے۔ ہو سکے تو میری بیوی بچّوں کا خیال رکھنا۔
خاکسار
سعادت حسن منٹو
20/اپریل 1955ء
(منٹو کی وفات کے تین ماہ بعد اردو کے مشہور جریدے نقوش کے منٹو نمبر میں محمد طفیل نے منٹو کا فرضی خط بنام مدیر نقوش شایع کیا تھا)