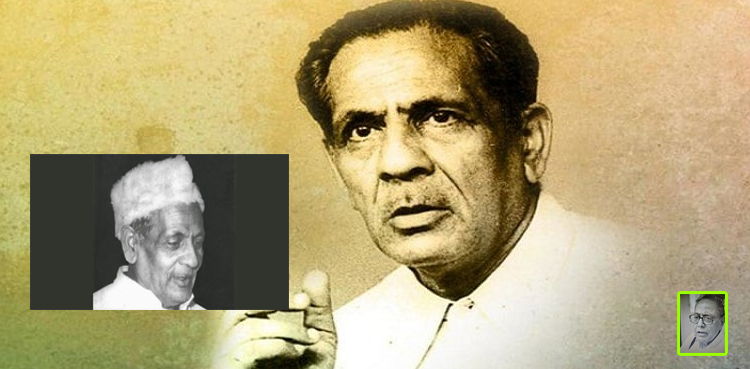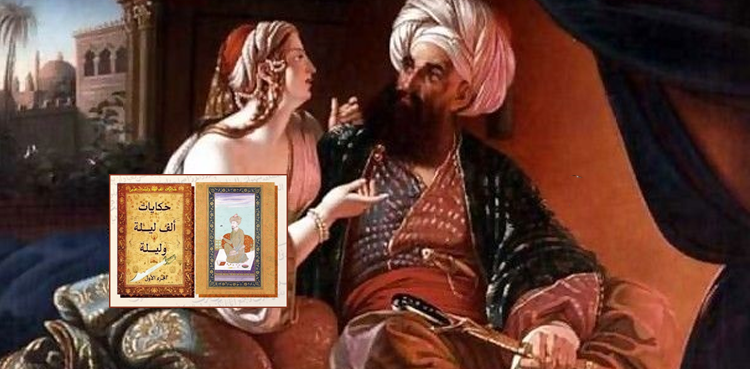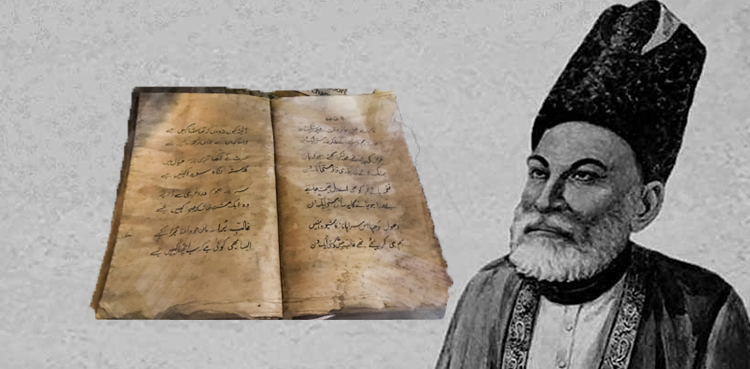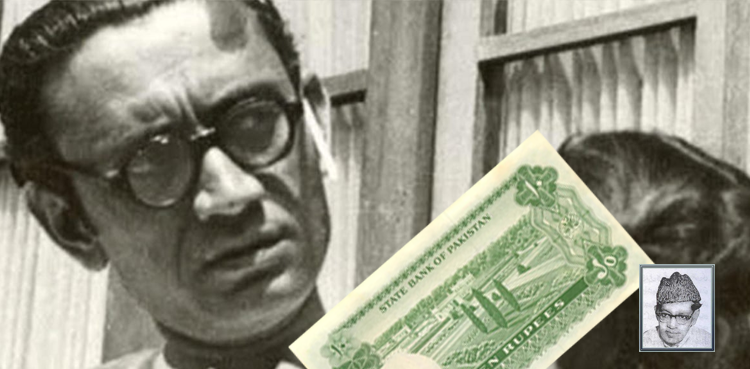پنجاب یونیورسٹی چنڈی گڑھ کے پوسٹ گریجویٹ ڈیپارٹمنٹ آف انگلش میں میرے رفقائے کار میں ڈاکٹر مسز نرمل مکرجی بھی تھیں، جو امریکا کی کسی یونیورسٹی سے انگریزی کے ہندوستانی ناول نویس آر کے ناراین پر ڈاکٹریٹ کر کے لوٹی تھیں۔
ان سے معلوم ہوا کہ الٰہ آباد میں وہ فراق گورکھپوری کی انڈر گریجویٹ کلاس میں تھیں اور ان سے ذاتی طور پر انس رکھتی تھیں۔ میں چونکہ شعبۂ انگریزی کی لٹریری سوسائٹی The Three Hundred کا پروفیسر انچارج تھا، میں نے انہیں اس بات پر راضی کر لیا کہ اب کے جب وہ اپنے والدین سے ملنے الٰہ آباد جائیں تو فراق گورکھپوری صاحب کو راضی کریں کہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک توسیعی لیکچر دینے کے لیے تشریف لائیں۔ ہم ٹرین سے فرسٹ کلاس کا کرایہ اور دیگر متعلقہ اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے، ان کی رہائش کا گیسٹ ہاؤس میں بندوبست ہو گا۔اور میں ذاتی طور پر ایک چپراسی کو ان کی خدمت کے لیے ہر وقت ان کے پاس حاضر رہنے کا انتظام کر دوں گا، اور ان کے آرام کا خیال رکھنے کے لیے خود بھی موجود رہوں گا۔
فراق گورکھپوری آئے۔ آڈیٹوریم میں ان کی تقریر نے جیسے ہم سب کو مسحور کر لیا۔ شستہ انگریزی لہجہ، اس پر ہر پانچ چھ جملوں کے بعد اردو سے (موضوع سے متعلق) ایک دو اشعار، اور پھر انگریزی میں گل افشانی۔ یہ تجربہ ہم سب کے لیے نیا تھا، کیونکہ ہم تو کلاس روم میں صرف (اور صرف) انگریزی ہی بولتے تھے۔ ایک گھنٹہ بولنے کے بعد تھک گئے۔ میں چونکہ اسٹیج پر تھا اور مجھے بطور شاعر جانتے تھے، مجھے کہا کہ جب تک وہ تھرموس سے ’’پانی‘‘ پی کر سانس لیں گے، میں کچھ سناؤں۔
میں نے اپنی ایک نظم انگریزی میں اور ایک اردو میں سنائی۔ تین چار گھونٹ ’’پانی‘‘ پینے اور دس پندرہ منٹ تک آرام کرنے کے بعد پھر تازہ دَم ہو گئے۔ ایک بار پھر چالیس پنتالیس منٹوں تک بولے۔ کیا اساتذہ اور کیا طلبہ، سبھی مسحور بیٹھے تھے، کسی کو خیال ہی نہ آیا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے۔ تب کلائی کی گھڑی کی طرف دیکھا اور کہا، ’’بھائی، کوئی کھانا وانا بھی ملے گا کہ نہیں!‘‘ اور تب طلبہ کو بھی خیال آیا کہ انہیں ہوسٹل کے میس میں کھانے کے لیے پہنچنا ہے، جس کا وقت گزر چکا ہے۔
شام کو میں گیسٹ ہاؤس پہنچا تو انتظار ہی کر رہے تھے۔ میں وہسکی کی ایک بوتل اپنے اسکوٹر کے بیگ میں رکھ کر لایا تھا اور باورچی خانے میں سوڈے کی بوتلیں پہلے ہی لا کر رکھ دی گئی تھیں۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر راج کمار بھی آ گئے۔ خاموش طبع انسان تھے اور بہت کم پیتے تھے، اس لیے گفتگو کا فرض ہم دونوں نے ہی ادا کیا۔ میں مودبانہ انداز سے ، لیکن کوئی چبھتی ہوئی بات کہہ دیتا اور پھر ان کے منہ سے گل افشانی شروع ہو جاتی۔
ایک موضوع جو زیرِ بحث آیا اور جس میں مراتب کا خیال رکھے بغیر میں نے کھل کر بحث کی، وہ شعرا کے لیے ایک آفاقی موضوع کے طور پر ’’عشق‘‘ تھا۔ فارسی اور اردو کے حوالے سے بات شروع ہوئی اور فراق صاحب نے کہا کہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے، جس میں دنیائے قدیم سے آج تک یہ موضوع اوّل و آخر نہ رہا ہو۔ ’’شعرا کے لیے تو التمش و اولیات سے لے کر آخرت اور عاقبت تک عشق ہی عشق ہے۔‘‘ انہوں نے اردو اور فارسی سے درجنوں مثالیں گنوانی شروع کر دیں تو میں نے ’’عذر مستی‘‘ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کیا کہ ہم تینوں انگریزی کے اساتذہ یہ جانتے ہیں کہ یورپ کی سب زبانوں کے قدیم ادب میں’’ عشق ‘‘ کی وہ pre-eminent position نہیں، جس کا دعویٰ آپ فرما رہے ہیں۔ ہومرؔ کا موضوع ہیلنؔ کا اغوا نہیں ہے، حالانکہ سمجھا یہی جاتا ہے، بلکہ دیوتاؤں کے دو الگ الگ فرضی گروپوں ، مسئلہ جبر و قدر کے عمل اور ردِّعمل کی نقاشی ہے۔ دو تمدنوں کے بیچ کا سنگھرش ہے۔ دانتےؔ کا موضوع بھی عشق نہیں ہے (جنس تو بالکل نہیں ہے، جیسے کہ فارسی ادب میں امرد پرستی کے حوالے سے ہے)۔ دانتےؔ کے بارے میں یہ سوچنا غلط ہے کہ چونکہ ’’ بیاترچےؔ ‘‘ جنت میں اسے راہ دکھاتی ہے، اس لیے تانیثی حوالہ فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے وہ اپنے تصور میں آگ کی بھٹّیوں میں ’’پاولوؔ ‘‘ اور ’’فرانچسکاؔ ‘‘ کو حالتِ جماع میں دیکھتا ہے کہ یہ ظاہر ہو کہ جنسی آزاد روی دوزخ کا پیش خیمہ ہے۔
فراق جیسے حالتِ استغراق میں مبہوت سے بیٹھے میری طرف دیکھتے رہے۔ تب میں نے کہا کہ شیکسپیئر نے اتنی بڑی تعداد میں ڈرامے لکھے لیکن ان میں صرف تین ایسے ہیں جنہیں کھینچ تان کر عشق کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ ’’انتھونی اینڈ کلیوپیٹرا‘‘، ’’رومیو اینڈ جولیٹ‘‘، تو یقیناً مرد اور عورت کے عشق کے موضوع پر ہیں، لیکن ’’اوتھیلو‘‘ عشق کے علاوہ رنگ و نسل اور ازدواجی زندگی کے بارے میں بھی ہے۔ اس سے پیچھے جائیں تو چودھویں صدی میں ہمیں ’’داستان‘‘ کے زمرے میں چاسرؔ کا طویل بکھان ملتا ہے، جس میں عشق سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے زمان وسطیٰ کی تخلیق Beowolf ہے، اس کا بھی عشق سے براہِ راست کوئی تعلق نہیں، تو انگریزی ادب کی شروعات تو عشق کے الوہی یا جنسی مسائل سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ لواطت تو خیر، …..میں کچھ کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ فراق چونکے۔ بوتل سے وہسکی انڈیل کر میرا گلاس پوری طرح بھر دیا اور بولے، ’’انگریز سالے تو نا مرد ہیں، لیکن آپ درست کہتے ہیں، فارسی کے حوالے سے جو اردو کی مائی باپ ہے، البتہ اوّل و آخر عشق صحیح ہے کہ نہیں؟‘‘ میں نے عرض کیا، ’’جی ہاں، صحیح ہے۔‘‘
خوش ہو گئے۔ فرمایا، ’’کبھی الٰہ آباد آئیں تو غریب خانے پر بھی تشریف لائیں۔
(بھارتی ادیب، شاعر اور نقّاد ستیہ پال آنند کے قلم سے)