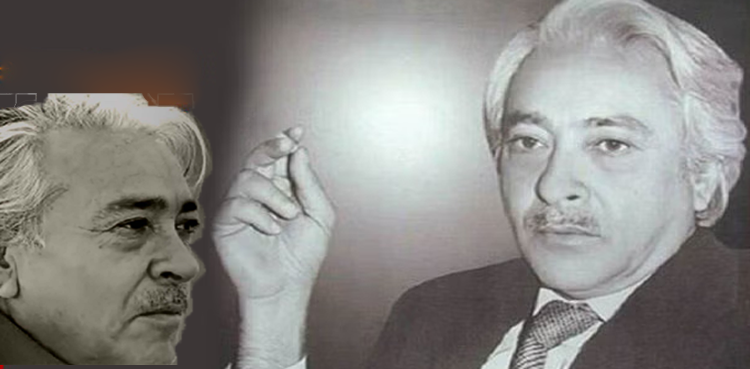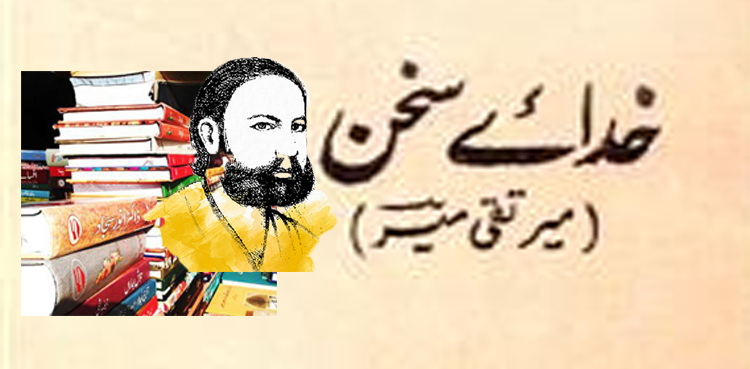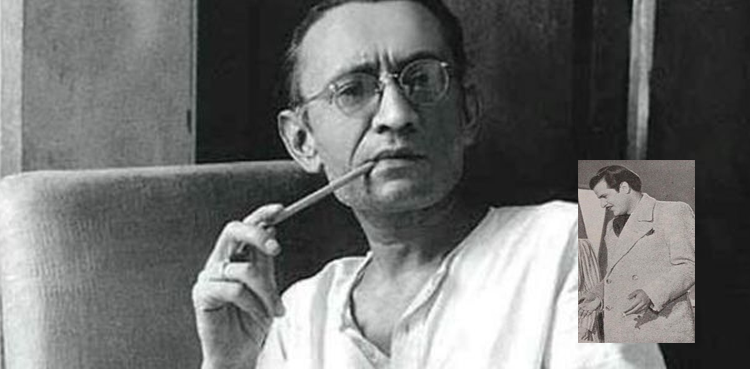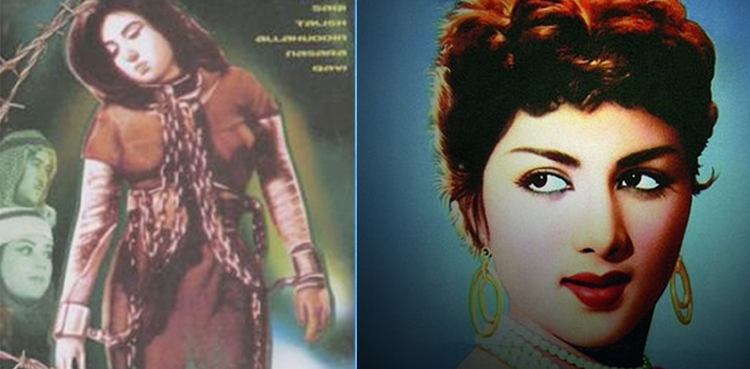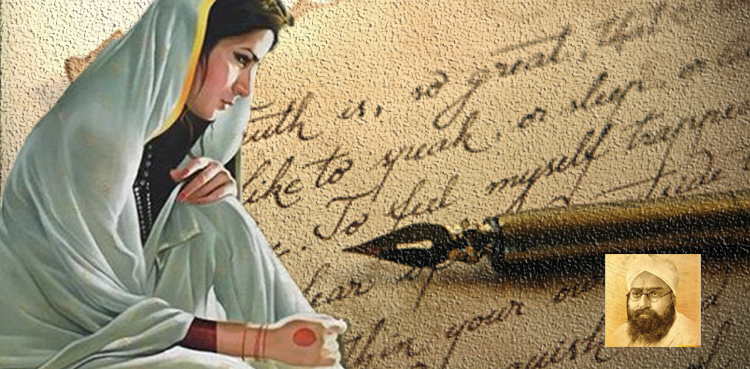منیر نیازی کی شاعری ایک طلسم خانۂ حیرت ہے۔ اردو زبان کے اس ممتاز شاعر کا کلام ایک خواب ناک ماحول کو جنم دیتا ہے جو قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ منیر نیازی کے طرزِ بیان اور شعری اسلوب نے اردو شاعری پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ آج منیر نیازی کی برسی ہے۔
اردو ادب میں منیر نیازی کو اپنے عہد کا بڑا شاعر مانا جاتا ہے جس نے کسی کلاسیکی روایت کا تعاقب نہیں کیا اور ان کی شاعری کسی دبستان کے اثر سے مغلوب نہیں بلکہ وہ اپنی شاعری سے ایک نئے دبستان کی طرح ڈالنے والے ایسے شاعر ہیں جس کی تقلید کرنے کی کوشش ان کے بعد آنے والوں نے کی ہے۔
بانو قدسیہ نے کہا تھا، میں منیر نیازی کو صرف بڑا شاعر تصوّر نہیں کرتی، وہ پورا ’’اسکول آف تھاٹ‘‘ ہے جہاں ہیولے، پرچھائیں، دیواریں، اُن کے سامنے آتے جاتے موسم، اور ان میں سرسرانے والی ہوائیں، کھلے دریچے، بند دروازے، اداس گلیاں، گلیوں میں منتظر نگاہیں، اتنا بہت کچھ منیر نیازی کی شاعری میں بولتا، گونجتا اور چپ سادھ لیتا ہے کہ انسان ان کی شاعری میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ منیر کی شاعری حیرت کی شاعری ہے، پڑھنے والا اونگھ ہی نہیں سکتا۔
بیسویں صدی کی آخری نصف دہائی میں منیر نیازی کو ان کی اردو اور پنجابی شاعری کی وجہ سے جو پذیرائی اور مقبولیت ملی، وہ بہت کم شعرا کو نصیب ہوتی ہے۔ ان کی شاعری انجانے اور اچھوتے احساس کے ساتھ ان رویّوں کی عکاسی کرتی ہے جن سے منیر اور ان کے عہد کے ہر انسان کا واسطہ پڑتا ہے۔ منیر نیازی کے کلام کا قاری معانی کی کئی پرتیں اتارتا اور امکانات کی سطحوں کو کریدتا ہوا اس میں گم ہوتا چلا جاتا ہے۔
منیر نیازی نے 19 اپریل 1928ء کو ہوشیار پور کے ایک قصبہ میں آنکھ کھولی۔ وہ پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد محمد فتح خان محکمۂ انہار میں ملازم تھے جو منیر نیازی کی زندگی کے پہلے برس ہی میں انتقال کرگئے تھے۔ منیر نیازی کی والدہ کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا اور ان ہی سے ادبی مذاق منیر نیازی میں منتقل ہوا۔ منیر نے ابتدائی تعلیم منٹگمری (موجودہ ساہیوال) میں حاصل کی اور یہیں سے میٹرک کا امتحان پاس کر کے نیوی میں بطور سیلر ملازم ہو گئے۔ لیکن یہ نوکری ان کے مزاج کے برعکس تھی۔ ملازمت کے دنوں میں بمبئی کے ساحلوں پر اکیلے بیٹھ کر ادبی رسائل پڑھتے تھے جس کا نتیجہ نیوی کی ملازمت سے استعفیٰ کی صورت سامنے آیا۔ انھوں نے لاہور کے دیال سنگھ کالج سے بی۔ اے کیا اور اس زمانہ میں کچھ انگریزی نظمیں بھی لکھیں۔ تعلیم مکمل ہوئی تھی کہ ملک کا بٹوارہ ہو گیا اور ان کا سارا خاندان پاکستان چلا آیا۔ یہاں انھوں نے ایک اشاعتی ادارہ قائم کیا، لیکن یہ اور دوسرے چھوٹے موٹے کاروبار میں ناکام ہونے کے بعد منیر نیازی لاہور چلے گئے۔ وہاں مجید امجد کے ساتھ ایک پرچہ ’’سات رنگ‘‘ جاری کیا اور اسی زمانے میں مختلف اخبارات اور ریڈیو کے لیے بھی کام کیا۔ 1960ء کی دہائی میں منیر نیازی نے فلموں کے لیے گانے بھی لکھے جو بہت مشہور ہوئے۔ فلم ’’شہید‘‘ کے لیے نسیم بانو کی آواز میں ان کا کلام ’’اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو‘‘ بہت پسند کیا گیا، اور نور جہاں کی آواز میں ’’جا اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کے سو جا‘‘ ایک مقبول نغمہ ثابت ہوا۔ اسی طرح 1976 میں ’’خریدار‘‘ کا گیت ’’زندہ رہیں تو کیا ہے جو مر جائیں ہم تو کیا‘‘ ناہید اختر کی آواز میں آج بھی مقبول ہے۔
منیر نیازی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انا پرست تھے اور کسی شاعر کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ قدیم شعراء میں بس میرؔ، غالبؔ اور سراج اورنگ آبادی ان کے پسندیدہ تھے۔ اسی طرح منیر نیازی نے شاعری کی اصناف، غزل اور نظم میں بھی معیار کو بلند رکھا ہے۔ لیکن گیت اور کچھ نثری نظمیں بھی لکھیں۔ منیر نیازی خود پسند ہی نہیں، بلا کے مے نوش بھی تھے اور آخری عمر میں ان کو سانس کی بیماری ہو گئی تھی۔ وہ 26 دسمبر 2006ء کو بیماری کے سبب وفات پاگئے تھے۔
حکومتِ پاکستان نے اردو اور پنجابی زبان کے اس مقبول شاعر کو ’’ستارۂ امتیاز‘‘ اور ’’پرائڈ آف پرفارمنس‘‘ سے نوازا تھا۔
ان کی زندگی میں تنہائی اور آوارگی کے ساتھ رومانس کا بڑا دخل رہا اور وہ خود کہتے تھے کہ زندگی میں درجنوں عشق کیے ہیں۔ وہ ساری عمر شاعری کرتے رہے اور بے فکری کو اپنی طبیعت کا خاصہ بنائے رکھا۔ اپنے ہم عصروں میں نمایاں ہونے والے منیر نیازی لاہور میں حلقۂ اربابِ ذوق کے رکن بنے اور سیکرٹری بھی رہے، لیکن کسی مخصوص گروہ اور ادبی تنظیموں سے کوئی وابستگی اور تعلق نہ رکھا۔ وہ اپنی دھن میں رہنے والے انسان تھے جس کے مزاج نے اسے سب الگ رکھا۔
مجید امجد وہ شاعر تھے جن کے ساتھ رہ کر منیر نیازی کا تخلیقی جوہر کھلنے لگا۔ وہ ایک ساتھ بہت سا وقت گزراتے اور شعر و ادب پر بات کرتے، اور اپنی شاعری ایک دوسرے کو سناتے۔ بقول منیر نیازی دونوں روز ایک نئی نظم لکھ کر لاتے تھے اور ایک دوسرے کو سناتے۔ منیر نیازی کی تخلیقات فنون، اوراق، سویرا، ادب لطیف، معاصر اور شب خون وغیرہ میں شائع ہوتی تھیں۔
منیر نیازی کی شخصیت بھی سحر انگیز تھی۔ وہ ہر محفل میں مرکزِ نگاہ ہوتے۔ ان کے ایک ہم عصر رحیم گل نے ان کی ظاہری شخصیت کا خاکہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔
‘ربع صدی قبل میں ایک نوجوان سے ملا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے سیاہ و سرخ قمیض میں اس کا چہرہ اور زیادہ سرخ نظر آتا تھا۔ اس کے سیاہ بال بانکپن سے اس کی پیشانی پر لہرا رہے تھے نیلگوں بھوری سی دو بڑی شفاف آنکھیں اس کے چہرے پر یوں جھلملا رہی تھیں جیسے سرخ ماربل میں سے دو چشمے ابل پڑے ہوں۔ ستواں ناک مگر نتھنے کچھ زیادہ کشادہ غالباً یہی وجہ تھی کہ اس کی قوتِ شامہ بہت تیز تھی اور وہ فطری طور پر بُوئے گل اور مانس بو کی مکروہات اور خصوصیات پا لیتا تھا۔ پہلی ملاقات میں منیر مجھے اچھا لگا۔’
منیر نیازی کے یہ مشہور اشعار دیکھیے۔
یہ کیسا نشہ ہے میں کس عجب خمار میں ہوں
تو آ کے جا بھی چکا ہے، میں انتظار میں ہوں
غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں
تو نے مجھ کو کھو دیا میں نے تجھے کھویا نہیں
آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے
ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائیگاں تو ہے
مدت کے بعد آج اسے دیکھ کر منیرؔ
اک بار دل تو دھڑکا مگر پھر سنبھل گیا
آنکھوں میں اڑ رہی ہے لٹی محفلوں کی دھول
عبرت سرائے دہر ہے اور ہم ہیں دوستو
اک اور دریا کا سامنا تھا منیرؔ مجھ کو
میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا
اردو میں منیر نیازی کے 13 اور پنجابی کے تین مجموعے شائع ہوئے جن میں اس بے وفا کا شہر، تیز ہوا اور تنہا پھول، جنگل میں دھنک، دشمنوں کے درمیان شام، سفید دن کی ہوا، سیاہ شب کا سمندر، چھ رنگین دروازے، پہلی بات ہی آخری تھی، ایک دعا جو میں بھول گیا تھا، محبت اب نہیں ہوگی، ایک تسلسل اور دیگر شامل ہیں۔
انھوں اپنے دور کے اہلِ قلم اور بالخصوص نقادوں سے ایک محفل میں یہ شکوہ اپنے مخصوص انداز میں کیا تھا کہ ’ایک زمانے میں نقّادوں نے مجھے اپنی بے توجہی سے مارا اور اب اس عمر میں آ کر توجہ سے مار رہے ہیں۔‘