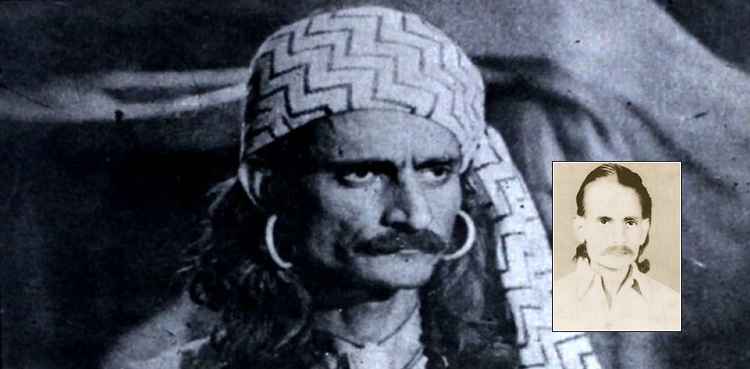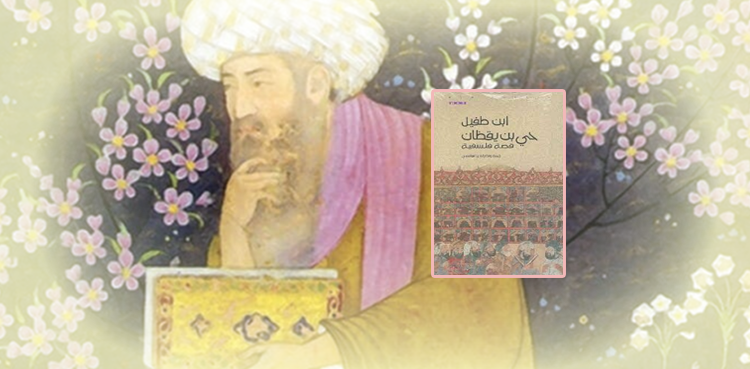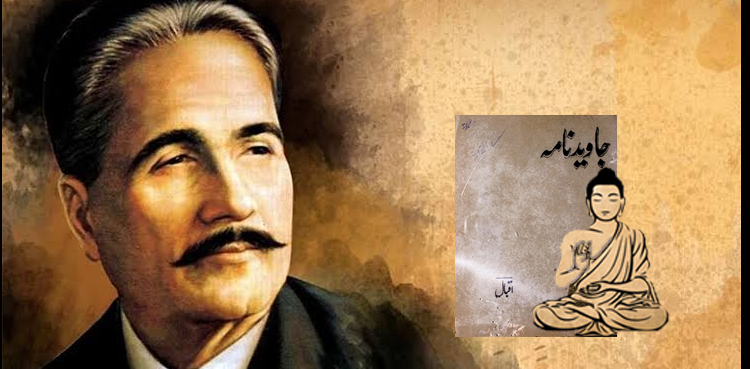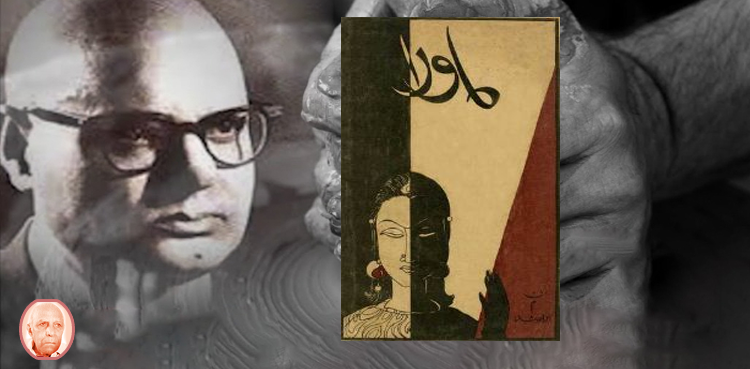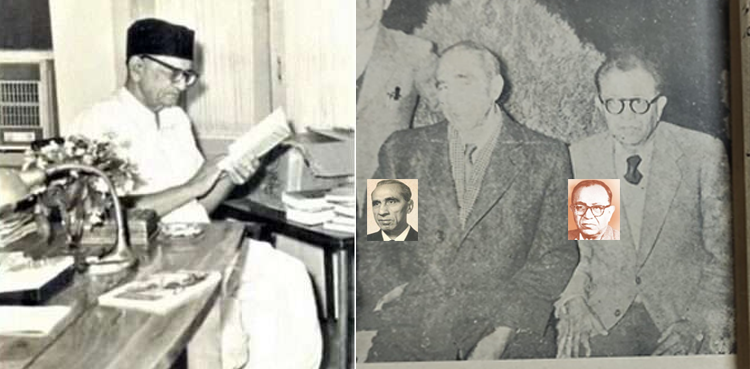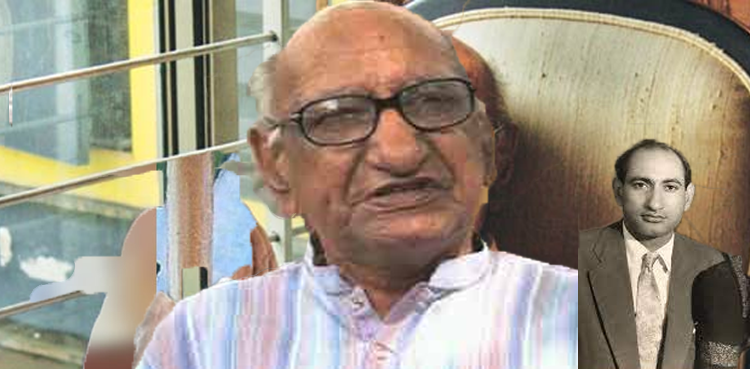منٹو نے "اخلاق باختہ” شاعر میرا جی کو پرلے درجے کا مخلص لکھا ہے۔ اردو نظم کو جدّت اور بہ لحاظِ ہیئت انفرادیت عطا کرنے والے میرا جی اپنے فن و تخلیق کے لیے تو اردو ادب میں زیرِ بحث رہے ہی ہیں، لیکن ان کی شخصیت کے بعض پہلوؤں سے بھی ان کے ہم عصر اہلِ قلم صرفِ نظر نہیں کرسکے اور میرا جی کے ‘اعمالِ بد’ کو بھی ادبی تذکروں اور خاکوں کا حصّہ بنایا ہے۔ آج میرا جی کی برسی ہے۔
مروجّہ سماجی اقدار سے بیزاری اور روایت سے انحراف نے میرا جی کو باغی شاعر بھی ثابت کیا ہے اور مگر ان کی فنی عظمت کا اعتراف سبھی کرتے ہیں اور انھیں بالخصوص اردو نظم کو تنوع اور نئی وسعتوں سے آشنا کرنے والا شاعر کہا جاتا ہے۔ لیکن بحیثیت انسان وہ اپنی آوارہ مزاجی اور ذہنی عیّاشی کے سبب ایسی قبیح عادات میں مبتلا رہے جو ناگفتہ بہ ہیں۔ انھیں جنسی مریض بھی سمجھا گیا، 3 نومبر 1949ء کو میرا جی ممبئی میں وفات پاگئے تھے۔
میرا جی نے زندگی کی صرف 38 بہاریں دیکھیں۔ ان کا اصل نام محمد ثناءُ اللہ ڈار تھا۔ میرا جی 25 مئی 1912ء کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد منشی شہاب الدین ریلوے میں ملازم تھے۔ بسلسلۂ ملازمت ان کا تبادلہ مختلف شہروں میں ہوتا رہا اور میرا جی نے بھی تعلیم مختلف شہروں میں مکمل کی۔ یہ کنبہ لاہور منتقل ہوا تو وہاں میرا سین نامی ایک بنگالی لڑکی ثناء اللہ ڈار کی زندگی میں داخل ہوئی۔ انھوں نے اس کے عشق میں گرفتار ہوکر اپنا نام میرا جی رکھ لیا، لیکن یہ عشق ناکام رہا۔ اس کے بعد میرا جی نے محبّت اور ہوس میں کوئی تمیز نہ کی اور کئی نام نہاد عشق کیے اور رسوائیاں اپنے نام کیں۔ یہ تو ایک طرف، میرا جی نے اپنا حلیہ ایسا بنا لیا تھا کہ نفیس طبیعت پر بڑا گراں گزرتا۔ ادیبوں نے میرا جی پر اپنی تحریروں میں لکھا کہ وہ جسمانی صفائی کا کم ہی خیال رکھتے۔ بڑھے ہوئے گندے بالوں کے علاوہ ان کے لمبے ناخن میل کچیل سے بھرے رہتے اور لباس کا بھی یہی معاملہ تھا۔
علم و ادب کی دنیا سے میرا جی کا تعلق مطالعہ کے شوق کے سبب قائم ہوا تھا۔ میرا جی مغربی ادب کے ذہین اور مشّاق قاری تھے۔ انھوں نے جب اپنی طبیعت کو موزوں پایا تو شاعری کا آغاز کردیا اور پھر ادب سے شغف کی بنیاد پر ایک مشہور رسالہ ادبی دنیا سے منسلک ہوگئے۔ یہاں ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور وہ مضمون نگار بن گئے، ساتھ ہی غیرملکی ادیبوں کی تخلیقات کا اردو ترجمہ بھی کرنے لگے۔ ادبی حلقے سے حوصلہ افزائی نے میرا جی کو طبع زاد تحریروں اور تنقیدی مضامین لکھنے کی طرف راغب کیا اور یوں وہ ادب کی دنیا میں نام و مقام بناتے چلے گئے۔ میرا جی نے قدیم یونانی اور سنسکرت شعرا کے علاوہ بے حد مشکل علامت پسند فرانسیسی شعرا کے بھی کامیابی سے تراجم کیے۔ عمر خیام کی رباعیات کو انھوں نے بڑے سلیقے سے ہندوستانی چولا پہنایا۔
یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستانی برطانیہ سے آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس دوران برّصغیر کے جملہ طبقات اور ہر شعبے میں نمایاں تبدیلیاں دیکھنے میں آرہی تھیں اور اردو ادب بھی نئے رجحانات اور ترقی پسند تحریک سے متاثر ہورہا تھا۔ اسی دور میں میرا جی نے حلقۂ اربابِ ذوق میں دل چسپی لینا شروع کی اور آگے چل کر جدید نظم کے بانیوں میں ان کا شمار ہوا۔ ظفر سیّد نے بی بی سی پر اپنی ایک تحریر میں میرا جی کے لیے لکھا تھا، وہ نام جس نے اردو میں جدیدیت کی داغ بیل ڈالی۔ جس نے کہنہ روایات کی برف کو توڑ کر راستا بنایا، جس نے جدید شاعروں کی ایک نسل کی آبیاری کی۔ یہ میرا جی ہیں، وہ میرا جی جو راشد سے زیادہ رواں، مجید امجد سے زیادہ جدید اور فیض سے زیادہ متنوع ہیں۔
ڈاکٹر انور سدید میرا جی کے بارے میں لکھتے ہیں، اربابِ ذوق کو میرا جی کی ذات میں وہ شخصیت میسر آگئی جو بکھرے ہوئے اجزا کو مجتمع کرنے اور انھیں ایک مخصوص جہت میں گام زن کرنے کا سلیقہ رکھتی تھی۔ میراجی ذہنی اعتبار سے مغرب کے جدید علوم کی طرف راغب تھے لیکن ان کی فکری جڑیں قدیم ہندوستان میں پیوست تھیں۔ مشرق اور مغرب کے اس دل چسپ امتزاج نے ان کی شخصیت کے گرد ایک پراسرار جال سا بُن دیا تھا۔ چنانچہ ان کے قریب آنے والا ان کے سحر مطالعہ میں گرفتار ہوجاتا اور پھر ساری عمر اس سے نکلنے کی راہ نہ پاتا۔ دور سے دیکھنے والے ان کی ظاہری ہیئت کذائی، بے ترتیبی اور آزادہ روی پر حیرت زدہ ہوتے اور پھر ہمیشہ حیرت زدہ رہتے۔
وہ مزید لکھتے ہیں، میرا جی کی عظمت کا ایک باعث یہ بھی تھا کہ وہ حلقے کے ارکان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑے تھے۔ ان کا ادبی ذوق پختہ اور مطالعہ وسیع تھا اور حلقے میں آنے سے پہلے وہ والٹ وٹمن، بودلیئر، میلارمے، لارنس، چنڈی داس، ودیاپتی اورامارو وغیرہ کے مطالعے کے بعد ادبی دنیا میں ان شعرا پر تنقیدی مضامین کا سلسلہ شروع کرچکے تھے۔
1941ء میں میرا جی کو ریڈیو اسٹیشن لاہور میں ملازمت مل گئی۔ اس کے اگلے سال ان کا تبادلہ دہلی ریڈیو اسٹیشن پر ہو گیا۔ اسی دوران انھوں نے فلموں میں قسمت آزمانا چاہی، لیکن ناکام رہے اور بعد میں اختر الایمان نے انھیں اپنے رسالے خیال کی ادارت سونپ دی۔
اردو کے اس ممتاز شاعر نے اپنی نظموں میں زبان و بیان کے جو تجربے کیے اور جس ذوقِ شعر کی ترویج کی کوشش کی اس نے اک ایسے شعری اسلوب کی بنیاد رکھی جس میں امکانات پنہاں تھے۔ اردو شاعری میں میرا جی کی اہمیت ایک خاص طرزِ احساس کے علاوہ ہیئت کے تجربوں کی وجہ سے ہے۔ ان کی شاعری کا ایک پہلو وہ بھی ہے جسے اشاریت اور ابہام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
نظموں اور غزلوں کے علاوہ میرا جی نے فلمی گیت نگاری بھی کی اور ان کے تنقیدی مضامین بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کی چند کتابوں کے نام یہ ہیں:
”مشرق و مغرب کے نغمے“ ، ”اس نظم میں “، ”نگار خانہ“، ”خیمے کے آس پاس“ جب کہ میرا جی کی نظمیں، گیت ہی گیت، پابند نظمیں اور تین رنگ شعری مجموعے ہیں۔
اردو کے ممتاز افسانہ نگار سعادت حسن منٹو نے میرا جی کے بارے میں لکھا تھا، بحیثیت انسان کے وہ بڑا دل چسپ تھا۔ پرلے درجے کا مخلص، جس کو اپنی اس قریب قریب نایاب صفت کا مطلقاً احساس نہیں تھا۔ میرا جی نے شاعری کی، بڑے خلوص کے ساتھ، شراب پی بڑے خلوص کے ساتھ، بھنگ پی، وہ بھی بڑے خلوص کے ساتھ، لوگوں سے دوستی کی، اور اسے نبھایا۔
یہاں ہم اردو کے جدید اردو نظم کے بانی اور مشہور شاعر میرا جی کی ایک غزل باذوق قارئین کے مطالعے کے لیے نقل کررہے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔
نگری نگری پھرا مسافر، گھر کا رستا بھول گیا
کیا ہے تیرا، کیا ہے میرا، اپنا پرایا بھول گیا
کیا بھولا، کیسے بھولا، کیوں پوچھتے ہو بس یوں سمجھو
کارن دوش نہیں ہے کوئی بھولا بھالا بھول گیا
کیسے دن تھے، کیسی راتیں، کیسی باتیں، گھاتیں تھیں
من بالک ہے پہلے پیار کا سندر سپنا بھول گیا
اندھیارے سے ایک کرن نے جھانک کے دیکھا شرمائی
دھندلی چھب تو یاد رہی، کیسا تھا چہرہ بھول گیا
ایک نظر کی ایک ہی پل کی بات ہے ڈوری سانسوں کی
ایک نظر کا نور مٹا جب اک پل بیتا بھول گیا
سوجھ بوجھ کی بات نہیں ہے من موجی ہے مستانہ
لہر لہر سے جا سر پٹکا ساگر گہرا بھول گیا