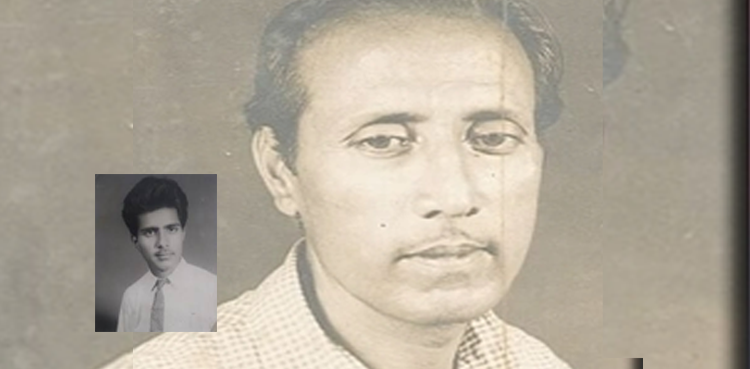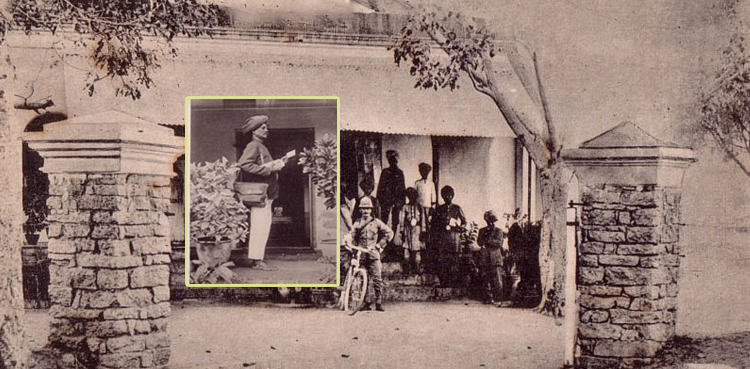اردو ادب میں میاں بیوی کے تعلق پر مزاح نگاروں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اردو ہی نہیں عالمی ادب میں بھی شادی شدہ مردوں کے بارے میں ایسی ہی مزاحیہ تحریریں پڑھنے کو ملتی ہیں جن میں انھیں خاتونِ خانہ کے آگے بے بس اور مجبور بتایا جاتا ہے۔
یہ پطرس بخاری کی ایک ایسی ہی تحریر ہے جس میں انھوں نے خود کو ایک ایسے خاوند کے طور پر پیش کیا ہے جو اپنی بیوی کے غصّے اور ناراضی سے ڈرتا ہے اور اس کی ہر بات مانتا ہے۔ وہ خاص طور پر اپنے دوستوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے کیوں کہ بیوی کی نظر میں اس کے دوست نکھٹو، احمق اور کام چور ہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس کا خاوند بھی انہی کی عادات اپنا رہا ہے۔ پطرس کے اس شگفتہ مضمون سے یہ اقتباسات ملاحظہ کیجیے۔
شادی سے پہلے ہم کبھی کبھی دس بجے اٹھا کرتے تھے ورنہ گیارہ بجے۔
اب کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جن کے گھر ناشتہ زبردستی صبح کے سات بجے کرا دیا جاتا ہے اور اگر ہم کبھی بشری کمزوری کے تقاضے سے مرغوں کی طرح تڑکے اُٹھنے میں کوتاہی کریں تو فوراً ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس نکھٹو نسیم کی صحبت کا نتیجہ ہے۔
ایک دن صبح صبح ہم نہا رہے تھے۔ سردی کا موسم، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ صابن سر پر ملتے تھے تو ناک میں گھستا تھا کہ اتنے میں ہم نے خدا جانے کس پُراسرار جذبے کے ماتحت غسل خانے میں الاپنا شروع کیا اور پھر گانے لگے کہ ’’توری چھل بل ہے نیاری۔۔۔‘‘ اس کو ہماری انتہائی بدمذاقی سمجھا گیا اور اس بدمذاقی کا اصل منبع ہمارے دوست پنڈت جی کو ٹھہرایا گیا۔
لیکن حال ہی میں مجھ پر ایک ایسا سانحہ گزرا ہے کہ میں نے تمام دوستوں کو ترک کر دینے کی قسم کھالی ہے۔ تین چار دن کا ذکر ہے کہ صبح کے وقت روشن آرا نے مجھ سے میکے جانے کے لیے اجازت مانگی۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے روشن آرا صرف دو دفعہ میکے گئی ہے، اور پھر اس نے کچھ اس سادگی اور عجز سے کہا کہ میں انکار نہ کرسکا۔
کہنے لگی، ’’تو پھر میں ڈیڑھ بجے کی گاڑی میں چلی جاؤں؟‘‘
’’میں نے کہا، اور کیا؟‘‘ وہ جھٹ تیاری میں مشغول ہوگئی اور میرے دماغ میں آزادی کے خیالات نے چکر لگانے شروع کیے۔ یعنی اب بیشک دوست آئیں، بیشک اودھم مچائیں۔ میں بے شک گاؤں، بے شک جب چاہوں اٹھوں۔ بے شک تھیٹر جاؤں۔ میں نے کہا، ’’روشن آرا جلدی کرو۔ نہیں تو گاڑی چھوٹ جائے گی۔‘‘
ساتھ اسٹیشن پر گیا۔ جب گاڑی میں سوار کرا چکا تو کہنے لگی، ’’خط روز لکھتے رہیے۔‘‘
’’میں نے کہا، ہر روز اور تم بھی۔‘‘
’’کھانا وقت پہ کھا لیا کیجیے اور ہاں دھلی ہوئی جرابیں اور رومال الماری کے نچلے خانے میں پڑے ہیں۔‘‘ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہوگئے اور ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرا دل بھی بیتاب ہونے لگا اور جب گاڑی روانہ ہوئی تو میں دیر تک مبہوت پلیٹ فارم پر کھڑا رہا۔
آخر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کتابوں کی دکان تک آیا اور رسالوں کے ورق پلٹ پلٹ کر تصویریں دیکھتا رہا۔ ایک اخبار خریدا۔ تہہ کرکے جیب میں ڈالا اور عادت کے مطابق گھر کا ارادہ کر لیا۔ پھر خیال آیا کہ اب گھر جانا ضروری نہیں رہا۔ اب جہاں چاہوں جاؤں، چاہوں تو گھنٹوں اسٹیشن پر ہی ٹہلتا رہوں۔ دل چاہتا تھا قلابازیاں کھاؤں۔
کہتے ہیں جب افریقہ کے وحشیوں کو کسی تہذیب یافتہ ملک میں کچھ عرصہ کے لیے رکھا جاتا ہے تو گو وہ وہاں کی شان و شوکت سے بہت متاثر ہوتے ہیں لیکن جب واپس جنگلوں میں پہنچتے ہیں تو خوشی کے مارے چیخیں مارتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی کیفیت میرے دل کی بھی ہو رہی تھی۔ بھاگتا ہوا اسٹیشن سے آزادانہ باہر نکلا۔ آزادی کے لہجہ میں تانگے والے کو بلایا اور کود کر تانگے میں سوار ہوگیا۔ سگریٹ سلگا لیا، ٹانگیں سیٹ پر پھیلا دیں اور کلب کو روانہ ہوگیا۔
رستے میں ایک بہت ضروری کام یاد آگیا۔ تانگہ موڑ کر گھر کی طرف پلٹا۔ باہر ہی سے نوکر کو آوازد دی۔
’’امجد!‘‘
’’حضور!‘‘
’’دیکھو، حجام کو جاکے کہہ دو کہ کل گیارہ بجے آئے۔‘‘
’’بہت اچھا۔‘‘
’’گیارہ بجے سن لیا نا؟ کہیں روز کی طرح پھر چھے بجے وارد نہ ہو جائے۔‘‘
’’بہت اچھا حضور۔‘‘
’’اور اگر گیارہ بجے سے پہلے آئے تو دھکے دے کر باہر نکال دو۔‘‘ یہاں سے کلب پہنچے۔ آج تک کبھی دن کے دو بجے کلب نہ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو سنسان، آدمی کا نام و نشان تک نہیں۔ سب کمرے دیکھ ڈالے۔ بلیرڈ کا کمرہ خالی، شطرنج کا کمرہ خالی، تاش کا کمرہ خالی۔ صرف کھانے کے کمرے میں ایک ملازم چھریاں تیز کر رہا تھا۔
اس سے پوچھا، ’’کیوں بے آج کوئی نہیں آيا؟‘‘ کہنے لگا، ’’حضور آپ جانتے ہیں، اس وقت بھلا کون آتا ہے؟‘‘ بہت مایوس ہوا۔ باہر نکل کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں؟ اور کچھ نہ سوجھا تو وہاں سے مرزا صاحب کے گھر پہنچا۔ معلوم ہوا ابھی دفتر سے واپس نہیں آئے۔ دفتر پہنچا۔ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میں نے سب حال بیان کیا۔
کہنے لگے،’’ تم باہر کے کمرے میں ٹھہرو، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ بس ابھی بھگتا کے تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کا پروگرام کیا ہے؟‘‘
میں نے کہا، ’’تھیٹر۔‘‘
کہنے لگے، ’’بس بہت ٹھیک ہے، تم باہر بیٹھو۔ میں ابھی آیا۔‘‘
باہر کے کمرے میں ایک چھوٹی سی کرسی پڑی تھی۔ اس پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا اور جیب سے اخبار نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع سے آخر تک سب پڑھ ڈالا اور ابھی چار بجنے میں ایک گھنٹہ باقی تھا۔ پھر سے پڑھنا شروع کر دیا۔ سب اشتہار پڑھ ڈالے اور پھر سب اشتہاروں کو دوبارہ پڑھ ڈالا۔
آخر کار اخبار پھینک کر بغیر کسی تکلف یا لحاظ کے جمائیاں لینے لگا، جمائی پہ جمائی۔ جمائی پہ جمائی، حتٰی کہ جبڑوں میں درد ہونے لگا۔ اس کے بعد ٹانگیں ہلانا شروع کیا لیکن اس سے بھی تھک گیا۔ پھر میز پر طبلے کی گتیں بجاتا رہا۔ بہت تنگ آگیا تو دروازہ کھول کر مرزا سے کہا،
’’ابے یار اب چلتا بھی ہے کہ مجھے انتظار ہی میں مار ڈالے گا۔ مردود کہیں کا، سارا دن میرا ضائع کر دیا۔‘‘
وہاں سے اُٹھ کر مرزا کے گھر گئے۔ شام بڑے لطف میں کٹی۔ کھانا کلب میں کھایا اور وہاں سے دوستوں کو ساتھ ليے تھیٹر گئے۔ رات کے ڈھائی بجے گھر لوٹے۔ تکیے پر سر رکھا ہی تھا کہ نیند نے بے ہوش کر دیا۔
صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ لہریں مار رہی تھی۔ گھڑی کو دیکھا تو پونے گیارہ بجے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر میز پر سے ایک سگریٹ اٹھایا اور سلگا کر طشتری میں رکھ دیا اور پھر اونگھنے لگا۔
گیارہ بجے امجد کمرے میں داخل ہوا کہنے لگا، ’’حضور حجام آیا ہے۔‘‘
ہم نے کہا، ’’یہیں بلا لاؤ۔‘‘ یہ عیش مدت کے بعد نصیب ہوا کہ بستر پر لیٹے لیٹے حجامت بنوا لیں۔ اطمینان سے اٹھے اور نہا دھو کر باہر جانے کے ليے تیار ہوئے لیکن طبیعت میں وہ شگفتگی نہ تھی، جس کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ چلتے وقت الماری سے رومال نکالا تو خدا جانے کیا خیال آیا۔ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا اور سودائیوں کی طرح اس رومال کو تکتا رہا۔ الماری کا ایک اور خانہ کھولا تو سرمئی رنگ کا ایک ریشمی دوپٹہ نظر آیا۔ باہر نکالا، ہلکی ہلکی عطر کی خوشبو آرہی تھی۔ بہت دیر تک اس پر ہاتھ پھیرتا رہا دل بھر آیا، گھر سُونا معلوم ہونے لگا۔ بہتیرا اپنے آپ کو سنبھالا لیکن آنسو ٹپک ہی پڑے۔ آنسوؤں کا گرنا تھا کہ بیتاب ہوگیا اور سچ مچ رونے لگا۔ سب جوڑے باری باری نکال کر دیکھے لیکن نہ معلوم کیا کیا یاد آیا کہ اور بھی بےقرار ہوتا گیا۔ آخر نہ رہا گیا، باہر نکلا اور سیدھا تار گھر پہنچا۔ وہاں سے تار دیا کہ، ’’میں بہت اداس ہوں۔ تم فوراً آجاؤ!‘‘
تار دینے کے بعد دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ یقین تھا کہ روشن آرا اب جس قدر جلد ہوسکے گا آجائے گی۔ اس سے کچھ ڈھارس بندھ گئی اور دل پر سے جیسے ایک بوجھ ہٹ گیا۔
دوسرے دن دوپہر کو مرزا کے مکان پر تاش کا معرکہ گرم ہونا تھا۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ مرزا کے والد سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں۔ اس ليے تجویز یہ ٹھہری کہ یہاں سے کسی اور جگہ سرک چلو۔ ہمارا مکان تو خالی تھا ہی۔ سب یار لوگ وہیں جمع ہوئے۔ امجد سے کہہ دیا گیا کہ حقے میں اگر ذرا بھی خلل واقع ہوا تو تمہاری خیر نہیں اور پان اس طرح سے متواتر پہنچتے رہیں کہ بس تانتا لگ جائے۔
اب اس کے بعد کے واقعات کو کچھ مرد ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ شروع شروع میں تو تاش باقاعدہ اور باضابطہ ہوتا رہا۔ جو کھیل بھی کھیلا گیا بہت معقول طریقے سے، قواعد و ضوابط کے مطابق اور متانت و سنجیدگی کے ساتھ لیکن ایک دو گھنٹے کے بعد کچھ خوش طبعی شروع ہوئی۔ یار لوگوں نے ایک دوسرے کے پتے دیکھنے شروع کر دیے۔ یہ حالت تھی کہ آنکھ بچی نہیں اور ایک آدھ کام کا پتہ اُڑا نہیں اور ساتھ ہی قہقہے پر قہقہے اُڑنے لگے۔
تین گھنٹے کے بعد یہ حالت تھی کہ کوئی گھٹنا ہلا ہلا کر گا رہا ہے، کوئی فرش پر بازو ٹیکے بجا رہا ہے۔ کوئی تھیٹر کا ایک آدھ مذاقیہ فقرہ لاکھوں دفعہ دہرا رہا ہے لیکن تاش برابر ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دھول دھپا شروع ہوگیا۔ ان خوش فعلیوں کے دوران میں ایک مسخرے نے ایک ایسا کھیل تجویز کردیا۔ جس کے آخر میں ایک آدمی بادشاہ بن جاتا ہے۔ دوسرا وزیر، تیسرا کوتوال اور جو سب سے ہار جائے وہ چور۔ سب نے کہا ’’واہ وا کیا بات کہی ہے۔‘‘
ایک بولا، ’’پھر آج جو چور بنا اس کی شامت آجائے گی۔‘‘
دوسرے نے کہا، ’’اور نہیں تو کیا۔ بھلا کوئی ایسا ویسا کھیل ہے۔ سلطنتوں کے معاملے ہیں، سلطنتوں کے۔‘‘
کھیل شروع ہوا۔ بدقسمتی سے ہم چور بن گئے۔ طرح طرح کی سزائیں تجویز ہونے لگیں۔‘‘ کوئی کہے، ’’ننگے پاؤں بھاگتا ہوا جائے اور حلوائی کی دکان سے مٹھائی خرید کر لائے۔ کوئی کہے، ’’نہیں حضور! سب کے پاؤں پڑے، اور ہر ایک سے دو دو چانٹے کھائے۔‘‘ دوسرے نے کہا، ’’نہیں صاحب ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر ہمارے سامنے ناچے۔‘‘
آخر میں بادشاہ سلامت بولے،’’ہم حکم دیتے ہیں کہ چور کو کاغذ کی ایک لمبوتری نوک دار ٹوپی پہنائی جائے اوراس کے چہرے پر سیاہی مل دی جائے اور یہ اسی حالت میں جاکر اندر سے حقے کی چلم بھر کر لائے۔‘‘
سب نے کہا۔ ’’کیا دماغ پایا ہے حضور نے! کیا سزا تجویز کی ہے! واہ وا‘‘
ہم بھی مزے میں آئے ہوئے تھے، ہم نے کہا، ’’تو ہوا کیا؟ آج ہم ہیں کل کسی اور کی باری آجائے گی۔‘‘
نہایت خندہ پیشانی سے اپنے چہرے کو پیش کیا۔ ہنس ہنس کر وہ بیہودہ سی ٹوپی پہنی۔ ایک شانِ استغنا کے ساتھ چلم اٹھائی اور زنانے کا دروازہ کھول کر باورچی خانے کو چل دیے اور ہمارے پیچھے کمرہ قہقہوں سے گونج رہا تھا۔
صحن میں پہنچے ہی تھے کہ باہر کا دروازہ کھلا اور ایک برقعہ پوش خاتون اندر داخل ہوئی۔ منہ سے برقعہ الٹا تو روشن آرا۔
دم خشک ہوگیا۔ بدن پر ایک لرزہ سا طاری ہوگیا۔ زبان بند ہو گئی۔ سامنے وہ روشن آرا جس کو میں نے تار دے کر بلایا تھا کہ، ’’تم فوراً آجاؤ میں بہت اداس ہوں۔‘‘ اور اپنی یہ حالت کہ منہ پر سیاہی ملی ہے، سر پر وہ لمبوتری سی کاغذ کی ٹوپی پہن رکھی ہے اور ہاتھ میں چلم اٹھائے کھڑے ہیں اور مردانے کمرے سے قہقہوں کا شور برابر آرہا ہے۔ روح منجمد ہوگئی اور تمام حواس نے جواب دے دیا۔ روشن آرا کچھ دیر تک چپکی کھڑی دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی۔۔۔ بس میں کیا بتاؤں کہ کیا کہنے لگی؟ اس کی آواز تو میرے کانوں تک جیسے بیہوشی کے عالم میں پہنچ رہی تھی۔
اب تک آپ اتنا تو جان گئے ہوں گے کہ میں بذاتِ خود از حد شریف واقع ہوا ہوں۔ جہاں تک میں میں ہوں۔ مجھ سے بہتر میاں دنیا پیدا نہیں کرسکتی۔ میری سسرال میں سب کی یہی رائے ہے اور میرا اپنا ایمان بھی یہی ہے لیکن ان دوستوں نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ اس ليے میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ اب یا گھر میں رہوں گا یا کام پر جایا کروں گا۔ نہ کسی سے ملوں گا اور نہ کسی کو اپنے گھر آنے دوں گا، سوائے ڈاکیے یا حجام کے اور ان سے بھی نہایت مختصر باتیں کروں گا۔
’’خط ہے؟‘‘
’’جی ہاں۔‘‘
’’دے جاؤ۔ چلے جاؤ۔‘‘
’’ناخن تراش دو۔‘‘
’’بھاگ جاؤ۔‘‘
بس، اس سے زیادہ کلام نہ کروں گا۔ آپ دیکھیے تو سہی!