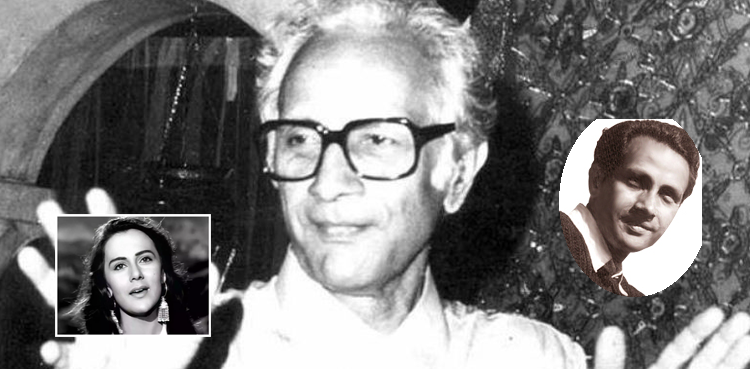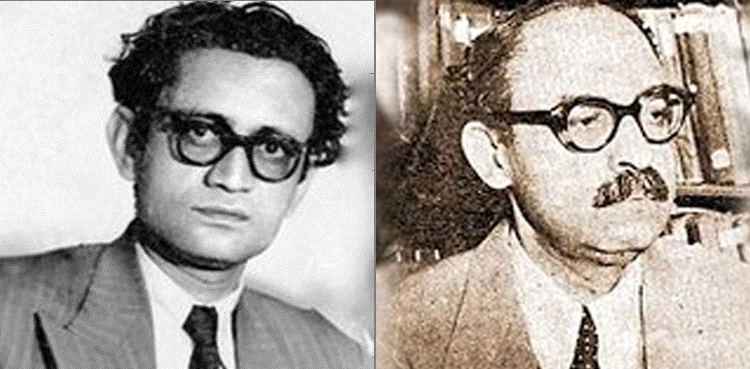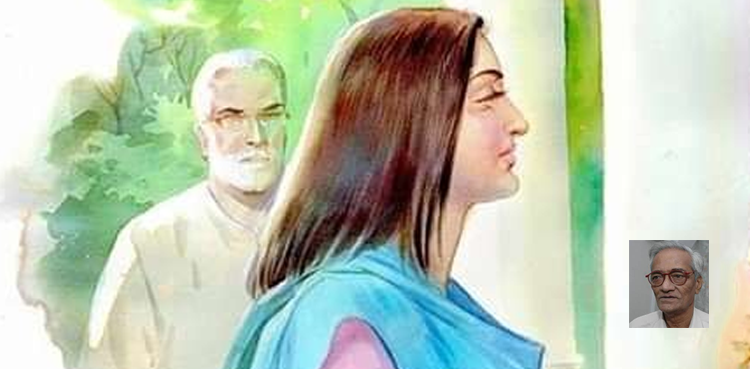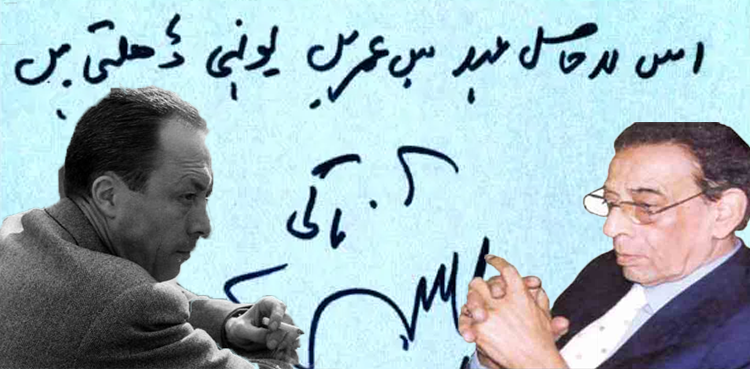ساس:: خادم بیٹا یہ کیسا شور ہے اور فائرنگ کی آوازیں کیسی ہیں؟
خادم:: امّی حضور! پریشان نہ ہوں کبیر صاحب کے ہاں پانچ بکرے اور دو بیل آئے ہیں۔ اس خوشی میں فائرنگ ہو رہی ہے۔“
ساس:: ہاں بھئی خوشی کا موقع ہے، خادم بیٹا! تم کب لا رہے ہو جانور؟
خادم:: امی حضور میں تو روز جاتا ہوں۔ جانوروں کے دام میرے ہوش اڑا دیتے ہیں۔ جانور اتنا مہنگا ہے معلوم نہیں خرید بھی پاؤں گا کہ نہیں؟
بہو:: آپ کے ہوش کا کیا ٹھکانہ خادم! وہ تو سستی اشیاء دیکھ کر بھی اڑ جاتے ہیں، اب لے ہی آئیں، ہاں اس بار تگڑا بکرا لائیے گا، دو سال سے ایسا کمزور جانور آرہا ہے کہ میرے میکے والو ں کا حصہ تو لگتا ہی نہیں، اس دفعہ پنکی کو ران بھی ضرور جائے گی۔
ساس:: کیوں بھئی پنکی کے لیے ران اتنی لازمی کیوں ہے؟ ایک ران میری رانی کو جائے گی اور دوسری میں خود رکھوں گی، رانی کے سسرال والوں کی دعوت میں بھون کر کھلاؤں گی۔
بہو:: ایک رانی اور ایک پنکی کو چلی جائے گی۔ ہو سکے تو دو بکرے لے آئیے گا، دو رانیں گھر میں رکھ لیں گے اس سے جھگڑا بھی نہیں ہوگا اور انصاف سے سب کا حصہ بھی لگ جائے گا۔“
بیٹا:: یہاں تو ایک ہی کے لالے پڑ رہے ہیں بیگم صاحبہ نے دو کی فرمائش کردی۔
ساس:: ہاں بھئی بڑی دیالو ہیں تمہاری بیگم۔ منہ دھو رکھو ملکہ، تمہارے میکے میں گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں جائے گا اور پَر کٹی پنکی کے لیے تو میں ہرگزنہ مانوں۔“
بیٹا:: ملکہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے امی اور پھر رانی کی شادی کو دس سال ہو گئے۔ ران ہر سال رانی ہی کو جاتی ہے، پنکی کی شادی کو تو ابھی دو سال ہی ہوئے ہیں، دو بکرے آگئے تو ایک ران پنکی کو بھی چلی جائے گی۔ ملکہ تم دل چھوٹا نہ کرو، دعا کرو دو بکرے مل جائیں تو بہن اور سالی دونوں کا حق ادا کر دوں گا۔“
ساس:: بک بک بند کر، بس چُپ کر
بیٹا:: ابھی تو میں جانور لینے گیا تک نہیں اور شروع ہو گیا ساس بہو کا سالانہ جھگڑا۔ میں منڈی جارہا ہوں۔
٭٭٭
ساس:: سات گھنٹے ہو چلے ہیں خادم کو گئے ابھی تک نہیں آیا اور بہو! تم کیا کھاتہ کھول کر بیٹھ گئیں؟
بہو:: رش بھی تو بہت ہوتا ہے۔ آجائیں گے، پریشان نہ ہوں، ہاں میں فہرست بنا رہی ہوں گوشت کے حصوں کی۔“
ساس:: میں بھی تو سنوں کیا فہرست بنا رہی ہو؟
بہو:: ایک ران پنکی کی۔
ساس:: ہرگز نہیں، اللہ رکھے ایک ہی تو میری بیٹی ہے وہ بھی تمہاری نظروں میں خار بن کر کھٹکتی ہے۔
بہو:: میری بھی ایک ہی بہن ہے جس کا نام آتے ہی آپ انگارے چبانے لگتی ہیں۔
ساس:: کیوں نہ چباؤں انگارے وہ کلموہی میری بچّی کا حق مارے، میں کچھ نہ کہوں۔ تم اگر ملکہ ہو بہو بیگم تو میں بھی نواب بیگم ہوں، تم سیر ہو تو میں سوا سیر۔“
بیٹا:: ساس بہو میں کیا تکرار ہو رہی ہے؟ یہ لیجیے آ گیا ہمارا بکرا۔
ساس:: جیتے رہو بیٹا، کیسا پیارا صحت مند بکرا لائے ہو، پھٹکری دینا بیٹا نظر اتار دوں۔ نظر نہ لگ جائے کہیں میرے پیارے بکرے کو۔
بہو:: نظر بعد میں اتروائیے گا خادم، پہلے میری سن لیجیے، اس بار ران میری پنکی کو ضرور جائے گی اور پائے امی کے گھر جائیں گے۔ میرے سارے بہن بھائی بھرپور گوشت بھیجتے ہیں اور میں بیچاری۔“
ساس:: ہاں ہاں تم بیچاری، درد کی ماری، ارے سب سمجھتی ہوں تمہارے چلتر پن کو، کچا گوشت بیشک میکے نہیں بھیجتیں لیکن گوشت پکا کرخوب بھر بھر میکے والوں کی دعوتیں جو کرتی ہو اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، مجھ سے پوچھتی تک نہیں کہ
بتا اماں، تیری رضا کیا ہے
غضب خدا کا میرے بیٹے کی خون پسینے کی کمائی اپنے میکے والوں پر ایسے لٹاتی ہے جیسے اس پر ان ہی کا تو حق ہے۔ سن لو ملکہ عالیہ پائے تو میں رانی کے سسرال والوں کی دعوت میں پکاؤں گی۔ ایک ران میری رانی کو جائے گی اور دوسری کا ران روسٹ بناؤں گی۔
بہو:: اور میں نے بھی کہہ دیا پنکی سسرال میں نئی ہے۔ ران اگر پرانی بیاہی رانی کو جائے گی تو میری پنکی کو بھی جائے گی۔
ساس:: کیسے جاتی ہے پنکی کو ران؟ میں بھی دیکھتی ہوں، انھیں خیال نہ آیا کہ میں اپنی ملکہ آپا کے لیے ران بھیج دوں، اتنا بڑا بیل آیا تھا، ایسی کنجوس کے لیے تو میں ہرگز نہ مانوں۔
بہو:: ران ہی تو نہیں بھیجی تھی پنکی نے، گوشت کیسا بھرپور بھیجا تھا میری بہن نے، دیکھ کر پانی بھر آیا تھا آپ کے منہ میں، سب یاد ہے مجھے آپ کی فرمائشیں، جیسے ہی گوشت آیا، آپ کی رال ٹپکنے لگی تھی، اے بہو! اس کی تو بریانی پکا لینا، خاص بریانی کا گوشت ہے، جب میں نے بریانی پکائی تو ڈکار پر ڈکار لے رہی تھیں لیکن کھانے سے ہاتھ نہیں کھینچ رہی تھیں، ہڈیاں تک اچھی طرح سے سوتی تھیں۔ آپ کا تو وہ حال تھا ”جان جائے خرابی سے ہاتھ نہ رکے رکابی سے۔“
ساس:: ہاں بہو کم ظرفی دکھاؤ، یہی ہے تمہاری اوقات۔ دو نوالے کیا کھا لیے اس کو اتنا بڑھاوا دے رہی ہو۔ سن رہے ہو خادم، اپنی بیگم کی گز بھر کی زبان کیسے ماں کی بے عزتی کر رہی ہے اور تم منہ بند کیے بیٹھے ہو زن مرید، پَر کٹی پنکی کے لیے تو میں ہرگز نہ مانوں چاہے آج زمین آسمان ایک کر دے۔“
بہو:: میں بھی کسی سے کم نہیں۔ ایک ران پنکی کو ضرور جائے گی، مما پپا ہمیشہ پنکی کے نام کی ایک ران الگ رکھتے ہیں۔“
ساس:: تو کہو اپنے اماں باوا سے نبھائیں اپنی روایت۔ ایک کیا چار رانیں بھیجیں پنکی کو۔ دس سال تو تمہاری شادی کو ہوگئے، آج تک ایک ران بھی نہ بھیجی اماں باوا نے تمہارے واسطے۔ وہ پنکی بیگم کہاں کی نواب زادی ہیں جن کے لیے ایک ران لازمی ہے۔
بہو:: نواب زادی تو آپ کی رانی ہے مہا رانی، دختر نواب بیگم۔ خادم کیوں منہ بند کیے بیٹھے ہیں کچھ تو کہیے۔
ساس:: ”ہاں بیٹا تم بھی ساز چھیڑ دو تم کیوں خاموش ہو۔“
خادم:: کروں تو کیا کروں اور کہوں تو کیا کہوں؟ میں غریب۔
ساس::
کہ دو تم بھی اپنے دل کی بچے
تم تو ہو ہی من کے سچے
بہو:: ہاں آپ بھی بھڑاس نکال لیں کہیں دل کے ارمان دل ہی میں نہ رہ جائیں۔
خادم:: دل کے تار سلامت ہوں گے تو ارمان نکلیں گے، میرے تو حواس بھی چھوٹے جا رہے ہیں ساس بہو کے جھگڑے میں۔
بہو:: بند کریں خادم اپنا راگ۔ آپ کے دل کے تار ٹوٹیں یا حواس چھوٹیں میری پنکی کو ران ضرور جائے گی۔“
ساس:: اگر تم کھال اتارنے میں ماہر ہو بہو! تو میں بھی کھال کھینچنے میں کسی سے کم نہیں۔
بیٹا:: (منمناتے ہوئے) کھال میں لُوں گا۔
ساس:: خادم بیٹا تمہیں کھال کی اچھی سوجھی۔ کیا کرو گے کھال لے کر؟
بیٹا:: یتیم خانے میں دوں گا امی حضور۔
ساس:: کیوں دو گے یتیم خانے میں؟ یتیم تم بھی ہو اور میں بھی تمہارے باپ کو مرے پانچ برس اور میرے باپ کو مرے پچّیس سال ہوگئے، زیادہ حق میرا بنتا ہے، اس لیے کھال تو میں ہی لوں گی۔ یوں بھی میں نے غفار بھائی سے پہلے ہی معاملہ طے کر لیا ہے۔ ان کے ہاتھوں فروخت کروں گی۔
بہو:: فرمائش بھی دل والوں سے کرتے ہیں خادم! مجھ سے کہتے اپنا دل چیر کر رکھ دیتی آپ کے آگے۔
ساس:: ہاں بھئی ”ماں سے بڑھ کر چاہے پھاپھا کٹنی کہلائے“ بی کٹنی نکلتا کیا تمہارے دل سے۔
بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا
جو چیرا تو اک قطرۂ خوں نہ نکلا
بہو:: ظاہر ہے جب سارا لہو آپ نچوڑ لیں گی تو بچے ہی گا کیا؟ خادم آپ لے لیجیے گا کھال۔
ساس:: کباب میں ہڈی آپ خاموش رہیں تو بہتر ہے، ہاں خادم بیٹا! غفار بھائی سے میں کھال کے بدلے میں بچھیا خریدوں گی اپنی رانی بٹیا کے لیے۔
بہو:: آپ بھی ساون کی اندھی ہیں ادھر قربانی کے جانورکی بات چلی ادھر آپ کو ایسی ہری ہری سوجھتی ہے کہ باغ کا سبزہ بھی ماند پڑ جاتا ہے۔
ساس:: تمہاری زبان کے آگے تو خندق ہے لیکن میں بھی میں ہوں۔ کھال کا جو فیصلہ میں نے کر لیا سو کر لیا۔ اب میں کسی کی نہیں مانوں گی۔ ہرگز بھی نہ مانوں۔
بہو:: میں بھی دیکھتی ہوں کیسے نہیں مانیں گی؟ کیسے جاتی ہے آپ کی رانی کو ران؟
ساس:: رانی کے ابا حضور کا ذوق اچھا تھا بکرا ایسا لاتے دیکھ کر میرا دل خوش ہوجاتا اور پھر رانی کی فرمائش پر ایسا سجاتے کہ سارا محلہ اکٹّھا ہو جاتا، خادم بیٹا تم! بھی اپنے بکرے کو ویسا ہی سجا کر اپنے ابا حضور کی یاد تازہ کر دو۔
بہو:: باسی یادیں تازہ کرتے ہوئے پنکی کو نہ بھول جائیے گا۔ اگر رانی مہارانی کو ران جائے گی تو پنکی بھی محروم نہیں رہے گی۔
ساس:: اس کا فیصلہ بھی ابھی ہو جاتا ہے، اچھا خادم یہ بتاؤ بیٹا ”بکرا کس کے نام کا ہے؟“
خادم:: یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ کے نام کا ہوتا ہے آپ کے نام کا ہوگا۔
ساس:: سن لیا ملکۂ عالیہ، فیصلہ تو ہو گیا۔ میرے نام کا بکرا، میری مرضی جس کا جو حصہ لگاؤں۔
بہو:: خادم اس بار میرے نام کی قربانی کر دیجیے۔“
ساس:: ارے کیسے کر دے، کیوں بھئی خادم کس کے نام کی قربانی ہو گی؟
بیٹا:: آپ کے نام کی امی حضور۔
ساس:: شاباش میرے بیٹے شاباش، کیسا ماں کا دل رکھتا ہے میرا خادم۔
بہو:: (روتے ہوئے) یہ نا انصافی ہے خادم کیا آپ کی کمائی پر میرا کوئی حق نہیں؟
ساس:: ہے کیوں نہیں سارا سال تم ہی تو ڈکارتی ہو۔
بہو::
کر لو تم اپنی من مانی مہارانی
اگلے برس ہوگی میری حکمرانی
ہاں ساسو جی تم دیکھ لینا اگلے برس میرا راج ہوگا اور تمہاری ”میں“ کند چھری کی زد پہ ہوگی پھر کیسے کہو گی ”میں تو ہر گز نہ مانوں“
ساس:: ارے تو کیا اگلے برس تم مجھے سولی پہ چڑھا دو گی؟ جب تک میں زندہ ہوں میری ”میں“ تند چھری کی زد پہ رہے گی۔
میں نے کبھی کسی کی نہ مانی ہرگز بھی نہ مانی
میں ہُوں اپنی ”میں“ کی رانی سُن لو میری بہو رانی
اور ہاں پَر کٹی پنکی کے لیے تو میں ہرگز بھی نہ مانوں۔
٭٭٭٭
بیٹا:: ہائے امی حضور میں لٹ گیا تباہ ہو گیا، ساس بہو کی کل کل نے سب ختم کردیا۔ ہائے میرے خون پسینے کی کمائی کیسے چٹ پٹ ہو گئی، ہائے میرا بکرا اتنا مہنگا خریدا تھا۔
بہو:: کیا ہو گیا آپ کی امی حضور کے بکرے کو؟
ساس:: کیا ہوا میرے بکرے کو؟
بیٹا:: یہ سب آپ دونوں کی وجہ سے ہوا ہے، آپ لوگوں کی میں میں نے برکت ہی اٹھا دی۔
ساس بہو:: ہوا کیا ہے؟
بیٹا:: امی حضور بکرا نہیں ہے۔
ساس:: بکرا نہیں ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کر تو میں نے خود اسے چارا دیا ہے۔
بہو:: قربانی کا جانور اور نیت اچھی نہ ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے ساس حضور۔
ساس:: اری چپ کر بدبخت
ہستی ہی تیری کیا ہے بھلا میرے سامنے
ہائے خادم بیٹا! میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے، ہائے میرے بچے کہیں سے بکرا ڈھونڈ کر لاؤ، اب میں کیا کروں گی، ہائے میرا بکرا۔
بیٹا:: کہاں سے لاؤں امی حضور؟
ساس:: ہائے بیٹا! میرا بکرا
بہو:: ہائے امی کی نیت کھا گئی بکرے کو
ساس:: میری نیت یا تمہاری پنکی کی نیت؟
بیٹا:: ختم کریں بک بک جھک جھک۔ آپ دونوں کی میں میں سے بکرا گیا ہاتھ سے، ار ے ایک کی نہیں دونوں کی نیت خراب ہے
ہائے بکرا، وائے بکرا
کھا گیا دونوں کا جھگڑا
(تحریر: شائستہ زریں ؔ)