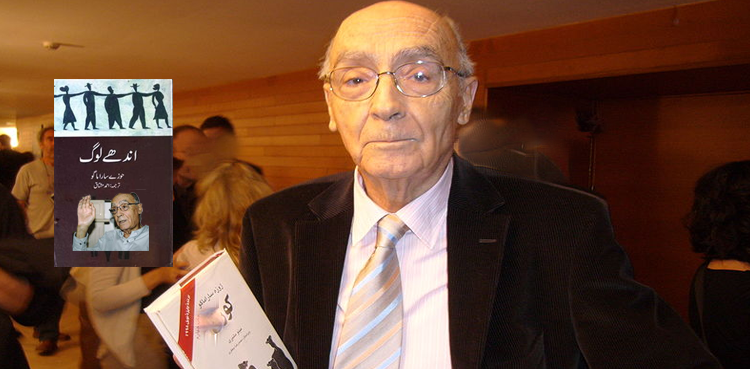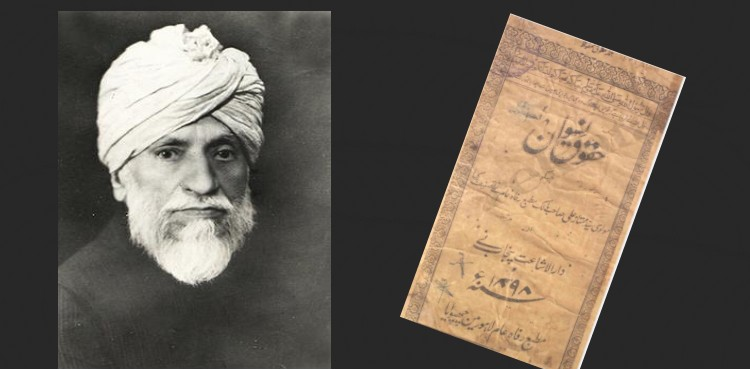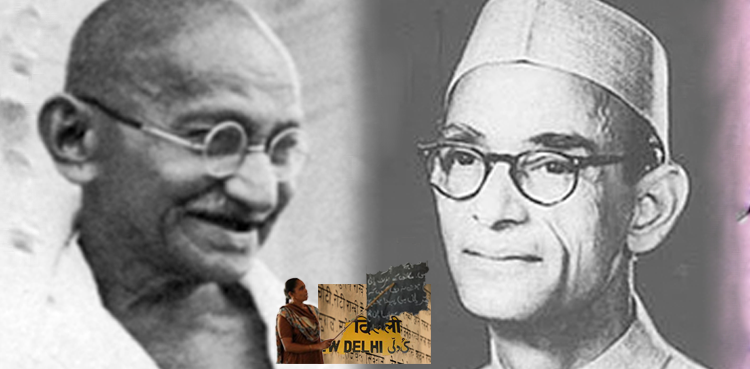دوسرے دن میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حسین صبح اپنی سحر انگیز آنکھوں کو کھول رہی ہے۔ باغ کی طرف کے دریچے کھلے ہوئے تھے اور آفتاب کی اچھوتی کرنیں گرجنے والے نیلے سمندر پر مسکرا رہی تھیں۔ باغیچے میں راگ گانے والے پرند مصروفِ نغمہ تھے مگر میرا دل اس دل فریب صبح میں بھی پریشان تھا۔
میں نے سرہانے کی کھڑکی کا سنہرا پردہ ہٹایا اور جھانک کر باغ میں دیکھنے لگی۔
عین دریچے کے نیچے ایک بڑا سا سرخ گلاب بہار کی عطر بیز ہواؤں میں والہانہ جھوم رہا تھا۔ نہ جانے زندگی کی کون سی تفسیر بیان کررہا ہے! کسے معلوم محبت کے کس پیچیدہ مسئلہ کی تشریح کررہا ہے! میں نے پریشان لہجہ میں اپنے آپ سے کہا۔ اتنے میں پردہ ہٹا۔ دیکھا تو زوناش (بوڑھی حبشی خادمہ) اپنی موٹی کمر سمیت اندر داخل ہورہی ہے: "خاتون روحی!” اس نے قدرے حیران ہوکر کہا۔
"آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئیں؟ بیگم زبیدہ ناشتہ کے لئے آپ کا انتظار کررہی ہیں۔”
صبح کے وقت میں کچھ زیادہ تنک مزاج ہوتی ہوں۔ زوناش سے خصوصاً کچھ چڑ سی ہوتی ہے۔ لہٰذا میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جھک کر صوفے کے پیچھے سے ستار اٹھا لیا اور اس کے تاروں کو درست کرنے لگی۔ زوناش ایک خوش رنگ ایرانی قالین پر کھڑی مجھ سے سوال پر سوال کئے جارہی تھی۔ اتنے میں دادی زبیدہ کی خادمہ صنوبر اندر آئی۔ خاتون روحی، چائے تیار ہے بیگم آپ کی منتظر ہیں۔
میں ایک بیزار ادا سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ قد آدم آئینہ کے آگے کھڑی بالوں پر ایک پن لگا رہی تھی کہ ایک خیال نے مجھے چونکا دیا۔
"زوناش! چائے کی میز پر دادی زبیدہ تنہا ہیں یا چشمی صاحب بھی موجود ہیں؟ مجھے کیا معلوم بی بی؟ زوناش کے ان روکھے سوکھے جوابوں سے مجھے دلی نفرت تھی۔ اور منیر کو رات بخار تو نہیں ہو گیا؟ کیسے رہے؟ یہ سوال میں نے مصلحتاً کیا۔
"نہیں۔ وہ اچھے ہیں۔” میں تبدیلیٔ لباس کے بعد چپ شاپ نچلی منزل میں آگئی۔ دیکھا تو دادی زبیدہ ایک نفیس ریشمی لباس میں بیٹھی ناشتہ کے لئے میرا انتظار کر رہی تھیں۔ ایک ہاتھ فاختائی رنگ کے دستانہ میں ملفوف تھا۔ دوسرا دستانہ سے خالی تھا۔ اس کی انگلیوں میں سگریٹ پکڑ رکھا تھا جس کا مسلسل دھواں اٹھ اٹھ کر دائرہ کی شکل میں گھوم رہا تھا۔ سامنے حسبِ عادت اخبار پڑا تھا جسے وہ کبھی کبھی پڑھ لیتی تھیں۔ میں نے جاکر انہیں پیار کیا۔ آداب دادی جان پیاری! آداب۔ تم بڑی دیر میں آئی پیاری۔ میں سویرے اٹھ گئی تھی۔ نماز میں کچھ دیر لگ گئی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے مقابل والی خالی کرسی پر نگاہ ڈالی۔ پھر کچھ تأمل کے بعد پوچھا، چشمی صاحب کہاں ہیں؟ کیا وہ چائے پی چکے؟ وہ آج صبح سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ دادی زبیدہ نے بے پروائی سے کہا: مربہ لو گی؟ لے لوں گی۔ وہ کہاں گئے ہیں دادی جان؟ میں نے بے چین ہوکر پوچھا۔
یہ لو گاجر کا حلوا۔ اور یہ شہتوت کا مربہ۔ اس موسم میں صبح کے ناشتہ پر تازہ پھل ضرور کھانے چاہئیں۔ انناس کے قتلے لے لو۔ میں نے بادلِ ناخواستہ ایک ٹکڑا لیا اور چھری سے کاٹ کر کھانے لگی۔ دو منٹ بعد ہمت کر کے وہی سوال دہرایا۔ تو چشمی صاحب کہاں گئے ہیں دادی جان؟
جو انناس تم کھا رہی ہو وہ ترش تو نہیں؟ اگر ترش ہو تو کیلا لے لو۔ چشمی صاحب کشتی کی سیر کے لئے گئے ہیں۔ غریب دن رات منیر کے کمرہ میں رہتا ہے۔ آج اس نے چھٹی منائی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اس لڑکے کو نہایت شریف پایا۔ یہ انجیر لو بیٹی۔
میں چپ تھی اور سوچ رہی تھی ۔ منیر کی تیمار داری نے آخر چشمی کو مضمحل کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ دوسرے کی تیمار داری ایک دن خود انہیں بیمار کر ڈالے گی۔ میں نے دبی زبان سے پوچھا: "تو کیا چشمی صاحب علیل ہیں دادی جان؟”
"نہیں۔ ویسے ہی تفریحاً باہر گئے ہیں۔ لڑکی! تمہاری آنکھیں گلابی ہو رہی ہیں۔ طبیعت کیسی ہے؟” "جب سے یہاں آئی ہوں طبیعت کچھ سست سی رہتی ہے ، دادی جان۔”
دادی زبیدہ نے فکر مندی کے الفاظ میں کہا۔ "سمندر کی ہوا تمہارے لئے مفید ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں چشمی صاحب سے التجا کرتی کہ تمہیں کشتی کی سیر کے لئے ساتھ لے جائیں۔ بڑا شریف آدمی ہے۔” مالک جانے میرا دل کیوں دھڑکنے لگا ۔ کشتی کی سیر! لہروں کی خاموش موسیقی! جھکی ہوئی خم دار ٹہنیوں کے سایہ میں چشمی جیسے ملاح کے ساتھ ایک نامعلوم آبی راستہ پر چلا جانا! یہ سب کچھ کس قدر رومان آفریں تھا۔
"شام تک وہ لوٹ آئیں گے۔ میں ان کے ساتھ شام کو باہر جاسکتی ہوں دادی جان؟” میں نے بھولی شکل بناکر پوچھا۔ "ہاں کیوں نہیں مگر منیر سے پوچھ لو۔ منیر سے پوچھ لو!” میری خوشیوں کے افق پرایک سیاہ بدلی ابھرنے لگی۔
ناشتہ کے بعد میں منیر کی مزاج پرسی کے لئے ان کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ تک جا کر رک گئی ۔ کہیں چشمی نے اس بد نصیب آدمی کو میرا پیام پہنچا تو نہیں دیا۔ دل دھک سے رہ گیا۔ ڈرتے ڈرتے پردہ ہٹا کر اندر آگئی مگر آثار کچھ ایسے معلوم نہ ہوئے۔ کیونکہ مجھے دیکھ کر منیر کے چہرے پر وہی پرانی شگفتہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر میرا دل دکھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کی کہ میں کیوں اس سے محبت نہیں کر رہی، کیا باوجود کوشش کے میں اس سے محبت نہ کر سکوں گی؟ اپنے منسوب سے!! اپنے ظلم پر خود اپنی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں نے چہرہ دریچہ کی طرف پھیر لیا۔ پھر بڑی ملائمت سے سوال کیا:
"منیر! آج تم بہت شگفتہ نظر آرہے ہو ۔ کہو رات کیسی کٹی؟ ”
"شکریہ! بہت اچھی کٹی۔ نیز محسوس کررہا ہوں کہ صحت بڑی سرعت سے مجھ پر عود کر رہی ہے۔” اسی وقت دادی جان اندر آئیں اور کہنے لگیں: "خدا نے چاہا تو ایک ہفتہ میں بالکل تندرست ہوجاؤ گے۔ پھر انشاء اللہ میں تم دونوں کو ایّام عروسی بسر کرنے کوہ فیروز کے پُر فضا مرغ زاروں میں چھوڑ دوں گی۔” منیر مسکرا پڑا۔ میں دور کہیں فضا میں تک رہی اور تشنج کی سی کیفیت محسوس کررہی تھی۔
کچھ دیر بعد دادی زبیدہ چہل قدمی کے لئے باہر چلی گئیں اور کمرے پر موت کی سی خاموشی طاری ہوگئی۔ ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں غرق تھے۔ ایک ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا، دوسرا ابھر ابھر کر ڈوب جاتا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے منیر کو دیکھا۔ وہ بغور مجھے تک رہا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کا نوجوان چہرہ وفور مسرت سے آفتاب کی طرح دمک رہا تھا۔ وہ مجھ پر جھک کر کہنے لگا۔ "تمہیں کوہ فیروز کے مرغ زار پسند ہیں؟”
"بہت منیر!” دھڑکتے ہوئے دل سے میں نے کہا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ نہایت دھیمے لہجہ میں بولا: "میری جان! زندگی کی کلی ایسے ہی مرغزاروں میں کھل کر پھول بنتی ہے۔ روحی اس دن کا خیال کرو جس دن ہم دونوں۔۔۔ پھولوں سے سجے ہوئے پھلوں سے لدے ہوئے باغیچوں میں چنبیلی کی معطر بیلوں تلے ایک دوسرے کی محبت کا اعتراف کریں گے۔”
میرے دل پر ایک تیر سا لگا کیونکہ میں ابھی تک اس کشتی کا خواب دیکھ رہی تھی جس کا ملاح چشمی تھا۔ دو منٹ بعد مجھے اپ نی خاموشی کا احساس ہوا۔ بولی: "واقعی منیر! باغیچوں میں چنبیلی کی بیلوں تلے محبت کا رات گانا بے حد پرلطف ہوگا۔”
"اور پھر ہم دونوں”۔۔۔ منیر نے جملہ ختم نہ کیا۔ مگر "ہم دونوں” کے لفظ نے میرے کاہیدہ جسم میں ایک ارتعاش پیدا کردیا۔ کون دونوں۔۔۔؟ منیر اور میں۔۔؟ یا دو محبت کرنے والے دل؟
کچھ دیر بعد میں منیر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ باغ کے زینے پر کھڑی سوچتی رہی۔ آہ! میری زندگی کا پلاٹ کتنا عجیب ہے! اگر میں منیر سے نفرت کر سکتی تو میں ان الجھنوں میں مبتلا نہ ہوتی۔ اگر محبت کر سکتی تو ان تمام مصائب کا خاتمہ ہو جاتا! مگر آہ! اس شخص سے نہ میں محبت کر سکتی نہ نفرت! میرے دل میں منیر کے لئے ہمدردی موجود تھی۔ میں اپنے آپ کو اس کی گنہگار محسوس کر رہی تھی۔ آہ! گناہ کا احساس! محبت کی مجبوری!
میں باغ میں چلی گئی اور فوارہ کے قریب ایک کوچ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بار بار نہر کی طرف دیکھ رہی تھی ۔ چشمی کی کشتی واپس آ رہی ہوگی مگر نہ آئی۔ جب دوپہر کی گرم ہوائیں چلنے لگیں تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ بہت دیر ایک صوفے پر پڑے موجودہ حالات پر غور کرتی رہی۔ چشمی دوپہر کے کھانے پر بھی نہ آئے تو مجھے شبہ ہوا کہ وہ مصلحتاً گھر سے باہر رہنا پسند کرتے ہیں۔
جب سائے ڈھل گئے اور ہواؤں میں دوپہر کے آفتاب کی تمازت کم ہوگئی تو میں بلاارادہ پھر باغ میں گھاٹ پر نکل آئی اور آنے والی کشتیوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں انتظار کی درد انگیز خلش محسوس کر رہی تھی۔
سورج زیتون کی ٹہنیوں کے اوپر تھا۔ کچھ دیر بعد وہ درختوں کی شاخوں تلے نظر آنے لگا۔ نہر کا پانی خالص سونے کی طرح سنہرا ہو گیا اور پورا باغیچہ دھوپ کی لہروں میں جگمگا اٹھا۔ دور۔۔ سنہری سنہری لہروں میں ایک ننھی سی نیلے رنگ کی کشتی نظر آنے لگی۔ میرا دل دھڑکا۔
اللہ جانے کیوں یہ آج کل غیر معمولی طور پر دھڑکنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد میں گنگنانے لگی
چشم قمر کو بھی مرے خوابوں پہ رشک ہے
پیش نظر ترا رخ روشن ہے آج کل
جس آستاں کو سجدۂ پرویں بھی بار تھا
وہ آستاں جبیں کا نشیمن ہے آج کل
بانس کے سر بلند درختوں پر ایک ہد ہد زور سے گا رہا تھا کہ اتنے میں وہ نیلی کشتی گھاٹ پر آ لگی۔ ادھر میرے دیکھتے دیکھتے چشمی اتر آئے۔ ان کی نظر مجھ پر پڑی۔”
آپ یاں کیا کررہی ہیں خاتون روحی؟” انہوں نے بچوں کے سادہ لہجہ میں پوچھا۔
لیکن میں کیا جواب دیتی؟ کیا یہ کہہ دیتی کہ آپ کے انتظار نے قریب المرگ کر رکھا تھا۔ توبہ توبہ۔ یہ کس طرح کہہ سکتی تھی۔ کچھ بوکھلا سی گئی۔ بولی: "میں؟ یوں ہی یہاں بیٹھی تھی۔ اندر بہت گرمی تھی۔ آج کا دن بڑا گرم رہا۔ آپ کہاں گئے تھے؟” یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی جاپانی وضع کی نارنجی چھتری کھول لی۔
"میں ذرا دل بہلانے نکل گیا تھا۔”
"ہاں” میں نے کہا۔
"گھر میں وحشت ہوتی ہوگی۔ تیمار داری کوئی دل چسپ کام نہیں۔”
"یہ آپ کیا فرماتی ہیں خاتون روحی!” چشمی نے مؤثر لہجے میں کہا۔ "منیر صاحب کی تیمار داری میرا ایک مرغوب فرض ہے۔ آپ نہیں جانتیں مجھے ان سے کتنی محبت ہے۔”
"میں جانتی ہوں” میں نے سنجیدگی سے کہا۔ "آپ نہیں جانتیں” چشمی ہنس کر بولے: "اس کا اندازہ یا تو منیر لگا سکتے ہیں یا پھر میرا دل۔”
میں اب بھی سنجیدہ تھی: "افوہ! اتنی گہری محبت ہے؟” یہ کہتے ہوئے میں نے ایک بے چینی سی محسوس کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چشمی نے میری وحشت کو محسوس کیا پھر کہنے لگے: "آپ گھبرائی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ یہاں بہت گرمی ہے۔ شمشاد کے درختوں کی طرف چلیے، اس چبوترے پر ہمیشہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔” اس نے میرا بازو تھام لیا اور شمشاد کے درختوں کے پاس سنگ مرمر کے ایک سفید چبوترہ پر لے گیا۔
"میں گھبرائی ہوئی نہیں ہوں، صبح سے ایک افسانہ لکھ رہی تھی۔ ایک جگہ پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں تو سوچنے کے لئے ادھر نکل آئی۔ کیا اپنے افسانہ کا پلاٹ آپ کو سناؤں؟ آپ کوئی رائے دے سکیں گے؟”
"زہے نصیب!” چشمی نے کہا: "مگر میں صائب الرّائے نہیں۔ ویسے افسانے بڑی دل چسپی سے پڑھتا ہوں۔ فرمائیے۔”
"تو سنئے!” میں نے کہا: "مگر افسانہ کچھ زیادہ رنگین ہے۔ آپ مجھ پر عریاں بیانی کا الزام تو نہ لگائیں گے۔”
"میری مجال نہیں۔ میں موپاساں کے افسانے پڑھ چکا ہوں”۔ چشمی نے کہا۔
"توبہ کیجئے۔ یہ افسانہ ایسا نہیں۔ اس کی عریانی میں بھی زندگی کا درد پوشیدہ ہے”۔
"فرمائیے”۔
میں نے احتیاطاً ایک دفعہ اور کہا: "مجھ پر شوخی کا الزام کسی طرح بھی نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ پلاٹ میرا اپنا نہیں۔ میں نے کہیں سے لیا ہے۔ اس لئے اس کی کوئی ذمہ داری مجھ پر نہیں بلکہ اس کے مصنف پر عائد ہوتی ہے۔”
"بالکل”۔ میں کہنے لگی: "افسانہ دو مردوں اور ایک عورت سے شروع ہوتا ہے۔”
"اف!” چشمی نے کہا: "یہ پلاٹ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ زمانہ قدیم میں۔۔۔”
"ٹھہریے، دیکھئے چشمی صاحب! پہلے آپ پلاٹ سن لیجئے پھر آپ سے آپ کی رائے پوچھی جائے گی۔”
"بہت اچھا!”
"تو ایک عورت اور دو مرد۔ عورت اس مرد سے بے پروا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ مرد اس عورت کو نہیں چاہتا جس سے یہ عورت محبت کرتی ہے۔ تو ایسے موقع پر عورت کو کیا کرنا چاہئے؟” چشمی کہیں دور ہری ہری دوب کے اس پار سنہری لہروں کو دیکھ رہے تھے۔
"میں زود فہم نہیں ہوں۔ اک دفعہ پھر آسان زبان میں کھول کر فرمائیے۔”
کھول کر! یہ ظالم اس کتاب کو کھول کر پڑھنا چاہتا ہے! آہ۔۔۔ میں بولی: "آپ نہیں سمجھے۔ عورت اس مرد کو چاہتی ہے جس کے متعلق اسے خود خبر نہیں کہ وہ مرد بھی اس سے محبت کر رہا ہے یا نہیں اور اس مرد کو نہیں چاہتی جس کے متعلق اسے علم ہے کہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ میں کسی قدر کانپ رہی تھی۔
"اب میں سمجھ گیا”۔ چشمی نے دور کہیں فضا میں تکتے ہوئے کہا۔
"تو پھر ایسے موقع پر عورت کو کیا کرنا چاہئے؟”
"مگر سوال یہ ہے”۔ چشمی کہنے لگے: "عورت جس مرد کو چاہتی ہے اس کے متعلق اس کے پاس اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ وہ مرد بھی اس پر جان نہیں دے رہا۔”
"کیا۔۔۔؟” بیساختہ میں بول پڑی ۔ میرے چہرے پر سرخی دوڑ گئی: "آپ نے کیا کہا ؟وہ مرد؟۔۔۔”
چشمی کے چہرے پر بے چینی اور اضطراب کی علامات نمودار ہوئیں، کہنے لگے: میں۔۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے محبوب سے عورت کو گمان ہونے کے اسباب کیا ہیں؟”
واقعی میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا: "تو۔۔۔ تو کیا وہ مرد بھی۔” اتنا کہہ کر میں یک لخت رک گئی۔
"ہاں تو آپ چپ کیوں ہو گئیں؟ پورا پلاٹ سنا ڈالیے۔”
"ختم ہو گیا۔” میں نے کہا: "بس اتنی ہی بات پوچھنی تھی۔ آج کئی دن سے اس پلاٹ کو سوچ رہی تھی کہ ایسے موقع پر عورت کو کیا کرنا چاہئے؟ کیا وہ مرد بھی۔ اس سے محبت کرتا ہے؟” میری آواز لرز گئی۔ میرا چہرہ کیلے کے نوخیز پتے کی طرح زرد پڑ گیا۔
ہائے کبھی کاہے کو میں نے ایسی مصیبتیں اٹھائی تھیں؟ میرے معبود مجھ پر رحم کر۔ چشمی نے ایک گہری سانس لی۔ ان کے چہرے پر فکرمندی کے آثار تھے۔ سنجیدہ لہجہ میں بولے: "تو کیا عورت کو اس دوسرے مرد سے جس کی محبت کا اسے یقین نہیں، واقعی محبت ہے۔”
"ہائے، ہاں۔ شدید شدید ہے چشمی صاحب !” میرے منہ سے نکل گیا۔ پھر میں سہم گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دعا کے پیرایہ میں میرے ہونٹوں سے اک آہ نکل گئی کہ اے عشق! نسوانی خودداری کو اس طرح پامال نہ کرو۔ یہ سچ ہے کہ تیرے آہنی ہاتھوں نے شاہنشاہوں کے تاج چکنا چور کر دیے مگر ایک بے بس مظلوم لڑکی پر رحم کر۔ آہ محبت کی مجبوریاں!
بڑی دیر تک ہم خاموش رہے۔ نارنجی رنگ کا بڑا سا آفتاب سمندر کی لہروں میں غرق ہونے لگا۔ باغ پر ایک افسردگی سی چھا گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے چشمی کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ ان کی گہری نیلی آنکھیں اداس نظر آ رہی تھیں۔ لیکن دفعتاً انہوں نے کہا:
"آپ نے افسانہ کے تیسرے فرد کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ اس کا کیا ہوگا؟”
میں بوکھلا سی گئی۔ غم ناک لہجہ میں بولی: "یہ ایک نامکمل پلاٹ ہے چشمی صاحب۔ میں اسے ختم نہیں کر سکی۔ نہیں معلوم، اس پلاٹ کے اختتام پر کتنی زندگیوں کا انحصار ہے۔”
میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جھٹ میں نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔
"ایسے پلاٹ عموماً بہت مشکل ہوتے ہیں خاتون روحی! بہرحال ایسی افسانوی باتوں پر آپ زیادہ غور نہ فرمایا کیجیے۔”
"شعر اور افسانہ تو میری جان ہے اور اس پر غور کرنا میری زندگی۔” میں نے بمشکل کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی: "چلیے دادی جان چائے پر انتظار کر رہی ہوں گی۔”
(نوٹ: بیسویں صدی کی حجاب امتیاز علی کا نام اردو فکشن نگاروں میں سرفہرست ہے۔ ان کی تحریروں کا دل کش انداز اور اردو زبان و ادب کی ترقی میں ان کا کردار ناقابلِ فراموش ہے۔ حجاب امتیاز علی کا یہ دل چسپ اور یادگار افسانہ "ظالم محبت” کے عنوان سے پہلی بار 1938 میں شائع ہوا تھا۔)