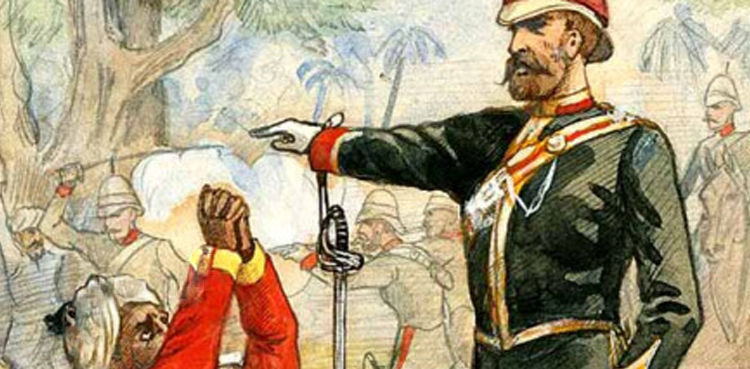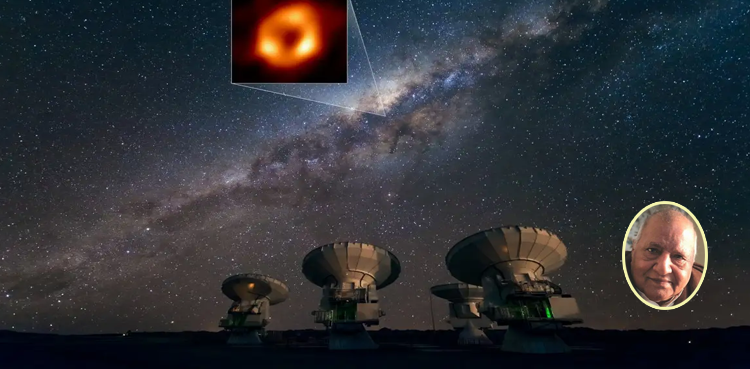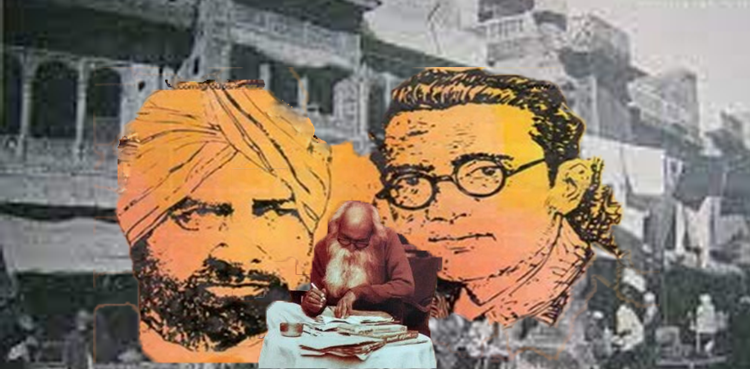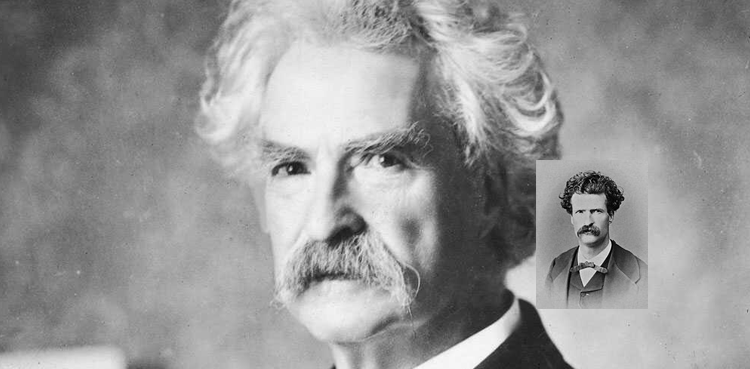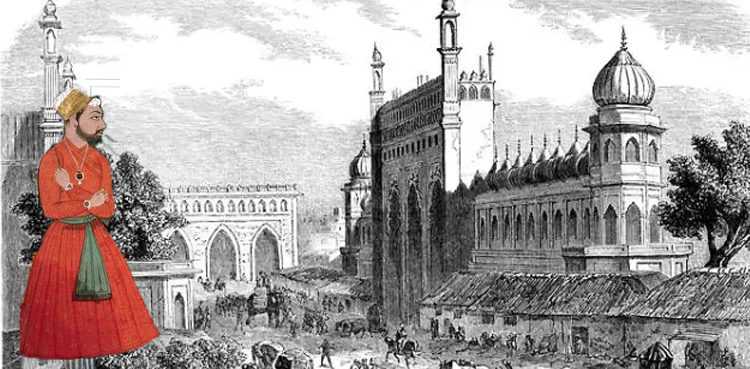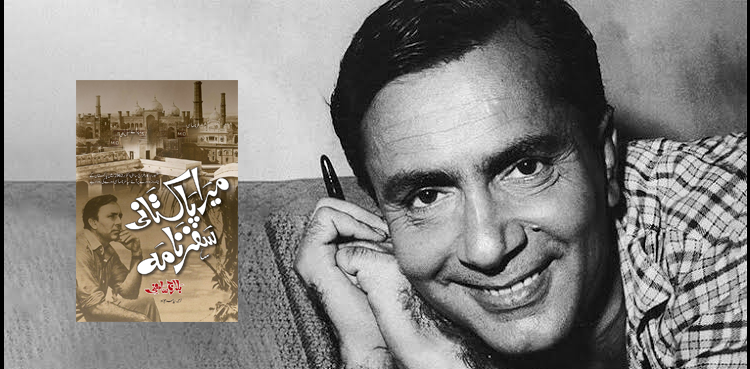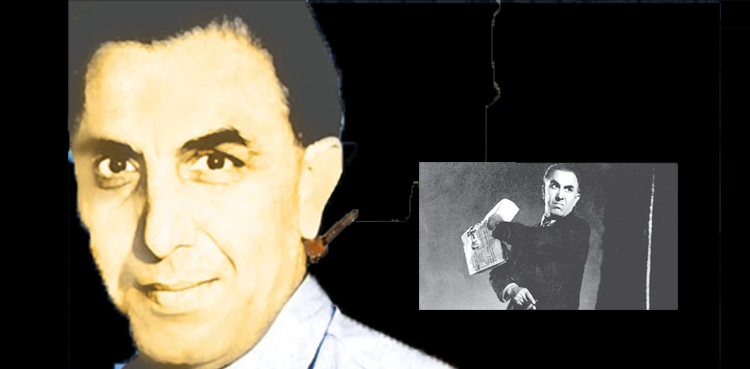کہنے کو تو نادر چار بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، لیکن گھر میں اُس کا خیال اس طرح رکھا جاتا، جیسے وہ سب سے چھوٹا ہو۔ بہن بھائیوں کے درمیان جب بھی کسی بات پر جھگڑا ہوتا، تو چاہے قصور نادر ہی کا کیوں نہ ہو، امی ابو کی ڈانٹ ڈپٹ ہمیشہ دوسرے بہن بھائیوں کے حصّے میں آیا کرتی۔
ایک دن سارے بہن بھائی گھر کے چھوٹے سے صحن میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ امجد بولنگ اسٹینڈ پر فاسٹ بولروں کے انداز میں گیند کروانے کی کوشش کر رہا تھا اور نادر گھی کے خالی کنستر کے آگے بلّا تھامے شاٹ کھیلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اپنی طرف آتی گیند کو اُس نے نظروں ہی نظروں میں تولا اور ایک زور دار شاٹ لگانے کے لیے بلّا گھما دیا۔ گیند سیدھی ایک کھڑکی کے شیشے سے ٹکرائی اور دیکھتے ہی دیکھتے شیشہ چکنا چور ہو کر فرش پر بکھر گیا۔ پورے ”میدان“ میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ اُس دن اتوار تھا اور صبح ہی سے بچوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔
نادر کے والد افتخار حسین اپنے کمرے میں اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز سنتے ہی وہ اور اُن کی بیوی صغراں دوڑتے ہوئے صحن میں آئے۔ افتخار حسین نے غصّے سے تمام بچوں کی طرف باری باری دیکھا۔ تمام کھلاڑیوں پر سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ نادر کے ہاتھوں میں بلاّ چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ شیشہ اسی کے ہاتھوں شہید ہوا ہے۔ افتخار حسین نے ایک سرسری نگاہ نادر اور بلّے پر ڈالنے کے بعد بولنگ اسٹینڈ پر کھڑے امجد کو شعلہ بار نظروں سے گھورا۔
”ابّو! شیشہ بھائی…. نے توڑا….ہے۔ میں تو بولنگ کروا رہا تھا۔“ امجد نے فوراً ہکلاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔
”امجد سچ کہہ رہا ہے، شیشے پر گیند بھائی نے ماری ہے۔“ ”سلپ“ میں کھڑی ننھی تہمینہ نے فوراً امجد کے حق میں گواہی دی اور دیگر بہن بھائیوں کے سر اُس کی تائید میں ہلنے لگے۔ ”عینی شاہدوں“ کے بیانات نظر انداز کرتے ہوئے افتخار حسین کا ایک بھرپور تھپڑ امجد کے گال پر پڑا اور دوسرا پرویز کی پیٹھ سہلا گیا۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ لگاتے ہوئے ننھی تہمینہ نے پہلے ہی کمرے کی جانب راہِ فرار اختیار کرلی تھی۔
”کمینو! تم لوگ مجھے زندہ بھی رہنے دو گے کہ نہیں۔ بیٹھے بٹھائے ڈیڑھ دو سو روپے کا نقصان کرا دیا۔ مار مار کے ادھ مُوا کر دوں گا، اگر آیندہ کسی کو صحن میں کرکٹ کھیلتے دیکھا۔ دفع ہوجاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔“ اس سے پہلے کہ افتخار حسین کے غصّے کے مزید سنگین نتائج برآمد ہوتے، صغراں نے خود ہی آگے بڑھ کر امجد اور پرویز کی پیٹھ پر دھپ جمائی اور کوسنے دیتی ہوئی بچوں کو کمرے میں لے گئی۔ اس بار بھی اصل ’مجرم‘ نادر صاف بچ نکلا تھا۔
کمرے میں پٹے ہوئے کھلاڑی اپنی اپنی چوٹیں سہلانے میں مصروف تھے۔ نادر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب بہن بھائی اُسے کینہ توز نظروں سے گھورنے لگے۔
”شیشہ تو بھائی نے توڑا، پھر مار ہمیں کیوں پڑی؟“ امجد نے سرگوشی کے انداز میں ماں سے شکایت کی۔ ”اس لیے کہ یہ تمھارا بڑا بھائی ہے اور بڑوں پر ہاتھ نہیں اُٹھایا کرتے۔“
آج پہلی بار اپنے بہن بھائیوں کو پٹتے دیکھ کر نادر کو اچھا نہیں لگا۔ اُس کے دل میں ایک گرہ سی پڑ گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد گھر کی فضا اعتدال پر آگئی۔ بچے اس ”ہول ناک“ سانحے کو بھول کر پھر سے آپس میں کھیل کود میں مصروف ہوگئے۔ شیشے کی کرچیاں سمیٹ لی گئیں اور افتخار حسین کا پارا بھی نیچے آگیا۔ لیکن نہ جانے کیوں نادر کے ذہن سے اس واقعے کا اثر زائل نہیں ہوا۔ کوئی کرچی سمیٹنے سے رہ گئی تھی، جو نادر کے دل میں مسلسل چبھے جا رہی تھی۔ اُس کا معصوم ضمیر اُسے اندر ہی اندر کچوکے لگا رہا تھا۔ ذہن ایک ہی سوال کی بار بار تکرار کیے جا رہا تھا۔
”جب شیشہ میں نے توڑا، تو امجد اور پرویز کو مار کیوں پڑی۔ مجھے تو کسی نے ڈانٹا تک نہیں؟“ اس سوال کے ساتھ ہی اس طرح کے کئی اور واقعات اُس کے ذہن کی اسکرین پر چلنے لگے…..ان سارے سوالات کے جوابات نادر کو سولہ سال کی عمر میں ملنا شروع ہوئے۔ وہ محسوس کرتا کہ اُس کی ظاہری ساخت اپنے دیگر بہن بھائیوں سے مختلف ہے۔ اسے لگتا تھا کہ جنس کے اعتبار سے اس کی بہن تہمینہ ماں کے زیادہ قریب ہے، جب کہ امجد اور پرویز باپ کی شباہت رکھتے ہیں۔ ایسے میں وہ خود کو بیچ دوراہے پر اُس مسافر کی طرح کھڑا پاتا، جو فیصلہ نہیں کرپاتا کہ کون سا راستہ اس کی منزل کی طرف جاتا ہے۔
نادر کو لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا اور بات چیت کرنا اچھا لگتا تھا۔ اُس کی ماں اُسے ٹوکتی کہ وہ اپنی بہن اور اُس کی سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارنے کی بہ جائے اپنے بھائیوں اور محلے کے لڑکوں کے ساتھ گھوما پھرا کرے۔ یہ بات کہنے کے بعد نہ جانے کیوں اُس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آجاتے اور وہ اپنا منہ پھیر کر دوپٹے سے اپنی آنکھیں خشک کرنے لگتی۔ نادر کو لڑکوں کی صحبت سے آہستہ آہستہ کوفت ہونے لگی۔ اسکول اور محلے کے لڑکے اس کا مذاق اُڑایا کرتے اور اس کے بات کرنے اور چلنے کے انداز پر پھبتیاں کستے تھے۔ چناں چہ، اپنے دو بھائیوں کے مقابلے میں اس کا زیادہ تر وقت گھر ہی پر کٹنے لگا۔ وہ محسوس کرتا کہ اُس کے والدین اُسے شادی کی تقریبات میں ساتھ لے جانے سے گریز کرتے ہیں۔ اُن کی کوشش ہوتی کہ وہ اُن کے ساتھ جانے کے بہ جائے گھر پر رہے۔
ایسے ہی ایک موقعے پر جب سارا گھر محلے کی ایک شادی میں شرکت کرنے گیا ہوا تھا، نادر گھر میں اکیلا بُری طرح بور ہو رہا تھا۔ اُس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہ تھا۔ چناں چہ، وقت گزاری کے لیے اُس نے ایک فلمی رسالے کی ورق گردانی شروع کر دی۔ رسالے کے پورے ایک صفحے پر اُس کی پسندیدہ ہیروئن جیا پرادا کی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ وہ انہماک سے اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ اچانک اُس کے دل میں ایک انوکھے خیال نے جنم لیا۔
”کیا میں جیا پرادا کی طرح بن سکتا ہوں؟“ اس خیال کے آتے ہی اُس کے قدم مشینی انداز میں کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اُسے جیا کے لباس جیسا اُس کی ماں کا سبز جوڑا مل گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے لباس تبدیل کرنے لگا۔ اس کام میں اس کے ارادے کا کوئی دخل نہ تھا۔ اُس کے اندر کوئی ایسی چیز تھی، جو اسے اس کام کے لیے اُکسا رہی تھی۔ زنانہ لباس زیب تن کرکے وہ الماری کے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ اپنا عکس آئینے میں دیکھنے سے نادر کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا مختلف زاویوں سے اپنے سراپے کا جائزہ لینے لگا۔
اچانک اس کی نظر سنگھار میز پر رکھے، میک اپ کے سامان پر پڑی، جو تہمینہ جلدی میں کُھلا چھوڑ گئی تھی۔ نادر اسٹول کھینچ کر سنگھار میز کے سامنے بیٹھ گیا اور دل چسپی سے میک اپ کے سامان کا جائزہ لینے لگا۔ بے ساختہ اُس کا ہاتھ ٹالکم پاؤڈر کی جانب بڑھا۔ تھوڑا سا پاؤڈر ہتھیلی پر نکالا اور آہستہ آہستہ چہرے پر ملنے لگا۔ اس کام میں نادر کو مزہ آنے لگا اور وہ مزید پاؤڈر نکال کر اسے دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی اپنے چہرے اور گردن پر اچھی طرح ملنے لگا۔ پھر لپ اسٹک کی باری آئی۔ آنکھوں میں کاجل لگانے سے نادر کی پوری شخصیت ہی تبدیل ہوگئی اور وہ ایک بار پھر آئینے میں اپنا بھرپور جائزہ لینے لگا۔ بے ساختہ اُس کی ہنسی چھوٹ گئی، جو جلد ہی قہقہوں میں تبدیل ہوگئی۔ نادر قہقہے لگاتا ہوا پورے کمرے میں تھرکنے لگا۔ ایسا کرنے میں اُسے بڑا لطف آرہا تھا۔ وہ تھرکنے کے ساتھ ساتھ دونوں بازو پھیلائے گول گول گھومنے بھی لگا۔ کافی دیر تک اس طرح تھرکنے اور گھومنے کے بعد وہ نڈھال ہوکر بستر پر گرگیا۔ تیز سانسوں کی وجہ سے اُس کا سینہ دھونکنی کی طرح چلنے لگا۔ نادر کی بند آنکھیں اور ہونٹوں پر پھیلی ہلکی مسکان اس کے ذہن میں چلنے والے خوش کن خیالات کا پتا دے رہی تھی۔ آج معما حل ہوگیا تھا۔ نادر کو اُس کی منزل کی طرف جانے والا راستہ مل گیا تھا اور اُس نے اِس راستے پر پہلا قدم رکھ دیا تھا۔
کئی برس گومگو کی کیفیت میں رہنے کے بعد آج اس زنانہ لباس میں اُس کی شخصیت کی تکمیل ہوگئی تھی۔ ”اب مجھ سے میرا اپنا پن کوئی نہیں چھین سکتا۔“ نہ جانے کتنی دیر تک نادر کا ذہن ان ہی خیالات کی آماج گاہ بنا رہا اور اُسے پتا ہی نہیں چلا کہ رات کے کس پہر اُس کی آنکھ لگ گئی۔
سکوت کے یہ لمحات دروازے پر ہونے والی تیز دستک کی آواز سے درہم برہم ہوگئے۔ نادر ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ بیٹھا۔ دوسری دستک کے ساتھ ہی اُس کے قدم تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ نیم غنودگی کے عالم میں اسے لباس تبدیل کرنے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ زنانہ لباس میں ملبوس اپنے اہل خانہ کے سامنے کھڑا تھا۔ افتخار حسین کو نادر کو اس حالت میں دیکھ کر سانپ سونگھ گیا اور صغراں کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ امجد اور پرویز کے چہروں پر پہلے تو حیرت کے آثار نمودار ہوئے، پھر اُن کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تہمینہ فیصلہ نہ کرسکی کہ اُسے اپنے بڑے بھائی کو اس حلیے میں دیکھ کر کیا ردعمل ظاہر کرنا چاہیے۔ صغراں کے رونے کی آواز اور افتخار حسین کی شعلہ بار نگاہیں جلد ہی نادر کو غنودگی کی کیفیت سے باہر لے آئیں۔
”وہ ابّو، میں….بور….بور ہو رہا تھا، اس لیے سوچا….. امّی….. کے کپڑے پہن کر دیکھوں….کیسا لگتا ہوں۔“ زندگی میں پہلی بار افتخار حسین کا ہاتھ نادر پر اٹھا۔ اُس رات انھوں نے نادر کو ملنے والا خصوصی استثنیٰ واپس لے کر پچھلی ساری کسر ایک ساتھ پوری کر دی۔
مار پیٹ، قید و بند اور ایذارسانی سے عادتیں تو سدھاری جا سکتی ہیں، لیکن کسی کی فطرت بَھلا کب بدلی ہے، جو نادر کی بدل جاتی۔ گھر والوں کے تشدد اور منت سماجت کے باوجود اُس نے اپنی چال ڈھال نہ بدلی۔ وہ اپنے ہی حال میں مست رہنے لگا۔ کئی مہینوں سے اُس نے حجامت نہیں بنوائی تھی، جس کی وجہ سے اُس کے بال زلفوں میں تبدیل ہونے لگے اور ناخن نیل کٹرکی شکل دیکھنے کو ترس گئے۔ کاجل ہمہ وقت نادر کی آنکھوں کی زینت بنا رہتا، مگر اُس کے ہونٹوں کو اُس واقعے کے بعد لپ اسٹک نصیب نہ ہوسکی۔ افتخار حسین اپنے ہی گھر کے اندر اپنی عمر بھر کی کمائی کو یوں برباد ہوتا دیکھتے اور اندر ہی اندر کڑھتے رہتے۔ نادر کی موجودہ ذہنی کیفیت کے سبب تہمینہ کی سہلیوں نے بھی نادر سے ایک خاص فاصلہ رکھنا شروع کر دیا تھا، جب کہ لڑکوں سے وہ خود فاصلے پر رہنا چاہتا تھا، جواس پر غلیظ جملے کستے اور اُسے چھیڑنے سے باز نہ آتے۔
کوئی بھی جان دار شے اپنے ہم جنسوں کو کسی نہ کسی طرح ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ سو، نادر نے بھی ایک دن اپنے ہم جنس ڈھونڈ ہی نکالے۔
خواجہ سراؤں سے اُس کا پہلا باقاعدہ رابطہ طارق روڈ کے ٹریفک سگنل پر ہوا۔ نادر گھر جانے کے لیے بس کے انتظار میں کھڑا تھا اور کافی دیر سے اُن دو خواجہ سراؤں کی جانب دل چسپی سے دیکھ رہا تھا، جو سامنے سگنل پر رُکی گاڑیوں کے مسافروں سے پیسے مانگنے میں مصروف تھے۔ اچانک لال رنگ کی شلوار قمیص پہنے ایک خواجہ سرا کی نظریں نادر کی نظروں سے چار ہوئیں اور فطرت نے اپنا کام شروع کردیا۔ سُرخ پوش خواجہ سرا نے ہرے رنگ کے زنانہ لباس والے دوسرے خواجہ سرا کو آواز دی،
”اری او چمکی، ذرا ادھر تو دیکھ، کیسا چیسا لورا (خوب صورت لڑکا) ہے، کچھ اپنا اپنا سا لگتا ہے۔“
چمکی نے نادر کی طرف غور سے دیکھا، جو اشتیاق بھری نظروں سے پہلے ہی ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ”ہائے میں مر گئی، نی زیبا، واقعی بڑا چیسا ہے۔ اگر یہ تھوڑا تڑاواہ (میک اپ) کر لے تو اپنی ہی برادری کا لگے۔“ یہ کہہ کر دونوں خواجہ سرا ہنسنے لگے۔
”چل، اس سے بات کرتے ہیں۔ پتا تو چلے کہ پیدایشی ہے یا صرف زنانہ ہے۔“ زیبا نے اپنے سر پر دوپٹے کو ٹھیک کیا اور چمکی کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرنے لگی۔
”سلام علیکم، کیسا ہے رے ہیرو۔“ قریب پہنچ کر زیبا نے نادر کو خواجہ سراؤں کے مخصوص انداز میں سلام کیا۔
”ٹھیک ہوں۔“ نادر خواجہ سراؤں کو اپنے قریب پا کر تھوڑا سا نروس ہوگیا۔
”اگر بُرا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں۔“ زیبا نے استفسارانہ انداز میں نادر کی آنکھوں میں دیکھا۔
”ہا…… ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے۔“ نادر نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔
”کیا تم بھی ہماری برادری کے ہو۔“
”کیا مطلب، میں کچھ سمجھا نہیں۔“ نادر نے استعجابیہ انداز میں کہا۔
”ارے، اس کا مطلب ہے کیا تم بھی ہماری طرح خواجہ سرا ہو۔“ چمکی نے تالی بجا کر لچکتے ہوئے زیبا کے سوال کی وضاحت کی۔ پتا نہیں آپ لوگ کیا پوچھ رہی…. رہے ہیں۔ کیا آپ لڑ…کیاں…. ہیں۔“
نادر کے اس جملے پر زیبا اور چمکی نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ چمکی پھر لچکنے لگی۔
”ہاں ہاں لڑکیاں ہیں، خوب صورت لڑکیاں۔“ جملے کے اختتام پر دونوں مردانہ آواز میں قہقہے لگانے لگے۔
”ایسی لڑکیاں تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، جو شیو بھی کرتی ہیں۔“ نادر کو ان دونوں کے ساتھ بات کرنے میں مزہ آنے لگا۔ اُس کی ہچکچاہٹ دور ہوگئی اور وہ دل لگی پر اُتر آیا۔
”کیا تجھے بھی میک اپ کرنے کا شوق ہے؟“ زیبا بے تکلفانہ انداز میں نادر کے سراپے کا بھر پور انداز میں جائزہ لینے لگی۔
”ہاں ہے۔“ مختصر جواب ملا۔ ”اور زنانیوں جیسے کپڑے پہننے کا؟“ تفتیش جاری رہی۔
”ایک بار پہنے تھے، ابّو نے بہت مارا تھا۔“
”کیا تو بچپن سے ایسا ہی ہے۔“ پھر سوال پوچھا گیا۔
”پتا نہیں، لیکن میں شروع سے اپنے بہن بھائیوں سے الگ ہوں۔ مجھے گھر والے ہر بات پر روکتے ٹوکتے ہیں۔“ نادر نے افسردگی سے کہا۔
ہمارے ساتھ چل، ہم تجھے اپنے گرو، بالی شاہ سے ملواتے ہیں۔ ہمارے ٹھکانے پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وہاں تُو اپنے سارے ارمان پورے کرلینا۔“
وہ دن نادر کی بے سمت زندگی کو ایک سمت دے گیا۔ اس کے پاؤں پھر اپنے گھر پر نہیں ٹکے اور وہ بہانے بہانے سے گھر سے غائب رہنے لگا۔ بالی شاہ کے ٹھکانے پر اپنے ”ہم جنسوں“ سے مل کر اُسے بہت خوشی ہوتی تھی۔ وہ خواجہ سراؤں کے ہم راہ گلی محلوں میں ودھائی (بخشش) لینے بھی جانے لگا تھا۔ افتخار حسین کو جلد ہی اپنے بیٹے کے ان کرتوتوں کا علم ہوگیا اور وہ اس پر اور زیادہ سختیاں کرنے لگے۔
گھر والوں کی طرف سے لاکھ پہرے بٹھانے کے باوجود نادر نے بالی شاہ کے ٹھکانے پر جانا نہیں چھوڑا۔ وہ بالی شاہ سے ملنا چھوڑ بھی کیسے سکتا تھا۔ اُسے تو بالی شاہ کا ٹھکانا ہی اپنا اصل گھر اور بالی شاہ کے چیلے اپنے اپنے سے لگتے تھے۔ افتخار حسین جب بھی اُسے مارتے تو وہ روتا ہوا بالی شاہ کے ٹھکانے پر جا پہنچتا۔ بالی، نادر کو افسردہ دیکھ کر تڑپ اُٹھتا، فوراً اُسے اپنی بانہوں میں بھر کر اُس کے سر پر دستِ شفقت پھیرنے لگتا اور اس کے رستے زخموں پر مرہم رکھتا۔ نادر کو زنانہ لباس میں دیکھ کر اُس کے بہن بھائی اُس سے نفرت کرتے اور بالی شاہ کے چیلے اُس کی بلائیں لیتے۔ افتخار حسین اور صغراں نادر کو کسی تقریب میں لے جانے اور گھر آئے مہمانوں سے اُس کا تعارف کروانے میں بھی شرمندگی محسوس کرتے، جب کہ بالی شاہ بڑے فخریہ انداز میں لوگوں سے نادر کا تعارف اپنے چیلے کے طور پر کرواتا۔
قدرت نے نادر کے ساتھ اگر بھیانک مذاق کیا تھا، تو اُس کے گھر والوں نے کون سا اُس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا؟ معاشرے نے اسے دھتکار دیا تھا۔ لے دے کر صرف اُس کا اپنا ایک گھر تھا، جو اُسے پناہ کا احساس دلاتا تھا، لیکن جب گھر والے بھی اُس کے ساتھ اچھوتوں جیسا سلوک کرنے لگے، تو نادر کے پاس بالی شاہ کے پاس جانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ افتخار حسین اور صغراں اپنے بیٹے کو عام لڑکوں کی طرح دیکھنا چاہتے تھے، لیکن نادر کی فطرت اُسے ان جیسا بننے نہیں دیتی تھی۔ اگرچہ یہ بات دونوں اچھی طرح سمجھتے بھی تھے، لیکن لوگوں کا تضحیک بھرا رویہ انھیں فطرت کی مخالفت پر اکساتا رہتا تھا۔ وہ اپنے بچے کو بُرا بھلا کہہ کر معاشرے کو مطمئن کرکے لوگوں کے سامنے سُرخ رو ہونا چاہتے تھے۔ چناں چہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے بچے کی فطرت کچلنے اور دبانے کی کوشش کرتے۔ آخر کار نادر نے اپنے گھر والوں کو روز روز کی شرمندگی سے بچانے کے لیے انھیں ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔
بالی شاہ کے ٹھکانے پر آج شادی کا سا سماں تھا۔ آس پاس کے علاقوں کے خواجہ سرا اس کے ٹھکانے پر جمع تھے۔ شیرمی (چائے) اور چھمک (ناچ گانے) کے دور وقفے وقفے سے چل رہے تھے۔ ایک طرف بالی شاہ خواجہ سراؤں کے دیگر گروؤں کے ساتھ بڑی شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ خوشی اس کے چہرے پر سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ آج اُس کے چیلوں میں ایک نئے چیلے کا اضافہ جو ہوا تھا، جس کی خوشی میں اُس نے آس پاس کے خواجہ سراؤں کی دعوت کا انتظام کر رکھا تھا۔ آج کی تقریب کا دولھا یا دلہن، نادر تھا، اس لیے خواجہ سراؤں نے مل کر اُسے خصوصی طور پر تیار کیا۔ سُرخ جوڑے، گہرے میک اپ اور مصنوعی زیورات سے آراستہ نادر آج سب سے الگ نظر آرہا تھا۔ اس تقریب میں نادر کو اپنے گرو بالی شاہ کی طرف سے ایک خصوصی نام ”جَیا“ عطا ہوا۔ آج کے دن نادر اپنے ماضی کی تمام چیزوں کے ساتھ اپنے والدین کا دیا ہوا نام بھی چھوڑ کر ایک نئے نام کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔
خواجہ سراؤں کی اپنی تو کوئی اولاد ہوتی نہیں، اس لیے ممتا کے مارے خواجہ سراؤں نے عمر رسیدہ بالی شاہ (گرو) کو امّی کہہ کر اُس سے ماں اور بچے (چیلا) کا رشتہ قایم کر لیا تھا۔ گُرو کا گُرو، وڈی امّی (دادی، نانی) کہلاتا اور سینیر خواجہ سرا، جونیر خواجہ سراؤں کی باجی بن گیا۔ اس طرح بالی شاہ کا یہ ”خاندان“ وجود میں آیا۔ اس خاندان میں حال ہی میں ایک نئے فرد (جیا) کا اضافہ ہوا تھا۔
اولاد چاہے گوری ہو یا کالی، لولی ہو یا لنگڑی، والدین کے لیے بہرحال اولاد ہوتی ہے۔ اسی جبر کے تحت نادر کے والدین رات کے اندھیرے میں بالی شاہ کے ٹھکانے پر جاکر نادر سے چوری چھپے ملنے پر مجبور ہوگئے۔ جیا کے نزدیک اپنے والدین کی عزت سب چیزوں سے مقدم تھی، چناں چہ نہ وہ باپ کا آخری دیدار کر سکی، نہ مُردہ ماں کے پیروں سے لپٹ کر اپنی جنت لٹ جانے کا غم منا سکی۔ وہ اپنے کفن میں لپٹے والدین کے جنازے کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جنازے کے ساتھ جانے والے عزت دار معاشرے کے معزز افراد کو یہ پتا ہی نہ چل سکا کہ جنازے کے سب سے پیچھے بال بکھرائے روتا ہوا جو خواجہ سرا چلا آ رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں بل کہ مرنے والوں کا اپنا سگا بیٹا ہے۔
وقت جیسے پر لگا کر اُڑتا رہا اور بیس سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ اس دوران جیا نے اپنے بہن بھائیوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ایک بار بھی ان کے گھر کا رُخ نہیں کیا۔ اُس کا اصل گھر اب بالی شاہ کا ٹھکانا تھا اور اس کے چیلے اس کے بہن بھائی۔ جیا نے بالی شاہ کی دن
رات خدمت کر کے اُس کے جانشین کی حیثیت حاصل کر لی۔ اُس کا شمار اب بالی شاہ کے سینیر چیلوں میں ہونے لگا تھا، اور دیگر چیلے اُسے اپنی ماں تصور کرتے تھے۔ جیا بھی انھیں اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتی اور اُن کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھتی تھی۔
معاشی مجبوریاں بسا اوقات ایسے ایسے گُل کھلاتی ہیں، جسے دیکھ کر قدرت بھی حیران رہ جاتی ہے۔ افتخار حسین اور صغراں کی وفات کے بعد جیا کے بہن بھائیوں کو معاشی پریشانیوں نے آن گھیرا۔ امجد ایم اے کرنے کے باوجود کوئی نوکری تلاش کرنے میں ناکام رہا اور پرویز کی کلرکی سے گھر کے اخراجات بہ مشکل پورے ہو رہے تھے۔ معاشی حالات نے انھیں ایک خواجہ سرا کو منہ لگانے پر مجبور کر دیا۔ والدین کی وفات کے بعد اب جیا ہی اُن کی مائی باپ تھی۔ بالی شاہ دیگر خواجہ سراؤں کے مقابلے میں ایک متمول خواجہ سرا تھا، جس نے کئی حج کر رکھے تھے۔ چناں چہ، جیا نے کبھی اپنے بھائیوں کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹایا۔ جیا جیب اور دل دونوں سے غنی تھی اور بالی شاہ کی چہیتی تھی۔
پھر ایک دن جیا اپنی سب سے بڑی متاع سے خود ہاتھ دھو بیٹھی۔ اُس کی سب سے بڑی دولت موت کے بے رحم ہاتھوں نے لوٹ لی۔ جیا کو اس کی اصل پہچان دینے والا، اُس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور حقیقی ماں باپ سے زیادہ پیار دینے والا بالی شاہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ اس بے رحم معاشرے کے ہر طعنے سے آزاد ہو کر ایک ایسی دنیا کو سدھار گیا، جہاں عزت و ذلت کا معیار جنس نہیں بل کہ اعمال تھے۔
وقت گزرتا رہا۔ امجد اور پرویز کی شادیاں ہوگئیں اور تہمینہ بھی پیا گھر سدھار گئی۔ اپنے
بہن بھائیوں کی شادیوں کے تمام تر اخراجات جیا نے خود اُٹھائے اور ایک ماں بن کر اپنی چھوٹی بہن کو رخصت کیا۔ اخراجات اُٹھانے سے جیا کو بہر حال اتنی عزت مل گئی کہ اُس کا اپنے بھائیوں کے گھر آنا جانا شروع ہوگیا۔ لیکن بالی شاہ کی وفات کے بعد چوں کہ جیا خواجہ سراؤں کی گرو بن چکی تھی، اس لیے ٹھکانے پر اُس کی ذمے داریاں بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھیں اور وہ اپنے چیلوں کو چھوڑ کر کسی اور جگہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اُس کے چیلے اُس کی اولاد تھے اور اُسے امیّ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ایک سال بعد اوپر والے نے امجد کو چاند سا بیٹا عطا کیا۔ اُس دن جیا اپنے ٹھکانے پر بد مستوں کی طرح کئی گھنٹے تک ناچتی رہی۔ اپنی امّی کو خوش ہوتا دیکھ کر اُس کے تمام چیلے بھی اُس کے ہم رقص بن گئے تھے۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امجد اور پرویز کے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس دوران تہمینہ بھی دو بیٹوں اور ایک بیٹی کی ماں بن گئی تھی۔ مشترکہ خاندان میں رہنے کی ایک پرانی خرابی نے امجد اور پرویز کے گھر اپنا ڈیرا جمالیا اور ان کے گھر کے برتن آپس میں ٹکرانے لگے۔ اگرچہ دونوں بھائیوں کی محبت اپنی جگہ برقرار رہی، لیکن اُن کی بیویوں میں جاری سرد جنگ، گرم جنگ میں تبدیل ہوگئی، جس کے باعث دونوں بھائیوں کے تعلقات بھی متاثر ہونے لگے۔ اکثر اوقات بچوں کی لڑائی بڑوں کو آپس میں لڑا دیتی۔ ایسے مواقع پر امجد اور پرویز کو پھر سے جیا کی مدد کی ضرورت پڑتی، جو اُن کی ماں جیسی تھی۔ جیا جب بھی صلح صفائی کے لیے اُن کے گھر آتی، تو اپنے بھائیوں کے بچوں کے لیے کھانے پینے کی ڈھیر ساری چیزیں اور کھلونے لاتی۔ امجد اور پرویز کے بچے بھی جیا سے بہت مانوس تھے۔ جیا کے گھر میں قدم رکھتے ہی وہ دوڑ کر اُس سے لپٹ جاتے اور جیا اُنہیں گود میں اُٹھائے ڈھیر سارا پیار کرتی اور بلائیں لینے لگتی۔ اپنی بھابھیوں کی ایک دوسرے کے خلاف بُرائیاں سنتی اور آخر میں دونوں میں صلح کروا کر اپنے ٹھکانے لوٹ آتی۔
یوں جیا کی زندگی ایک کچے مگر رنگارنگ دھاگے سے بندھی ہوئی تھی، مگر دھاگا تو ٹھہرا کچا دھاگا، سو ایک دن ٹوٹ گیا۔ اُس دن ایک اخباری رپورٹر کو جیا کا انٹرویو لینے آنا تھا۔ جیا رپورٹر کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کے موبائل فون کی گھنٹی بج اُٹھی، جس کی اسکرین پر امجد کا نام جگمگا رہا تھا۔ امجد سے گفتگو کرکے اس کے چہرے پر پریشانی نے ڈیرا جمالیا۔ آج پھر دونوں بھائیوں کی بیویوں میں جھگڑا ہوا تھا اور اس بار پرویز نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر امجد سے بد تمیزی کی تھی۔ جیا نے اپنے چیلوں کو اخباری رپورٹر کے بارے میں چند ہدایات دیں اور کچھ دیر میں آنے کا کہہ کر روانہ ہوگئی۔ راستے میں اُس نے حسب معمول بچوں کے لیے کھانے پینے کی چند چیزیں خریدیں اور دس منٹ میں اپنے بھائیوں کے گھر پہنچ گئی۔
بچّے جیا کو دیکھ کر اُس سے لپٹ گئے۔ جیا نے انہیں باری باری پیار کیا اور پرویز کی چار سالہ بیٹی رخشی کو اپنی گود میں بٹھالیا۔ آج پرویز کی بیوی کا موڈ زیادہ خراب تھا۔ جیا نے دونوں بھابھیوں کی صفائیاں سُنیں اور اُنھیں نرمی سے سمجھانے لگی۔ اس بار پرویز کی بیوی کا قصور زیادہ تھا۔ جیا نے جب اُس کی غلطی کی نشان دہی کرنا چاہی تو وہ ہتھے سے اُکھڑ گئی اور جنونی انداز میں جیا کی طرف ہاتھ اُٹھا کر چلائی، ”جا رے ہیجڑے! تو کیا ہم دونوں میں صلح صفائی کروائے گا، تیری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ تو کیا جانے اولاد کسے کہتے ہیں۔“
یہ کہتے ہوئے اُس نے جھٹکے سے جیا کی گود میں بیٹھی رخشی کو اپنی طرف کھینچ لیا۔
پرویز نے اپنی بیوی کی طرف غصّے سے دیکھتے ہوئے کہا، ”یہ تو کیا بک رہی ہے، پتا ہے تو کس سے بات کر رہی ہے۔“
”ہاں ہاں، اچھی طرح جانتی ہوں اسے، یہ ہیجڑا ہے۔ ہیجڑا بن کر رہے تو اچھا ہے، خواہ مخواہ دوسروں کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑایا کرے۔“ پرویز کا زناٹے دار تھپڑ بیوی کے منہ پر پڑا اور وہ غصّے سے پاؤں پٹختی کمرے سے باہر چلی گئی۔
جیا کے لیے ہیجڑا ہونے کا طعنہ نیا نہیں تھا۔ اُس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، دنیا والوں کے اسی قسم کے طعنے سنتی آرہی تھی۔ لیکن بے اولادی کا طعنہ اُسے آج پہلی بار اپنوں کی طرف سے ملا تھا۔ اس سے پہلے کسی غیر نے بھی اسے اس طرح کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ جیا کے اندر کوئی چیز ٹوٹ سی گئی، جسے وہ کوئی معنی نہ دے سکی۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اُٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے گھر کے صحن کو دیکھ کر نہ جانے کیوں تیس سال پرانا منظر اُس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ امجد اور پرویز اُس سے معذرت کرتے ہوئے اُس کے ساتھ ہی صحن میں چلے آئے، لیکن جیا کے کان میں تو کرکٹ کھیلتے بچوں کے شور کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ سلپ میں کھڑی تہمینہ امجد کو چلا کر جلدی گیند کرانے کا کہہ رہی تھی۔ پرویز اور امجد بولنگ کرانے کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ پھر جیا نے خود کو بلّا پکڑے دیکھا۔ نہ جانے جیا کب تک ٹکٹکی باندھے سامنے کی جانب دیکھتی رہی۔ اچانک شیشہ ٹوٹنے کی زور دار آواز اُسے خیالی دنیا سے حقیقی دنیا میں کھینچ لائی۔ جیا نے بے ساختہ دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے۔ کرچی کی برسوں پرانی چبھن پھر سے تکلیف دینے لگی۔
وہ نہ جانے کب اور کیسے اپنے ٹھکانے پر واپس لوٹی۔ کمرے میں قدم رکھا تو اخباری نمایندے اور اُس کے ساتھی فوٹو گرافر کو اپنا منتظر پایا۔ جیا نے سر کو جھٹکا، چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور کمرے میں داخل ہو کر اخباری رپورٹر سے انتظار کرانے پر معذرت کرنے لگی۔ انٹرویو شروع ہوا۔ جیا پرسکون انداز میں ہر سوال کا جواب دیتی رہی۔ اس کے چیلے اس دوران خاموشی اور توجہ کے ساتھ اپنی ماں کو انٹرویو دیتے سنتے رہے۔ کوئی بھی شخص اُس وقت جیا کے دل کی کیفیات کو اُس کے چہرے پر محسوس نہیں کر سکتا تھا۔
اخباری رپورٹر نے اپنا آخری سوال کیا، ”یہ تاثر عام ہے کہ خواجہ سرا ناچے گائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیا آپ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں خوشی سے ناچتے گاتے ہیں؟“
نہ جانے کیوں جیا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کچھ جذباتی سی ہوگئی، ”بھیّا! خوشی سے انسان صرف اپنوں کی شادی میں ناچتا گاتا ہے، بیگانوں کی شادی میں مجبوری میں ناچنا پڑتا ہے۔ پیٹ ہمیں ناچنے پر مجبور کرتا ہے۔ لوگوں کو تو صرف ناچتا ہوا خواجہ سرا دکھائی دیتا ہے، لیکن ناچتے وقت اس کے دل میں جو مناظر طلوع اور غروب ہوتے ہیں، ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ ایک منظر میں اُس کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے۔ وہ ناچتے ہوئے سوچتا ہے کہ جوانی ڈھل گئی تو اُسے کون ناچنے کو کہے گا۔ اگر وہ ناچے گا نہیں تو اُسے پیسے کون دے گا۔ سامنے بیٹھے دُولھا کو دیکھ کر ایک اور منظر پہلے منظر کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس منظر میں وہ خود کو دوُلھا کی جگہ بیٹھا محسوس کرتا ہے۔ دُلہن کو دیکھ کر دُولھا بننے کا منظر دھندلا جاتا ہے اور وہ تصور میں خود کو دُلہن بنے دیکھ رہا ہوتا ہے۔“
جیا نے اخباری رپورٹر کے مختصر سوال کا طویل جواب دے کر چائے کا آخری گھونٹ بھی اپنے حلق سے نیچے اُتارا اور سگریٹ سُلگا کر سلگتے ہوئے لہجے میں اُلٹا اُس سے سوال کر ڈالا، ”کیا لوگ ہمیں نچوائے بغیر پیسے نہیں دے سکتے۔“ پھر خود کلامی کے انداز میں کہنے لگی، ”ہمیں لوگوں نے انسان ہی کب سمجھا ہے۔ کسی کے لڑائی جھگڑے میں صلح کروانے جاؤ تو یہ طعنہ سُننے کو ملتا ہے، جا رے جا! تُو تو ہیجڑا ہے، تجھے کیا فکر، تیری تو کوئی اولاد ہی نہیں۔“
اپنی بات کے اختتام پر جیا نے تالی پیٹی اور زور سے قہقہہ لگا کر کمرے میں بیٹھی اپنی اولادوں (چیلوں) کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی، جو اُس کی بات سن کر کچھ افسردہ سی ہوگئی تھیں۔ جیا کے چہرے پر اُس وقت ایک ممتا بھرا تقّدس اُبھرنے لگا، جس کے سامنے ساری دنیا کی ممتا ہیچ محسوس ہو رہی تھی۔
(افسانہ نگار: شفیع موسیٰ منصوری)