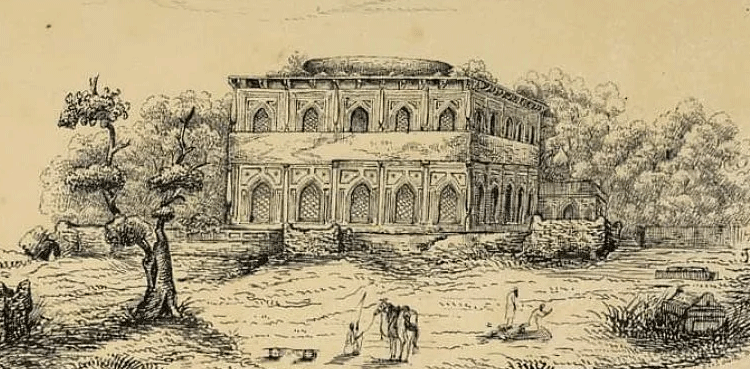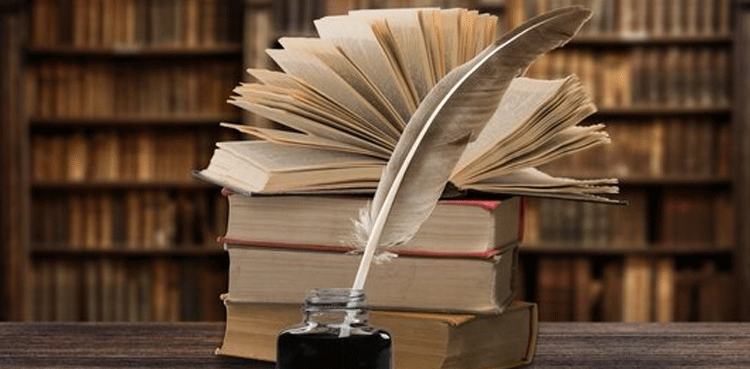ہندوستان کی سیاسی اور ثقافتی تاریخ میں 1857ء ایک سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی نے اس کو شورش قرار دیا تو کسی نے غدر اور فوجی بغاوت سے تعبیر کیا۔ ملک کی آزادی کے بعد سے 1857ء کو آزادی کی پہلی جنگ یا قومی تحریک کے عنوان سے پکارا جاتا ہے۔ غرض کہ ڈیڑھ سو سال قبل 9 مئی 1857ء کو جو فوجی بغاوت میرٹھ سے شروع ہوئی وہ انقلاب کا پہلا نقیب اور جنگِ آزادی کی پہلی آواز تھا۔
تاریخ اور ادب سے متعلق مزید تحریریں پڑھیں
ملکی اور غیر ملکی مؤرخ 1857ء کی بغاوت کی ماہیت کے بارے میں جتنی بھی بحث کریں لیکن ہندوستان کے عوام یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ میرٹھ کی یہ بغاوت ہماری قومی تحریک کا سر چشمہ ہے۔
خود فیلڈ مارشل لارڈ رابرٹس نے تسلیم کیا ہے کہ ’’حکومتِ ہند کے سرکاری کاغذات میں مسٹر فارسٹ کی تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ کارتوسوں کی تیاری میں جو روغنی محلول استعمال کیا گیا تھا، واقعی وہ قابلِ اعتراض اجزاء یعنی گائے اور سؤر کی چربی سے مرکب تھا اور ان کارتوسوں کی ساخت میں فوجیوں کے مذہبی تعصبات اور جذبات کی مطلق پروا نہیں کی گئی۔
1857ء کے اس خونیں انقلاب میں میرٹھ کے 85 بہادر سپاہیوں نے پوری دنیا کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ ہندو مسلم اتحاد، جذبۂ ایثار، مادرِ وطن کی خاطر مذہبی اتحاد اور رواداری کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ گائے کا گوشت کھانے والے اور گائے کی پوجا کرنے والے، لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان اور منتروں کا جاپ کرنے والے ہندوؤں نے مل کر بغاوت کی۔
میرٹھ چھاؤنی سے جو بھی سپاہی ملک کے کسی حصہ کی طرف کوچ کرتا تھا وہ نعرہ لگاتا ہوا کہتا تھا کہ ’’ بھائیو! ہندو اور مسلمانو!! انگریزوں کو اپنے ملک سے باہر کرو۔‘‘ انقلابیوں کے اس حقارت آمیز نعرے میں تین الفاظ اہمیت کے حامل ہوا کرتے تھے یعنی ’’ہندو اور مسلمان ‘‘۔ ان تین الفاظ میں اس بات کی تلقین کی جا رہی تھی کہ ہندو اور مسلمان مل کر یہ قومی جنگ لڑیں کیونکہ اس کے بغیر غلامی سے نجات نہیں ہو سکتی۔ اس اعلان کے بعد پورے ہندوستان میں انقلاب کی لہر دوڑ گئی۔
میرٹھ کے فوجیوں میں انقلاب کی روح پھونکنے والا شخص عبداللہ بیگ نام کا ایک بر طرف فوجی افسر تھا جس نے اپنے ہم وطن فوجی ساتھیوں سے کہا تھا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جو کارتوس تمہیں دیے جا رہے ہیں ان میں سؤر اور گائے کی چربی لگی ہوئی ہے اور سرکار تمہاری ذات بگاڑنے کی خواہش مند ہے۔ میرٹھ فوج کے دو مسلم سپاہی شیخ پیر علی نائک اور قدرت علی نے سب سے پہلے 23 اپریل 1857ء کی رات کو ملٹری میس میں ایک خفیہ میٹنگ کی اور اسی وقت ہندو اور مسلم فوجیوں نے مقدس گنگا اور قرآن شریف کی قسمیں کھا کر حلف لیا کہ وہ اس کارتوس کا استعمال نہیں کریں گے۔ 24 اپریل 1857ء کو فوجی پریڈ گراؤنڈ پر نوے فوجیوں میں سے 85 فوجیوں نے جن میں سے اڑتالیس مسلمان اور37 ہندو تھے کمپنی کمانڈر کرنل اسمتھ (Smyth) کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ چربی والے کارتوس اس وقت تک استعمال نہیں کریں گے جب تک کہ وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہو جاتے۔ چنانچہ ایک فوجی عدالت میں ان سپاہیوں کو پیش کیا گیا اور جابر فوجی عدالت نے تمام سپاہیوں کو دس سال قید با مشقت کی سزا سنائی۔ سپاہیوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جو جنرل ہیوٹ (Hewitt) نے مسترد کر دی۔
9 مئی 1857ء کو ہندوستانی رسالے کی پلٹن کو میدان میں آنے کا حکم دیا گیا۔ چاروں طرف توپ اور گورا فوج تیار کھڑی تھی۔ پچاسی سپاہیوں کو ننگے پاؤں پریڈ کراتے ہوئے میدان میں لایا گیا اور چار سپاہیوں کو وہیں گولی کا نشانہ بنا دیا گیا اور بقیہ اکیاسی سپاہیوں کی وردیاں پھاڑ کر اتار دی گئیں، فوجی میڈل نوچ لئے گئے اور وہاں پہلے سے موجود لوہاروں سے ان باغی سپاہیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔
جو سپاہی پلٹن میدان سے واپس آ گئے تھے ان میں نفرت اور غصہ پھوٹ رہا تھا اور انہوں نے 10 مئی کو اتوار کے دن جب سبھی انگریز فوجی افسر گرجا گھر میں اتوار کی عبادت کے لئے جمع ہو رہے تھے کہ یکایک چند جوشیلے نوجوانوں نے مشتعل ہو کر ہندوستانی سپاہیوں کی بیرکوں میں آگ لگا کر آزادی کی جد و جہد کا اعلان کر دیا۔ کرنل فینس (Finnis) سب سے پہلے ان انقلابی سپاہیوں کی گولی کا نشانہ بنے۔ اس کے بعد نو اور انگریزوں کو قتل کر دیا گیا جن کی قبریں آج بھی میرٹھ۔ رڑکی روڈ پر واقع سینٹ جونس سیمٹری میں اس تاریخی واقعہ کی یاد دلاتی ہیں۔ حالانکہ بہت سے مؤرخین نے ہزاروں انگریزوں کے قتلِ عام کا حوالہ دیا ہے مگر میرٹھ کے قدیمی مسیحی قبرستان میں صرف دس قبریں ہیں جو دس مئی کے واقعہ کی خاموش گواہ ہیں۔
ان انقلابی فوجیوں میں جوش و جذبہ پیدا کرنے میں میرٹھ کے صدر بازار کی چار طوائف صوفیہ، مہری، زینت اور گلاب کو بھی بہت دخل ہے۔ ان فوجیوں کو ان طوائفوں نے ہی وطن پرستی کے لئے للکارا تھا اور اس طرح 1806ء میں قائم میرٹھ کی فوجی چھاؤنی دیکھتے دیکھتے ہی انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گئی۔
ظہیر دہلوی لکھتے ہیں کہ ان عورتوں نے لعن و طعن و تشنیع سے پنکھا جھل جھل کر نارِ فتنہ و فساد کو بھڑکانا شروع کیا اور ان کی چرب زبانی آتشِ فساد پر روغن کا کام کر گئی۔ ان عورات نے مردوں کو طعنے دینے شروع کیے کہ تم لوگ مرد ہو اور سپاہی گری کا دعویٰ کرتے ہو مگر نہایت بزدل بے عزت اور بے شرم ہو۔ تم سے تو ہم عورتیں اچھی ہیں تم کو شرم نہیں کہ تمہارے سامنے افسروں کے ہتھکڑیاں، بیڑیاں پڑ گئیں مگر تم کھڑے دیکھا کئے اور تم سے کچھ نہ ہو سکا۔ یہ چوڑیاں تو تم پہن لو اور ہتھیار ہم کو دے دو ہم افسروں کو چھڑا کر لاتی ہیں۔ ان کلمات نے اشتعال طبع پیدا کیا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ مردانگی کی آگ بھڑک اٹھی اور مرنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ میرٹھ کے اس واقعہ نے عام بغاوت کی کیفیت پیدا کر دی تھی اور آگ کی طرح یہ خبریں پھیل گئیں تھیں۔ میرٹھ چھاؤنی کی اس چنگاری نے دیکھتے ہی دیکھتے شعلۂ جوالہ بن کر پورے برِ صغیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
اسی دوران انقلابیوں نے میرٹھ سینٹرل جیل کے دروازے توڑ دیے، کھڑکیاں اکھاڑ پھینکیں اور ایک دن پہلے جیل میں قید اپنے ساتھیوں کو آزاد کرا لیا۔ ان کے ساتھ تقریباً بارہ سو قیدی بھی جیل سے نکل بھاگے۔ بعض قیدی ہتھکڑی اور بیڑی لگے ہوئے وہاں سے چل دیے اور عبداللہ پور، بھاون پور، سیال، مبارک پور ہوتے ہوئے مان پور پہونچے جہاں کسی نے انگریزوں کے ڈر کی وجہ سے ان کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کاٹنے کی ہمت نہیں کی۔ وہاں مان پور گاؤں کے ایک لوہار مہراب خاں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان قیدیوں کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کاٹ ڈالیں اور ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو کنویں میں ڈال دیا۔
میرٹھ کے عالم مولانا سید عالم علی اور ان کے بھائی سید شبیر علی جو صاحبِ کشف بزرگ تھے، دل کھول کر ان باغی سپاہیوں کی مدد کی۔ شاہ پیر دروازے سے نوچندی کے میدان تک ہزاروں جوان سر بکف آتشِ سوزاں بنے ہوئے نبرد آزما دکھائی دے رہے تھے۔ یکایک کپتان ڈریک اسلحہ سے لیس ایک فوجی دستہ لئے ہاپوڑ روڈ پر نمودار ہوا اور ہجوم پر فائرنگ کر دی۔ یہاں زبردست قتلِ عام ہوا۔ 11 مئی1857ء کو بائیس حریت پسندوں کو نوچندی کے میدان میں پھانسی دے دی گئی جن میں سید عالم اور سید شبیر علی صاحبان بھی شامل تھے۔ شہر کے باشندے یہ خبر سن کر بھڑک اٹھے اور اسی دن سرکاری دفاتر کو نذر آتش کر دیا۔ انتظامیہ مفلوج ہو گئی۔ ہر طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور دھوئیں سے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔
میرٹھ کے ممتاز شاعر مولانا اسمٰعیل میرٹھی جو خود اس ہنگامے کے عینی گواہ تھے ان کے بیٹے محمد اسلم سیفی اپنے والد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ’’ دس مئی 1857ء کا واقعہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی 14تاریخ اس دن تھی۔ پڑوس میں دعوت روزہ افطار کی تھی۔ مولانا اور دیگر اعزا اس میں شریک تھے۔ یکایک ہولناک شور و غل کی آوازیں بلند ہوئیں۔
معلوم ہوا کہ جیل خانہ توڑ دیا گیا ہے اور قیدی بھاگ رہے ہیں۔ لوہار ان کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کاٹنے میں مصروف ہیں۔ شہر کے لوگ سراسیمہ ہر طرف رواں دواں نظر آ رہے تھے۔ کثیر التعداد آدمی جیل خانہ کی سمت دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ مولانا کے قلب پر اس ہنگامہ کا بہت گہرا اثر ہوا۔ اس عظیم الشان ہنگامۂ دار و گیر کا تلاطم۔ دہلی کی تباہی کا نقشہ، اہلِ دہلی کا حالِ پریشان، ان باتوں نے مولانا کے دل و دماغ پر بچپن ہی میں ایسا گہرا اثر بٹھایا کہ آئندہ زندگی میں فلاح و بہبود و خلائق کے لئے بلا لحاظ دین و ملت یا ذات پات مصروفِ کار رہے۔‘‘ مولانا اسماعیل میرٹھی کے دل میں بھی آزادی کی تڑپ پیدا ہوئی جس کا اظہار انہوں نے اس طرح کیا ہے۔
ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر
ہے وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر
جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بے ضرر ہو
بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو
(برصغیر کی تاریخ پر مبنی تحقیقی کتاب "میرٹھ اور1857ء” سے اقتباس، تالیف و تدوین ڈاکٹر راحت ابرار)