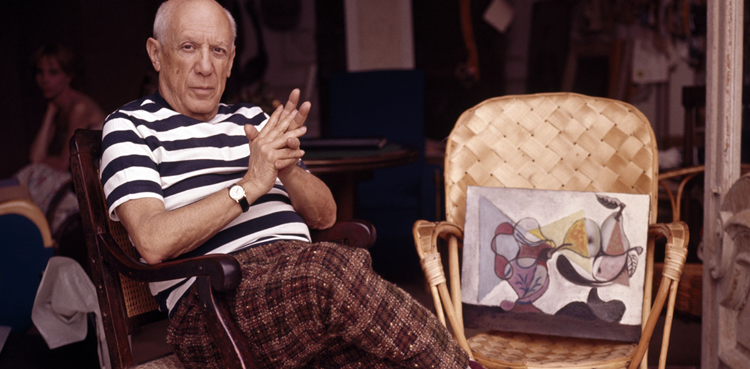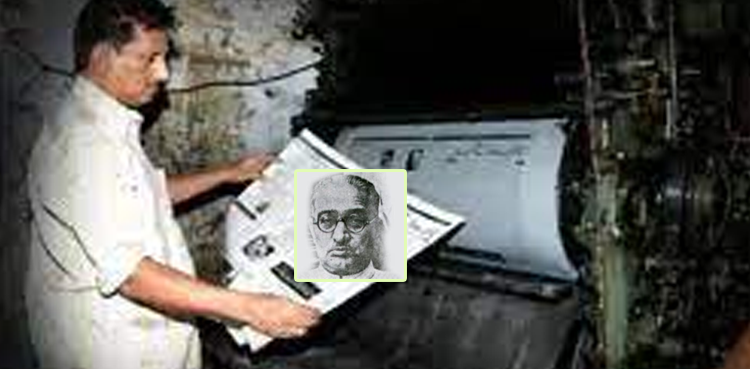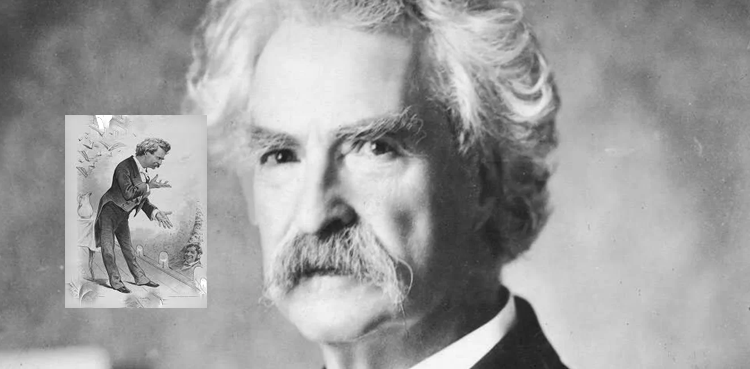فسادی مزاج لوگوں کے جھگڑے کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ کوئی رُو بہ رُو، دُو بہ دُو اور تُو تڑاخ کر کے تسکین پاتا ہے تو کوئی غائبانہ فساد ڈالنے میں مہارت رکھتا ہے۔
زمانے کے ارتقا کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سوچ اور رویوں میں بھی تبدیلی رونما ہو گئی۔ وہ جو کبھی ”گھر کی بات گھر میں رہے“ کے آرزومند ہُوا کرتے تھے اب دل کی بات بھی دل میں نہیں رکھ پاتے۔ یوں گھر کی بات گھر گھر پھیلتی ہے۔
آج دنیا بھر میں سماجی رابطے کا سب سے بڑا اور مقبول ذریعہ واٹس ایپ ہے جس کا اس حوالے سے فعال کردار نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ جب سے واٹس ایپ پر فیملی گروپ کا رواج پڑا اور بڑھا ہے، انفرادی اور خاندانی جھگڑے یہیں نمٹائے جارہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک ہی گھر کے مکینوں کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے یہی فیملی گروپ مؤثر اور کارآمد معلوم ہوتے ہیں۔
ہم نے اہتمام کیا کہ خیر النساء کے ”برسوں کے تجربات“، اُن کی بڑی بہو تابندہ کے”صبح تڑکے دل لگتی باتیں“ چھوٹی بہو فراست کے ”آج کی سوغات“ اور خیر النساء کے بھائی نصیر کے”امن کی پُکار“ نامی گروپوں کے اسٹیٹس پر لگائی جانے والی گفتگو آپ کی نذر کریں۔
٭تابندہ٭ ”صبح تڑکے دل لگتی باتیں“: محبت کیجیے، محبت بانٹیے، محبت پائیے۔
٭فراست٭ ”آج کی سوغات‘‘: محبت کی تقسیم پر اپنے پرائے سب کا یکساں حق ہے۔
٭خیرالنساء٭ ”برسوں کے تجربات“: اتفاق میں برکت ہے۔
لیکن پھر ہُوا یوں کہ تابندہ کے اسٹیٹس ”صبح سویرے دل پہ بیتی باتیں“ کے عنوان سے لگنے لگے۔ اب تابندہ دل کو چُھو لینے والے پیغامات کے بجائے دل پر بیتنے والی باتیں پیغامات کی صورت شیئر کر رہی تھیں، وہ بھی ایسے جو پڑھنے والوں کو چونکا دیتے تو فراست کے دل میں کانٹے بن کر چبھتے۔ کیونکہ وہ خوب جانتی تھیں کہ یہ پیغامات کس کے لیے ہیں لیکن چپ رہتیں۔ آخر کب تک؟ ایک دن تابندہ کا اسٹیٹس پڑھ کر فراست نے اپنی خاموشی توڑی اور ”نہلے پہ دہلا“ کے عنوان سے اسٹیٹس لگانے شروع کر دیے۔ ان بے لاگ اسٹیٹس کی وجہ سے دیورانی جیٹھانی میں بُری طرح ٹھن گئی۔ تابندہ کے سیر پر سوا سیر کا بٹہ مارنا فراست نے اپنا معمول بنا لیا۔
٭تابندہ٭ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔
٭فراست٭ معلوم نہیں کیوں لوگوں کو اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔
٭تابندہ٭ سو باتوں کی ایک بات۔ کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا۔
فراست٭ کمی نہیں ایسے لوگوں کی جو من بھاتا کھاتے ہیں سو کھاتے ہیں، مانگا تانگا بھی کھانے سے نہیں ہچکچاتے۔
٭تابندہ٭ تجھ کو پڑائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تُو۔
فراست٭ آدھا تیتر، آدھا بٹیر، ہنسی روکوں تو کیسے روکوں۔
٭تابندہ٭ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کردے
٭فراست٭ منہ اچھا نہ ہو نہ سہی۔ منہ سے نکلے بھلی بات کوئی
٭خیرالنساء٭ ”برسوں کے تجربات“: درگزر سے کام لو، دل صاف کرو، مل کر رہو، خوش رہو، لوگوں کے لیے مثال بنو۔
٭تابندہ٭ بات ہے پتے کی
٭فراست٭ عمل کی نوبت آئے تب۔ ورنہ؟
٭خیرالنساء٭ وہ نوبت بجے گی کہ دنیا دیکھے گی۔
٭فراست٭ دل میں چھپا ارمان تو یہی ہے لوگوں کے۔
٭خیرالنساء٭ کھانا پکائیں، اُبلا سُبلا اُبالا سُبالا، باتیں بگھاریں لذّت بھری۔
اپنی ساس کے اسٹیٹس کے جواب میں فراست نے ”زندگی عذاب ٹرانسمیشن“ کے عنوان سے ساس کے برہمی کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے بیان جاری کیا۔
٭فراست٭ صبح ناشتہ مع طعنہ۔ ظہرانہ دل جلانا۔ ہائے ہائے اور عصرانہ جاری ہُوا شکایت نامہ سنگ عشائیہ۔
فراست کے اسٹیٹس نے تابندہ کے دل میں گلاب کھلا دیے۔ دیورانی سے شدید اختلافات کے باوجود فوری دل، ستارے اور پھول بھیج کر بھر پور داد دی، اس بیان کے ساتھ کہ بہو وہی اچھی جو ساس نامی بھڑ کے جتھے کو نہ چھیڑے ورنہ…..؟
٭فراست٭ انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی کیونکہ اس بھڑ کے جتھے میں ساس کی بد ذاتی کیفیات ذاتی رویوں کے ساتھ آپ کو ہلا کر رکھ دیں گی۔
بہوؤں کے کاری واروں نے خیرالنساء کو اسٹیٹس کے نئے عنوان ”ساس کی للکار“ کے ہمراہ آنے پر مجبور کر دیا۔
٭خیرالنساء٭ طعنے بہوؤں کے سنوں اور کچھ بھی نہ کہوں
ائی بہوؤں میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں
٭فراست٭ نہ، نہ، نہ خاموش؟ ہر گز نہیں۔ خاموش رہ کر سینے پر مونگ دلنے سے بہتر ہے کہ بول کر بھڑاس نکال لی جائے۔
٭تابندہ٭ سکوتِ شہرِ سخن میں وہ آگ سا لہجہ
سماعتوں کی فضا نار نار کر دے گا
٭خیرالنساء٭ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔
٭فراست٭ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے
٭تابندہ٭ دن بھر دل جلاتے رہنے والے تہذیب کے دیے جلاتے بھلے نہیں لگتے۔
٭خیرالنساء٭ اولاد کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔
٭فراست٭ اور بہو کی ساس بنتے ہی ماں اس تربیت گاہ کے پرخچے اُڑا دیتی ہے اور اولاد کو تتر بتر کر دیتی ہے۔
٭تابندہ٭ بڑے جب چھوٹوں سے بڑھ کر چھوٹے بن جائیں تب ایسا ہی ہوتا ہے۔
٭خیرالنساء٭ جس کا جتنا ظرف ہے اُتنا ہی وہ خاموش ہے۔
٭فراست٭ دریا میں کنکر مارنے والے کریں سمندر کے سکوت کا تذکرہ۔ واہ بھئی
٭تابندہ٭ بیٹا اگر محبت سے شریکِ حیات کو تحفہ دے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے نہ کہ آگ بگولہ ہوں۔
٭فراست٭ داماد بیٹی کو تحفہ دے تو نگاہوں تک سے بیٹی کی آرتی اُتار لی جاتی ہے اور………
٭تابندہ٭ خالی جگہ پُر کریں۔
٭فراست٭ بیٹا بہو کو مسکرا کر بھی دیکھ لے تو لفظوں کے تیروں سے بہو کا کلیجہ چھلنی کر دیں۔
٭خیرالنساء٭ جلنے والے اپنی ہی آگ میں بھسم ہو جاتے ہیں۔
٭تابندہ٭ لے ساس بھی شائستہ کہ ظالم ہے بہت کام
آفات کی اس پُڑیا کی تیشہ گری کا
٭فراست٭ چار دن ساس کے تو چار دن بہو کے۔
جب اسٹیٹس کی جنگ کے شعلے زیادہ شدت سے بلند ہونے لگے تو خیرالنساء کے ہر دلعزیز اور صلح جُو بھائی نصیر کا اسٹیٹس ”امن کی پکار“کے نام سے آگیا۔
٭نصیر٭ نہ وہ بہوؤں میں لحاظ رہا
نہ شرم ہے ساس کی زبان میں
اپنی عزت اپنے ہی ہاتھوں اُچھالنے والوں کو اب سنبھل جانا چاہیے۔
٭فراست٭ نیک قدم بڑے اُٹھائیں گے تو چھوٹے وہی راہ اختیار کریں گے۔
٭تابندہ٭ لیکن جب بڑے بچوں کو بھی مات دے دیں تب یہ ناممکن ہے۔
٭خیرالنساء٭ شعلوں کو ہوا دینے والے کیسے آگ بجھا سکتے ہیں؟
٭نصیر٭ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں
٭فراست٭ ستائش بیٹیوں کے لیے اور آزمائش بہوؤں کے لیے ہو تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی جاتا ہے۔
٭تابندہ٭ اور جب چھلکتا ہے تو کیسا ادب؟ کیسی محبت؟
٭خیرالنساء٭ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔
٭نصیر٭ جتنا بات کو بڑھائیں بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔
٭تابندہ٭ بعض لوگوں پر اپنے نام کا اثر ہی نہیں ہوتا۔
٭فراست٭ ہو بھی کیسے جب دل میں شر کے شرارے اور دماغ میں بدی کا طوفا ن اُٹھ رہا ہو۔
٭خیرالنساء٭ خیر و شر کی جنگ میں فتح ہمیشہ خیر کی ہوتی ہے۔
٭نصیر٭ معافی سے بڑا انتقام اور کوئی نہیں۔
٭خیرالنساء٭ بڑوں ہی کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔
٭تابندہ٭ جب بڑے آغاز کریں تو چھوٹے بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں۔
٭فراست٭ اور چھوٹوں کا کام ہی بڑوں کی تقلید ہے۔ جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے۔
٭نصیر٭ بقول رابرٹ بینلن ”محبت تب ہوتی ہے جب کسی کی خوشی آپ کی خوشی کے لیے لازمی شرط ہو۔“
٭خیرالنساء٭ محبت میں اخلاص اور دوستی بھی شامل ہو تو محبت کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ اور میں اسی احساس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہوں۔
٭تابندہ٭ اگر ایسا ہے تو آج ہی سے ”ساس ہے میری سہیلی۔“
٭فراست٭ دوستی ایسا ناتا جو سونے سے بھی مہنگا۔
٭نصیر٭ محبت کے دیے جلا لو، وفا کے گیت گنگنا لو تقاضہ ہے یہ زندگی کا۔
٭خیرالنساء٭ مسکراتا رہے آشیانہ۔
(کثیرالاشاعت روزناموں میں شائستہ زریں کی مفید اور بامقصد تحریریں، افسانے اور سروے رپورٹیں شایع ہوتی رہتی ہیں، انھوں نے ریڈیو کے لیے سنجیدہ اور شگفتہ تحریروں کے ساتھ کئی فیچر اسٹوریز بھی لکھی ہیں)