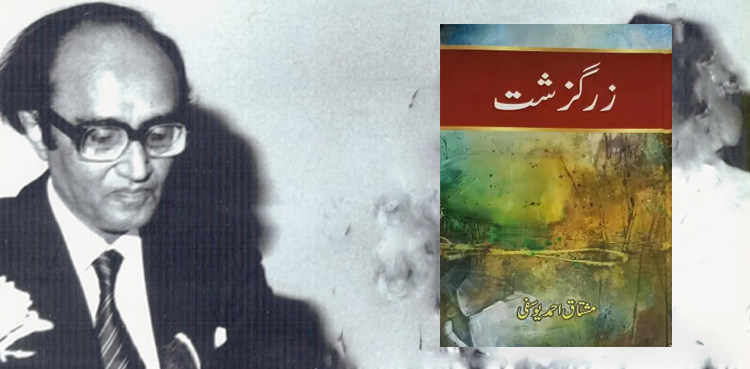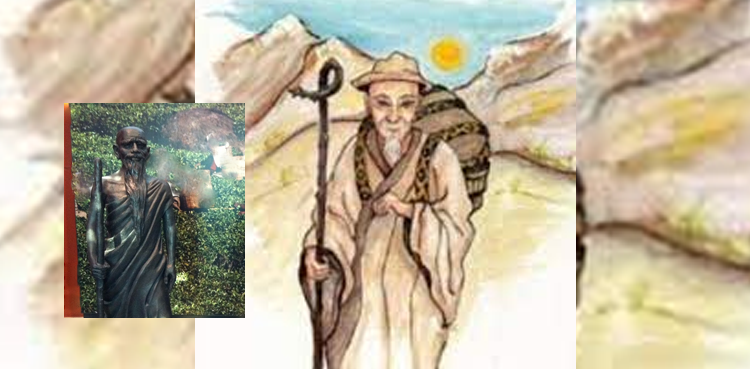اس سال علم و ادب کی دنیا میں جہاں کتابوں کی اشاعت، تقاریب کا سلسلہ جاری رہا وہیں ادبی میلے بھی سجائے گئے، اور اہلِ قلم نے متاثر کن تخلیقات پر ایوارڈ اپنے نام کرکے عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کی۔
آئیے، دنیا بھر میں زبان و ادب کے فروغ کی کاوشوں اور اہلِ قلم کی سرگرمیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
ادب کا نوبیل انعام
شروع کرتے ہیں ادب کے نوبیل انعام سے جس کی فاتح کا نام 6 اکتوبر کو سامنے آیا۔ اس سال نوبیل کی قطار میں کینیا کے نگوگی وا تھیونگو، کینیڈا کی شاعرہ این کارسن، فرانس کے مائیکل ہولی بیک شامل تھے، اس ادیب نے 1998 کے اپنے ناول ‘ایٹمائزڈ’ پر عالمی سطح پر پہچان حاصل کی تھی۔ اسی فہرست میں فرانسیسی مصنفہ اینی ارنو (Annie Ernaux) بھی شامل تھیں۔ وہ اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب کے طفیل نوبیل انعام کی دوڑ میں شامل ہوئی تھیں۔ یہ وہ سوانحی تصنیف ہے جس میں خاتون کی حیثیت سے اینی ارنو نے سماجی عدم مساوات کی جھلک پیش کی ہے۔ اکیڈمی نے انھیں نوبیل انعام کا حق دار قرار دیا اور ان کی کتاب ’’جرات اور کلینیکل تیز رفتاری‘‘ کو سراہا۔ اس سال کی نوبیل انعام یافتہ اینی ارنو کی عمر 82 برس ہے۔
سویڈش اکیڈمی نے اس انعام کے لیے مصنفہ کے انتخاب کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ارنو مسلسل اور مختلف زاویوں سے ایک ایسی زندگی کا جائزہ لیتی ہیں جس میں صنف، زبان اور طبقے کے حوالے سے سخت تفاوت پایا جاتا ہے۔
وہ 22 ناولوں کی مصنف ہیں۔ ان کے ناول طبقات سماج اور صنف کے ذاتی تجربے پر مبنی ہیں۔ اینی ارنو ادب کا نوبل انعام جیتنے والی پہلی فرانسیسی خاتون ہیں جنھوں نے ایک انٹرویو کے دوران اپنے جذبات کا اظہار کچھ اس طرح کیا:’’میں بہت حیران ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک مصنفہ کے طور پر اس اعزاز سے نوازا جائے گا۔‘‘
اینی ارنو کا پہلا ناول’’لیس آرموائرس وائڈز‘‘1974 میں شائع ہواتھا۔ 2008 میں ان کی دنیا بھر میں پہچان جس ناول کے سبب بنی وہ تھا ’’لیس اینیس۔‘‘ 2017 میں اس کا ترجمہ شائع ہوا تھا۔
ارنو کا ایک ناول سنہ 2000 میں شائع ہوا تھا جس کا نام’ہیپننگ‘ تھا۔ یہ 1960ء کی دہائی میں فرانس میں اسقاط حمل کو غیر قانونی قراردینے اور اس دوران مصنفہ کے اسقاط حمل کے ایک تجربے پر مبنی ہے۔ اس پر بنائی گئی فلم نے 2021 میں وینس فلمی میلے میں انعام جیتا تھا۔
شمالی فرانس کے نارمنڈی کے ایک دیہی علاقے میں اینی ارنو نے 1940 میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد ایک اسٹور اور کیفے کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنی تصانیف میں بتایا کہ کس طرح اپنے محنت کش طبقے کے پس منظر کے ساتھ وہ فرانسیسی طبقاتی ںظام کے ضابطوں اور عادات کو اپنانے کے لیے جدوجہد کرتی ہوئی بڑی ہوئیں۔
فکشن کا بکر پرائز
فکشن کی دنیا میں ‘بکر پرائز’ ایک معتبر انعام ہے جو رواں برس سری لنکن ادیب کے نام ہوا۔ شیہان کرونا تیلاکا کو ان کے سیاسی طنزیہ ناول بعنوان ’مالی المیدا کے سات چاند‘ پر یہ انعام دیا گیا۔ یہ سری لنکا کی طویل خانہ جنگی کے موضوع پر تصنیف کردہ ہے۔
17 اکتوبر کی شام لندن میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں بکر پرائز وصول کرتے ہوئے مصنف نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ ان کا یہ ناول سری لنکا میں بھی پڑھا جائے گا، ”ایک ایسا ملک جو اپنی کہانیوں سے سیکھتا بھی ہے۔‘‘
یہ ناول سری لنکا میں 1990ء کی دہائی کے حالات کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔ یہ ایک ایسے فوٹو گرافر کے بارے میں ہے، جو ملک میں جاری خانہ جنگی کے دوران ایک صبح جاگتا ہے تو مر چکا ہوتا ہے۔ 47 سالہ شیہان کرونا تیلاکا یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے دوسرے سری لنکن ہیں، اس سے پہلے 1992 میں سری لنکن ادیب مائیکل اونداجے کو ان کی تصنیف ‘دی انگلش پیشنٹ’ پر بکر پرائز دیا گیا تھا۔
بکر پرائز کی جیوری کے سربراہ کا کہنا تھا کہ کرونا تیلاکا کا یہ ناول ایک ”مابعد الطبیعیاتی تھرلر ہے، جو بعد از حیات کی تاریکی کا اس طرح احاطہ کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف تخلیقی ادب کی مختلف اقسام کی حدود بلکہ زندگی اور موت، جسم اور روح حتیٰ کہ مشرق و مغرب کے درمیان سرحدیں بھی تحلیل ہوتی جاتی ہیں۔‘‘
کرونا تیلاکا کی یہ کتاب برطانیہ کے Sort of Books نامی ایک آزاد اشاعتی ادارے نے شائع کی ہے۔ شیہان کرونا تیلاکا 1975ء میں جنوب مغربی سری لنکا کے شہر گالے میں پیدا ہوئے۔ دارالحکومت کولمبو میں رہتے ہوئے انھوں نے قلم کار کی حیثیت سے کئی بین الاقوامی جرائد اور رسائل کے لیے لکھا۔ انھیں بین الاقوامی سطح پر 2011ء میں ان کے ناول ‘چائنا مین‘ کی وجہ سے شہرت ملی تھی۔
2022ء میں بکر پرائز کے لیے جن دیگر ادیبوں کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے تھے، ان میں برطانیہ کے ایلن گارنر، زمبابوے کی نووائلٹ بولاوائیو اور امریکی مصنف پیرسیوال ایویرٹ بھی شامل تھے۔
بکر پرائز کا سلسلہ 1968ء میں شروع ہوا تھا اور فکشن کا یہ انعام انگریزی زبان میں اس کتاب پر دیا جاتا ہے جو برطانیہ میں شائع ہوئی ہو۔ انعام یافتہ کتاب کے مصنّف کو 50 ہزار پاؤنڈ کی رقم دی جاتی ہے۔
عالمی بکر پرائز
اس برس انٹرنیشنل بکر پرائز کی فاتح بھارتی ادیبہ گیتانجلی شری رہیں۔ انھیں ہندی زبان میں لکھے گئے ناول ‘ریت سمادھی‘ پر یہ انعام دیا گیا ہے۔ اس اعزاز کے لیے گیتانجلی شری سمیت پانچ مصنفین کو شارٹ لسٹ کیا گیا تھا اور وہ سب کی سب خواتین تھیں۔ انٹرنیشنل بکر پرائز ایسی ادبی تخلیقات پر دیا جاتا ہے، جن کے انگریزی زبان سمیت بین الاقوامی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہوں۔ ‘ریت سمادھی‘ ہندی زبان کا پہلا ناول ہے جس کا ترجمہ ناول کو اس انعام کی تیار کی گئی فہرست تک لے آیا۔ ڈیزی راک ویل وہ مترجم ہیں جنھوں نے ریت سمادھی کو انگریزی میں ‘ٹومب آف سینڈز‘ کے نام سے منتقل کیا۔
2016ء میں انٹرنیشنل بکر پرائز کے ضوابط میں چند بنیادی تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ یہ ایوارڈ سالانہ اور مجموعی کام کے بجائے ایک کتاب تک محدود کر دیا گیا۔ اب ضروری تھا کہ کتاب کی اصل زبان انگریزی نہ ہو، بلکہ یہ کسی بھی دوسری زبان سے انگریزی میں منتقل شدہ ہو، جس کی اشاعت برطانیہ یا آئرلینڈ میں ہوئی ہو۔
گیتانجلی شری کا ناول ریت سمادھی سات سے آٹھ سال تک کی طویل محنت اور مسلسل لگن کا نتیجہ ہے جو ہندی میں پہلی بار 2018 میں سامنے آیا۔ مصنفہ کی شہرت ادبی ہنگاموں سے نسبتاً الگ تھلگ رہنے والی خاتون کی ہے اور قبل ازیں ان کا ایک ناول مائی کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔
ناول ایک 80 سالہ عورت کی کہانی ہے، جو اپنے خاوند کی موت کے بعد زندگی سے بیزار نظر آتی ہے۔ اپنے انٹرویو میں گیتانجلی شری نے کہا، ”ہمارے ارد گرد ایسے بے شمار بوڑھے افراد موجود ہوتے ہیں، جو بظاہر ایک کونے میں بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔‘‘ ان کے بقول، ”ایسے کسی انسان کی بیزاری نے میرے اندر تجسس بیدار کیا کہ آیا یہ بیزاری کسی نئی وابستگی کا پیش خیمہ تو نہیں۔‘‘ گیتانجلی شری کا ناول ریت سمادھی مقامی ثقافت کے مٹتے نقوش کو صفحات میں قید کرنے کی لازوال کوشش ہے جس کی چمک نے بین الاقوامی سطح پر اپنی جانب توجہ مبذول کروائی ہے۔
بھارتی ریاست اتر پردیش سے تعلق رکھنے والی 65 سالہ گیتانجلی شری اب تک پانچ ناول اور کئی افسانے تحریر کر چکی ہیں لیکن ادبی منظر نامے پر ان کی بھرپور انٹری ‘مائی‘ سے ہوئی۔ یہ ناول بھی ہندوستان کے مٹتے ہوئے مقامی رنگوں کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اس کا مرکزی کردار ایک خاموش طبع اور سر جھکا کر جینے والی ایک گھریلو خاتون ہے۔ مائی کے دو بچے سبودھ اور سونینا نئی نسل کا روپ اور روایتی ہندو گھرانے میں بغاوت کی آواز ہیں، جو مائی میں خاندانی بندشوں کے خلاف کوئی شعلہ بیدار نہیں کر سکتیں۔ بشیر عنوان نے ناول کو مائی کے نام سے اردو کے قالب میں اس وقت ڈھالا تھا جب گیتانجلی کو یہ نام و مقام نہیں ملا تھا۔
پلٹزر پرائز
فکشن کے پلٹزر پرائز کے لیے جوشوا کوہن کا نام دس مئی 2022ء کو فاتح کے طور پر سامنے آیا تھا۔ اس ایوارڈ کا آغاز 1911 میں انتقال کرنے والے اخبار پبلشر جوزف پلٹزر کی وصیت پر 1917 میں شروع ہوا تھا۔ جوزف پلٹزر نے کولمبیا یونیورسٹی میں جرنلزم اسکول شروع کرنے اور پلٹزر ایوارڈ کے لیے اپنی زندگی میں ہی رقم مختص کر دی تھی۔
ویمنز پرائز کا تذکرہ
اس سال ویمنز پرائز کے لیے اپریل میں ناموں کی مختصر فہرست سامنے آئی تھی اور 15 جون کو فکشن کے لیے امریکی مصنف اور فلم ساز کو اس کا حق دار قرار دیا گیا۔ یہ مصنّف کا چوتھا ناول ہے جسے لندن میں منعقدہ تقریب میں ایوارڈ دیا گیا۔
فرینکفرٹ کا کتب میلہ
جرمنی کا مشہور کتب میلہ فرینکفرٹ شہر میں 19 اکتوبر سے 23 اکتوبر تک جاری رہا اور اس سال بھی دنیا بھر سے علم و ادب کی ممتاز شخصیات اور معروف ناشروں کی شرکت کے ساتھ میلے کے آخری روز کتابی صنعت کے امن انعام کا اعلان بھی کیا گیا، یہ انعام یوکرین کے ادیب کو دیا گیا۔
15 ویں عالمی اردو کانفرنس
کراچی کی عالمی اردو کانفرنس میں اس سال بھی حسبِ روایت علم و ادب، تہذیب و ثقافت اور فنون لطیفہ کی مختلف جہتوں پر نشستیں برپا ہوئیں اور مذاکرے کے دوران مختلف موضوعات پر اہل علم و فن نے سیر حاصل گفتگو کی۔
15 ویں عالمی اردو کانفرنس کا آغاز کراچی میں یکم دسمبر کو ہوا تھا جو چار روز تک جاری رہی۔ حسبِ روایت صدر آرٹس کونسل آف پاکستان احمد شاہ نے خطبۂ استقبالیہ پیش کیا جس کے بعد افتتاحی اجلاس شروع ہوا۔ ملک بھر سے مایہ ناز اہلِ قلم اور فن کار اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ مہمانِ خصوصی وزیراعلی سندھ مراد علی شاہ تھے۔
کانفرنس کے پہلے روز ناصر عباس نیّر، ایلکس بیلم (آغا خان یونیورسٹی، لندن) نے مقالے پیش کیے۔ اقبال اور قوم کے موضوع پر سہیل عمر، نعمان الحق نے گفتگو کی۔
رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو کے عنوان سے‘‘ اردو کا شاہکار ادب کی پڑھنت ضیاء محی الدّین نے کی۔ دوسرے دن اردو کا نظامِ عروض۔ ضروری غیر ضروری کے موضوع پر آفتاب مضطر، ایاز محمود، تسنیم حسن، رخسانہ صبا نے گفتگو کی۔ اکیسویں صدی میں اردو فکشن (ناول، افسانہ، کہانی) پر بات ہوئی تو صدارت اسد محمد خاں اور زاہدہ حنا کر رہے تھے۔ اصغر ندیم سید نے اکیسویں صدی میں اردو ناول کے موضوعات، فرحت پروین نے داستان سے افسانے تک جب کہ اختر رضا سلیمی نے اردو ناول کے اسلوب اور تیکنیک کے تجربات پر بات کی اور اکیسویں صدی کا اردو افسانہ کے عنوان سے حمید شاہد نے اظہار خیال کیا۔ افسانے کا موضوعاتی تنوع اخلاق احمد اور اردو فکشن کے امتیازات پر محمد حفیظ خان نے بات کی۔
اکیسویں صدی میں تقدیسی ادب پر مذاکرے کی صدارت افتخار عارف اور عالیہ امام کررہے تھے۔ اس میں اکیسویں صدی کی اردو نعت کا اسلوبی جائزہ عزیز احسن نے پیش کیا۔ اکیسویں صدی کی اردو حمد پر فراست رضوی، نعتیہ مسدس کی نئی جہت (خیال آفاقی کے مجموعے ” یا سیدی” کے تناظر میں) پر محمد طاہر قریشی رضوان حسین نے بات کی۔
کانفرنس کے تیسرے روز اکیسویں صدی میں اردو شاعری کی مختلف اصناف پر بات ہوئی جب کہ بچوں کا ادب بھی ایک اہم موضوع تھا۔ پاکستان۔ تعلیم کی صورتحال کے موضوع پر شرکائے گفتگو سردار علی شاہ، شہناز وزیر علی، انجم ہالائی و دیگر تھے۔ اکیسویں صدی میں فنون کی صورتحال (ریڈیو،تھیٹر، ٹی وی،فلم، موسیقی) کے موضوع پر بھی اظہار خیال کیا گیا۔
ااس کانفرنس میں 14 کتابوں کی تقریب رونمائی میں تجزیہ نگار عاصمہ شیرازی کی کتاب بڑے گھر کی کہانی بھی شامل تھی، نشست میں حامد میر اور سہیل وڑائچ نے بند کمروں کی سیاست پر بات کی۔ پاکستان آج اور کل کے موضوع پر حامد میر نے ملک کی جڑوں میں پوشیدہ مسائل اُجاگر کیے۔
عالمی اردو کانفرنس کے آخری روز ادیب شوکت صدیقی کے سو سال، مشتاق احمد یوسفی کی بے باک مزاح نگاری پر بات ہوئی۔ اس مرتبہ کانفرنس کے لیے انگریزی زبان میں دعوت نامہ علمی اور ادبی حلقوں میں تنقید کا باعث بنا تھا جس پر بعد میں توجہ دی گئی تھی اور اسی بات کو اختتامی سیشن کے دوران گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ قرارداد میں یہ بات شامل کی جانی چاہیے کہ عالمی اردو کانفرنس کا دعوت نامہ اردو میں ہو۔ اختتامی اجلاس کے مہمانِ خصوصی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری تھے۔
یادِ رفتگاں کے عنوان کے تحت اس کانفرنس کے دوران شمس الرحمان فاروقی، گوپی چند نارنگ، شمیم حنفی، امداد حسینی، فاروق قیصر (انکل سرگم) کی شخصیت اور فن پر بات ہوئی۔
کتابوں کی دنیا اور ادبی میلے
اس سال ممتاز ادیب مستنصر حسین تارڑ کا پنجابی ناول ’میں بھناں دِلّی دے کِنگرے‘ منظرِ عام پر آیا جو برطانوی راج کے مخالف اور انقلابی بھگت سنگھ کی زندگی پر مبنی ہے۔ رواں برس کی انٹرنیشنل بکر پرائز کی فاتح گیتانجلی شری کا انعام یافتہ ناول بھی اسی سال اردو میں ترجمہ ہو کر قارئین تک پہنچ گیا۔ معروف براڈ کاسٹر، ادیب اور مترجم انور سن رائے نے اس ناول کو اردو زبان میں منتقل کیا ہے۔
اس سال مئی کے مہینے میں آرٹس کونسل کراچی میں "Conversations with my father” کی تقریبِ رونمائی بھی ہوئی، یہ فیض احمد فیض کی بیٹی منیزہ ہاشمی کی کتاب ہے جو رواں برس سامنے آئی۔
کراچی میں عالمی کتب میلہ 8 دسمبر سے 12 دسمبر تک جاری رہا۔ یہ 17 واں کتب میلہ تھا جو کراچی کی روشن اور توانا شناخت بن چکا ہے، اس میلے میں ہر سال زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے عام افراد کے علاوہ علم و ادب سے وابستہ شخصیات اور نام ور لوگ شریک ہوتے ہیں اور کتاب دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے علم و فنون کے فروغ کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ میلے کا مقصد کتب بینی کو فروغ دینا اور اس پلیٹ فارم پر ملکی و غیر ملکی ناشروں اور تقسیم کاروں اکٹھا کرنا بھی ہے۔
کراچی لٹریچر فیسٹول رواں برس مارچ میں منعقد ہوا۔ یہ چار تا چھے مارچ جاری رہنے والا 13 واں ادبی میلہ تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے تحت تین روزہ میلے میں فن و ادب سے جڑے موضوعات پر اہم مذاکرے ہوئے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے علاوہ کئی اہم شخصیات کراچی لٹریچر فیسٹیول میں نظر آئیں جب کہ غیرملکی مندوبین کی بڑی تعداد بھی اس میلے میں شریک تھی۔
اس برس نومبر کے وسط میں دو روزہ میلہ ملتان لٹریری فیسٹیول کے زیرِ اہتمام منعقد کیا گیا جس میں اہلِ قلم اور اردو زبان و ادب کے پڑھنے والوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔
اسی طرح فیصل آباد آرٹس کونسل میں بھی نواں لٹریری فیسٹیول منعقد ہوا جب کہ کراچی میں ادبی میلے کا چوتھا سلسلہ 26 سے 27 نومبر تک جاری رہا۔ یہ میلہ فریئر ہال میں سجایا گیا تھا۔