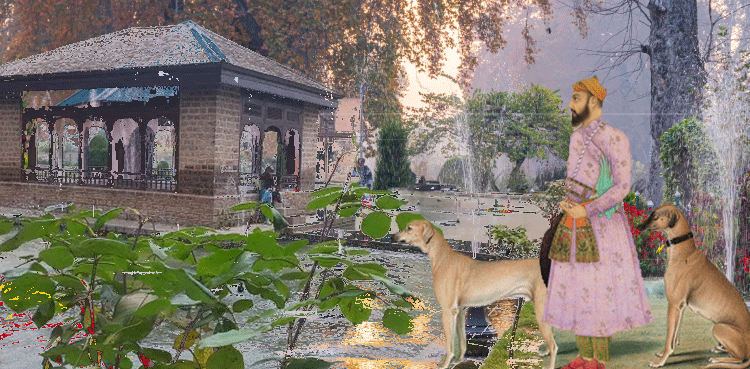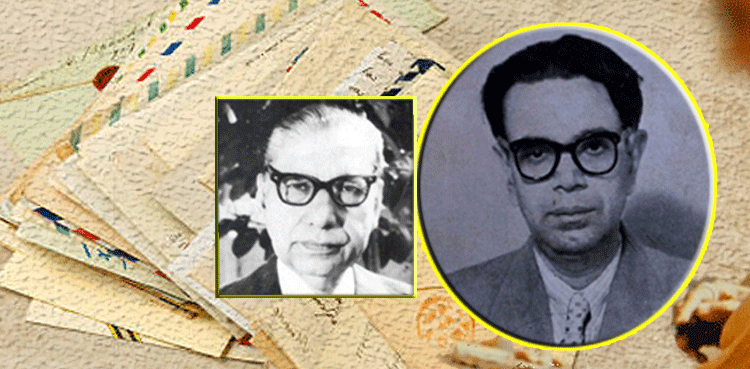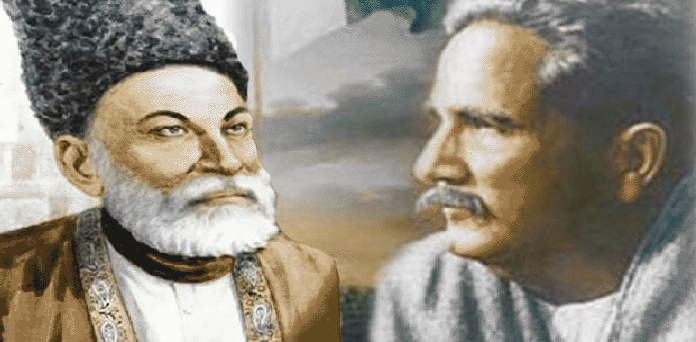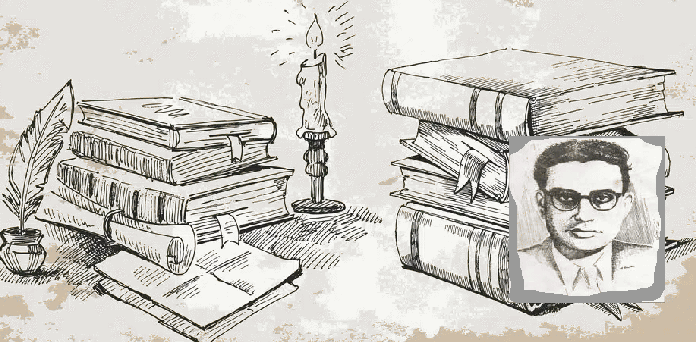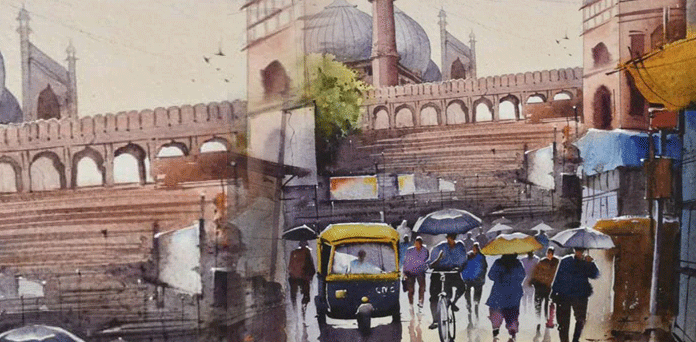ایک زمانہ تھا جب بغرضِ بیانِ حالِ دل، اور شکوہ و شکایت عام آدمی سے لے کر مشاہیر تک خط یا مکتوب نگاری کا سہارا لیتے تھے۔ ادب اور فنون کی دنیا سے وابستہ شخصیات اور اداروں کے درمیان بھی یہی نامے رابطہ و تعلق برقرار رکھنے کا ایک بڑا ذریعہ تھے۔
سرحد پار یا ملک کے کسی بھی شہر سے تخلیق کار اشاعتی اداروں کے پتے پر خط ارسال کرکے اپنے مدیر یا ناشر سے بات کرتا تھا۔ یہ تحریر اسی دور کے ایک مشہور ادبی رسالہ کے مدیر اور ایک نام ور ادیب کے درمیان کچھ نرم گرم اور بنتے بگڑتے تعلق کو ہمارے سامنے لاتی ہے۔ ملاحظہ کیجیے….
عزیز احمد اردو ادب کی ایک مشہور و ممتاز شخصیت کا نام ہے۔ یہ جب جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں زیر تعلیم تھے تب ہی سے شعر و ادب سے وابستگی کا ثبوت دینے لگے تھے۔ عزیز احمد صرف فکشن ہی میں ممتاز نہ تھے بلکہ وہ ایک کام یاب منفرد شاعر بھی تھے۔
عزیز احمد کے کارناموں کی فہرست بہت طویل ہے۔ انھوں نے زندگی کے ایک ایک لمحے کی اہمیت محسوس کی۔ جم کر لکھا اور خوب لکھا۔ ’’ایسی بلندی ایسی پستی‘‘کے خالق کے نشیب و فراز کی داستان ان کے خطوط سے جھانکتی دکھائی دیتی ہے جو انھوں نے مدیر ’’نقوش‘‘ محمد طفیل کے نام لکھے ہیں۔
’’نقوش‘‘ کوئی سرکاری رسالہ نہیں تھا اس کے باوجود وہ اپنے لکھنے والوں کو ان کی تحریروں کا معاوضہ بھی پیش کرتا تھا۔ ویسے ’’نقوش‘‘ایسا معیاری رسالہ تھا کہ لکھنے والے اس میں اپنی تخلیقات کے چھپ جانے ہی کو بہت بڑا انعام سمجھتے تھے۔ نقوش کے معیاری ضخیم نمبر تاریخی و دستاویزی حیثیت کے حامل شمار ہوتے ہیں جیسے ادبی معرکے نمبر، رسول نمبر، خطوط نمبر، افسانہ نمبر، ناولٹ نمبر وغیرہ وغیرہ۔ خود محمد طفیل نے ’’جناب‘‘ اور ’’صاحب‘‘ وغیرہ کے عنوان سے اہم شخصیات پر دلچسپ خاکے بھی لکھے ہیں۔
عزیز احمد نے مدیر ’’نقوش‘‘سے اپنی تحریروں کے معاوضے کے سلسلے میں جو سودے بازی کی ہے وہ چونکاتی ہے۔
محمد طفیل نے ادارہ ’’نقوش‘‘سے مشہور ناول ’’امراؤ جان ادا‘‘ چھاپا تھا۔ در اصل انھوں نے ’’سلسلۂ روحِ ادب‘‘ کے تحت کلاسیکی ادبی سرمائے کی نشاۃِ ثانیہ کا بیڑہ اٹھایا تھا جو کافی مقبول ہوا۔ عزیز احمد لکھتے ہیں:
’’بہرحال آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے تو اردو ادب پر بڑا احسان کیا ہے۔ اسے World’s Classic کی طرح جاری رکھیے۔ ایک اور بڑا بے مثل ناول ’’نشتر‘‘ ہے جو امراؤ جان ادا سے بھی پہلے لکھا گیا اور جس کا شمار اردو کے بہترین ناولوں میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں تو اسے Edit کر کے مقدمے کے ساتھ آپ کے پاس بھیج دوں، مقدمہ، Editing وغیرہ کا جملہ معاوضہ مجھے دو سو روپے 200/- دینا ہو گا جو ایسا زیادہ نہیں ہے۔ اور بھی اس سلسلے میں کیا پروگرام ہے؟
اگر میں کوئی مدد کر سکتا ہوں تو حاضر ہوں۔
فقط عزیز احمد (خط مورخہ ۲۶، فروری ۱۹۵۰ء ) تحقیق نامہ جی سی یونیورسٹی‘‘لاہور)
اس عرصے میں عزیز احمد کا ایک مضمون اور ایک افسانہ ’’نقوش‘‘ میں شائع ہوا تھا۔ مگر محمد طفیل صاحب کی طرف سے ان کا معاوضہ بھیجنے میں تاخیر ہو گئی تھی۔ چنانچہ کراچی سے عزیز احمد انھیں لکھتے ہیں:
مکرمی جناب طفیل صاحب
آپ نے اب تک مضمون وغیرہ کے معاوضے کے 65/- روپیے نہیں بھیجے۔ ’’نشتر‘‘ پر میں نے کافی کام شروع کر دیا ہے۔ دو ہفتے میں آپ کے پاس بھیج دوں گا۔
فقط عزیز احمد (خط مورخہ ۲۴، اپریل ۱۹۵۰ء )
اس دوران عزیز احمد کا تبادلہ کراچی سے راولپنڈی ہو گیا۔ وہاں سے انھوں نے مدیر ’’نقوش‘‘ کے نام خط لکھا:
مکرمی طفیل صاحب تسلیمات
نقوش کا نیا پرچہ دیکھنے کو ملا۔ خود مجھے نہیں ملا۔ شاید اس لیے کہ میں تبادلہ ہو کے راولپنڈی آ گیا ہوں۔ ایک پرچہ روانہ فرمائیں اور نیز معاوضہ چالیس 40/- روپے بھی۔۔۔۔
’’نشتر‘‘ مع اصلاح و دیباچہ کب تک مطلوب ہے تحریر فرمائیے
فقط عزیز احمد (خط مورخہ ۱۷، جولائی ۱۹۵۰ء )
اپنی تحریر کے معاوضے کے لیے وہ اس قدر اتاؤلے ہو رہے تھے کہ پانچ دن بعد اک اور خط لکھا:
مکرمی جناب طفیل صاحب تسلیمات عرض ہے۔
گرامی نامہ ملا۔ براہ کرم آپ چالیس 40/- روپیہ مجھے خود براہ راست فوراً بھیج دیجیے۔ آپ کے کراچی کے آفس کو میرا پتہ نہیں معلوم ہے، اس کے علاوہ میں معاوضے میں تاخیر نہیں چاہتا۔ میرا دوسرا افسانہ ’’آخر کار‘‘ آپ بلا معاوضہ قطعاً نہیں شائع کر سکتے۔ میں اتنی رعایت کر سکتا ہوں کہ بجائے چالیس 40/- کے اس کا معاوضہ آپ سے تیس 30/- روپیہ لوں۔ اس سے زیادہ رعایت نہیں ہو سکتی۔ یہ منظور نہ ہو تو افسانہ مجھے فوراً واپس بھیج دیں۔ تقاضہ اور تکرار خوشگوار چیز نہیں۔
’’نشتر‘‘ عنقریب تیار ہو جائے گی۔ مگر یہی خیال رہے کہ اس کا معاوضہ فوراً مل جائے۔‘‘
فقط عزیز احمد (خط مورخہ۲۱، جولائی ۱۹۵۰ء )
ادبی دنیا میں ’’نقوش‘‘ کا معیار و مرتبہ مسلمہ تھا۔ محمد طفیل کی اپنی ادبی شناخت بھی مسلمہ تھی۔ انھوں نے عزیز احمد کے افسانے کا معاوضہ ادا کرتے ہوئے ان کا دوسرا افسانہ واپس کر دیا اور ’’نشتر‘‘ شائع کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ تب شاید عزیز احمد کو کچھ احساس زیاں ہوا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:
مکرمی جناب طفیل صاحب تسلیمات عرض ہے۔
چالیں 40/- روپیہ اور ’’آخر کار‘‘کا مسودہ واپس مل گئے۔ بہت بہت شکریہ۔ ’’نشتر‘‘ کی حد تک مجھے حیرت ضرور ہوئی لیکن جو آپ کی مرضی۔ اس کا شائع ہو جانا ہی میرے لیے ایک طرح کا انعام اور معاوضہ ہے۔ اس کا دیباچہ میں لکھ چکا تھا۔ لیکن خیر۔ اور کوئی کام اگر میرے لائق ہو تو پس و پیش نہ کیجیے گا۔ معاوضہ کا معاملہ البتہ بالکل کاروباری قسم کا ہونا چاہیے۔‘‘
فقط عزیز احمد (خط مورخہ۱۰، اگسٹ ۱۹۵۰ء )
اسی زمانے میں جلال الدین احمد تین نئے ناول کے عنوان سے قسط وار ایک ایک ناول کا تفصیلی جائزہ لے رہے تھے۔ جس کی دوسری قسط قرۃ العین حیدر کے ناول ’’میرے بھی ضم خانے‘‘(مطبوعہ مکتبۂ جدید لاہور ۱۹۴۹ء ) پر مشتمل تھی جو ’’نقوش‘‘ کے سالنامہ (دسمبر ۱۹۵۰ء ) میں شائع ہوئی۔ تیسری قسط، اعلان کے مطابق عزیز احمد کے ناول ’’ایسی بلندی ایسی پستی‘‘ پر شائع ہونے والی تھی۔ چنانچہ عزیز احمد نے محمد طفیل کو لکھا:
جناب طفیل صاحب، اسلام علیکم
نقوش کا سالنامہ ملا۔ بہت پسند آیا۔ آپ کو اور وقار صاحب کو مبارک ہو۔ احمد ندیم قاسمی کی کہانی بہت خوب ہے۔ میرے خیال میں تو یہ ان کی بہترین کہانی ہے۔ نقوش کا اس طرح ناغہ نہ کیا کیجیے۔ پابندی سے شائع ہو تو رسالہ کا مارکیٹ بندھا ہوا رہتا ہے۔ اور کوئی خدمت میرے لائق ہو تو تحریر فرمائیں۔ ’’نقوش‘‘ کے آئندہ نمبر میں جلال الدین احمد کے مضمون کی تیسری قسط کا انتظار رہے گا جو غالباً میرے ناول پر ہے۔۔۔۔
فقط عزیز احمد (خط جنوری ۱۹۵۱ء)
اس سالنامے کے بعد محمد طفیل ’’نقوش‘‘ کا ایک ’’ناولٹ نمبر‘‘ شائع کرنا چاہتے تھے۔ انھوں نے عزیز احمد سے بھی لکھنے کی فرمائش کی۔ جواباً عزیز احمد نے جو شرائط پیش کیں وہ ان کے مزاج کی عکاسی کرتے ہیں:
مکرمی و محبی جناب طفیل صاحب۔ تسلیمات عرض۔
میں ضرور آپ کے ناولٹ نمبر کے لیے ایک طویل مختصر افسانہ لکھنے کو تیار ہوں بشرطے کہ: (۱) اس کی ضخامت ’’نقوش‘‘ کے تیس ۳۰ صفحے کے لگ بھگ ہو گی نہ کہ ساٹھ صفحے۔ نقوش کے ساٹھ صفحے چھوٹی تقطیع (کذا) کے ۱۲۰ صفحوں سے بھی زیادہ ہو جائیں گے جن کا معاوضہ مجھے عام طور پر ہزار روپیہ ملا کرتا ہے۔
(۲) اس کو آپ نقوش میں تو شائع کر سکیں گے۔ نقوش ہی کے دوسرے ایڈیشن میں بھی اسے شامل کر سکیں گے لیکن اسے کتابی صورت میں نہ شائع کر سکیں گے۔
(۳) اس کا معاوضہ دو سوروپے 200/- مسودہ ملتے ہی مجھے ارسال فرما دیں گے۔
اگر یہ منظور ہو تو فروری کے ختم تک انشاء اللہ طویل مختصر افسانہ یا ناولٹ بھیج دوں گا۔۔
فقط عزیز احمد (خط مورخہ ۲۵، جنوری۱۹۵۱ء )
مدیر ’’نقوش‘‘ نے ناولٹ کے لیے دوسو روپے 200/- ادا کرنے کی ہامی بھر لی تھی مگر نقوش کے تیس صفحات کے بجائے ساٹھ صفحات پر مشتمل ناولٹ پر اصرار کیا تھا۔ چنانچہ عزیز احمد انھیں خط لکھتے ہوئے تیقن دلاتے ہیں:
’’ناولچہ میں ضرور لکھ دوں گا اور کوشش کروں گا کہ پچاس ساٹھ صفحے کا ہو مگر اس کا معاوضہ وہی ہو گا جو آپ خود متعین کر چکے ہیں یعنی محض نقوش کے ایک یا ایک سے زیادہ ایڈیشن کے لیے دوسو روپے 200/- اس میں کمی کا امکان نہیں۔ اور کوئی خدمت!
فقط عزیز احمد (خط مورخہ۳۰، جنوری۱۹۵۱ء )
شاید اس دوران مدیر نقوش کی طرف سے یاد دہانی کرائی گئی تھی۔ عزیز احمد نے بڑے دو ٹوک انداز میں محمد طفیل صاحب کو خط لکھا:
مکرمی و محبی جناب طفیل صاحب۔ سلام علیکم۔
گرامی نامہ کا شکریہ۔ آپ کو ناولٹ ’’نقوش‘‘ کے لیے مل جائے گی اور مجھے دوسو روپیہ معاوضہ جو خود آپ کا تجویز کیا ہوا ہے۔ اس لیے بحث ختم۔۔ ناولٹ نمبر ہی میں جلال الدین احمد کے بقیہ مضمون کو بھی شامل فرما دیجیے جو ’’ایسی بلندی ایسی پستی‘‘پر ہے۔ اور سب خیریت ہے۔
فقط عزیز احمد (خط مورخہ۶، فروری ۱۹۵۱ء )
مگر اپریل ۱۹۵۱ء تک بھی عزیز احمد ناولٹ لکھ نہ سکے۔ حالانکہ ۲۵، جنوری ۱۹۵۱ء کے اپنے خط میں اپنی شرائط پیش کرتے ہوئے انھوں نے فروری کے ختم تک ناولٹ بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ اب وہ محمد طفیل کو لکھتے ہیں:
مکرمی و محبی جناب طفیل صاحب۔
گرامی نامہ کا شکریہ۔ ناولچہ نہ بھیج سکنے کا افسوس ہے لیکن میں نے آپ سے حتمی وعدہ تو نہیں کیا تھا۔ کو شش کرنے کے لیے لکھا تھا۔ باوجود کوشش کے میں اس کی تکمیل نہ کر سکا اور نہ مستقبل قریب میں اس کے مکمل ہو سکنے کی کوئی توقع ہے۔ بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے کوشش تو بہت کی کہ آپ کی فرمائش کی تکمیل کروں۔ لیکن کام کی چیز لکھنے کے لیے وقت درکار ہے اور وقت آپ نے ہمیشہ بہت کم دیا۔ اگر آپ نے بجائے فروری کے مجھے آخر اپریل تک شروع ہی میں مہلت دی ہوتی تو بہت اچھا ناولٹ اب تک تیار ہو گیا ہوتا۔ اب آپ کا جی چاہے تو میرا انتظار کیے، بغیر ناولٹ نمبر شائع کر دیں۔ یا مجھے کم از کم ایک ماہ کی مہلت دیں۔
مخلص۔ عزیز احمد (اس خط پر تاریخ درج نہیں ہے مگر قرائن سے یہ اوائل اپریل۱۹۵۱ء کا لگتا ہے )
مئی ۱۹۵۱ء میں ’’نقوش‘‘ کا ناولٹ نمبر شائع ہو گیا۔ رقمی معاوضے کے علاوہ اب عزیز احمد اس پر اصرار کرنے لگے کہ ان کے ناول کے بارے میں جلال الدین احمد کا لکھا ہوا مضمون ’’نقوش‘‘میں شائع کیا جائے۔ ان کا ایک خط بڑا حیران کن ہے:
مکرمی و محبی جناب طفیل صاحب۔ تسلیمات عرض
آپ سے ایک چھوٹی سی شکایت بھی ہے۔ جلال الدین احمد کے مضمون تین نئے ناول’’ کے دو حصے تو آپ نے شائع کیے لیکن تیسرا حصہ جو ’’ایسی بلندی ایسی پستی‘‘کے متعلق تھا آپ نے اب تک شائع نہیں کیا۔ اس ناراضی کا باعث کیا ہے؟ یہ حصہ شائع ہو لے تو پھر میں بھی ’’نقوش‘‘ کے لیے کچھ لکھوں گا اور پہلی چیز جو میں آپ کے لیے لکھوں گا بلا معاوضہ ہو گی لیکن اس کے لیے مجھے جلال الدین کے مضمون کا انتظار رہے گا۔ جنھیں خود شکایت ہے۔
کم ترین۔ عزیز احمد (خط مورخہ۶، جنوری ۱۹۵۲ء )
ایک عرصے تک عزیز احمد نے ’’نقوش‘‘ کے لیے کچھ نہیں لکھا۔ ایسا لگتا ہے اندر اندر وہ مدیر ’’نقوش‘‘سے خفا خفا سے تھے۔ ان کی فرمائش کے جواب میں وہ لکھتے ہیں:
مکرمی و محبی جناب طفیل صاحب۔ السلام علیکم۔
آپ کے دو خط ملے ایک شکایت کا دوسرا میرے خط کے جواب میں۔ میں آپ کو مضمون یا افسانہ ضرور بھیجوں گا۔ اس کا حتمی وعدہ کرتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ پہلے آپ ’’ایسی بلندی ایسی پستی ’’پر جلال الدین احمد والا مضمون شائع کریں۔ آخر آپ نے مجھ سے یہ امتیاز کیوں برتا؟ اگر مجھ سے ’’نقوش‘‘ کے لیے لکھنے میں تاخیر ہوئی تو احسن فاروقی اور قرۃالعین نے اتنا بھی نہیں لکھا جتنا میں نے لکھا۔ اگر آپ اب تک ’’نقوش‘‘ کے لیے کچھ نہ بھیجنے کی وجہ پوچھتے ہیں تو عرض ہے کہ وجہ محض یہی تھی کہ آپ نے ایک مضمون کا محض وہ حصہ شائع کرنے سے اجتناب کیا جو مجھ سے متعلق تھا اور یہ تضاد میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک طرف تو مجھ سے مضمون کا تقاضہ اور اخلاص کا دعویٰ اور دوسرے میرے ہی خلاف ایسا امتیازی سلوک! اس لیے میں آپ کو ایک نہیں کئی مضامین یا افسانے بھیجنے کو تیار ہوں جن میں سے صرف پہلا بلا معاوضہ ہو گا لیکن اگر آپ کو اپنے اخلاص کا دعویٰ سچا نظر آتا ہے تو آپ کو بھی میرے خلاف یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا اور اب یہی صورت ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ ’’ایسی بلندی ایسی پستی‘‘ والا مضمون شائع فرمائیں۔ میں اس کو پڑھ لوں۔ اس کے بعد کے شمارے کے لیے افسانہ یا مضمون بھیجنے کا میرا حتمی اور پکا وعدہ ہے۔ مجھے نقوش سے کوئی بیر نہیں۔ ہمدردی ہے کیونکہ آپ اس ناموافق زمانے میں اتنی گراں قدر ادبی خدمت انجام دے رہے ہیں۔
مخلص۔ عزیز احمد (خط مورخہ فروری ۱۹۵۲ء )
عزیز احمد حکومت پاکستان کے Department of Advertising, Films and Publications میں ڈپٹی ڈائریکٹر اور پھر ڈائریکٹر ہو گئے تھے۔ ۱۹۵۰ء میں یعنے آج سے ساٹھ برس پہلے کے تیس چالیس روپے آج کے تیس چالیں ہزار روپیوں کے برابر تھے۔ ایک ناولٹ کے لیے عزیز احمد کا دو سو روپے طلب کرنا گویا دو لاکھ روپے کا مطالبہ کرنا ہے۔ مدیر ’’نقوش‘‘ کی ہمت کی داد دینی پڑتی ہے کہ وہ اپنے لکھنے والوں کو ایسی کثیر رقم بطور معاوضہ دینے پر قادر تھے۔
عزیز احمد کو روپے پیسے کی کبھی کمی نہیں رہی۔ حیدرآباد میں وہ بادشاہ کی بہو در شہوار کے پرائیوٹ سکریٹری رہے جو بہت با عزت منصب تھا۔ پاکستان میں بھی وہ اہم عہدوں پر اچھے خاصے مشاہرے کے حامل رہے۔ اس کے باوجود وہ اگر مدیر نقوش سے سودے بازی کرتے دکھائی دیتے ہیں تو دراصل وہ اپنے قلم کی اہمیت جتانا چاہتے تھے۔
(ماخوذ از مشاہیر…. خطوط کے حوالے سے (تنقیدی مضامین) مصنفہ رؤف خیر)