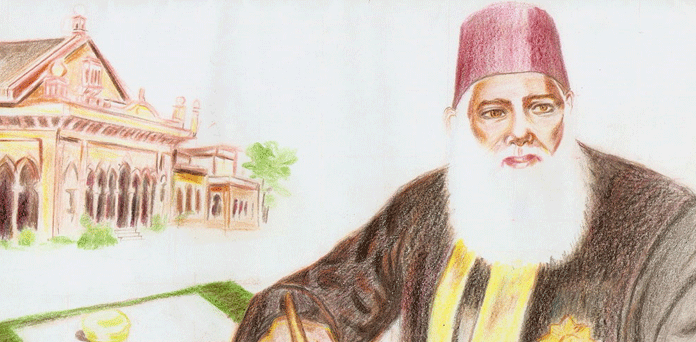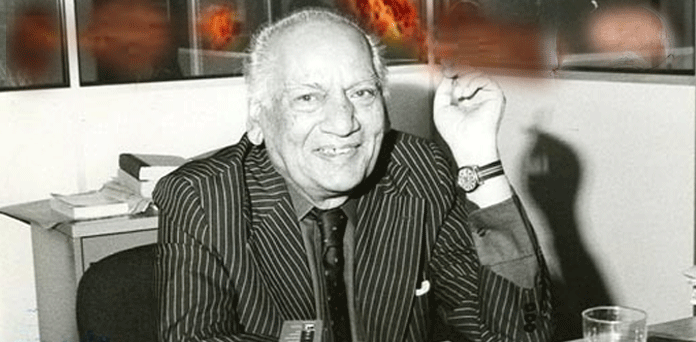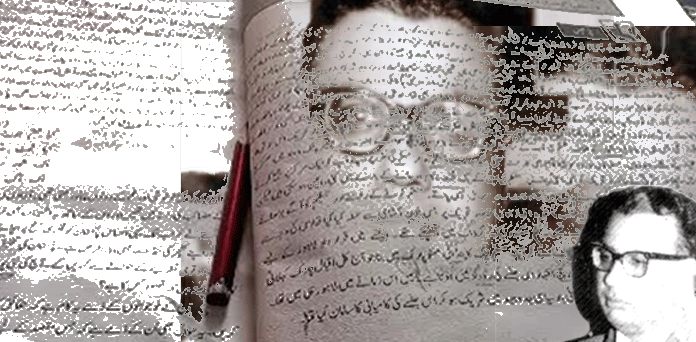فورٹ سینٹ جارج کالج مدراس
ہندوستان کی بساط سیاست پر جب انگریزوں نے اپنے قدم مضبوطی سے جما لئے تو انگلستان سے آنے والے جونیر انگریز سول اور فوجی ملازمین کے لئے جنہیں منشی (WRITER) کہا جاتا تھا مقامی زبانوں اور ہندوستانی تہذیب و تمدن سے آشنا کرنے کے لئے جوزف کلکٹ (JOSEPH COLLECT) گورنر مدراس نے 1717ء میں مدراس میں فورٹ سینٹ جارج اسکول کی بنیاد ڈالی جو رائٹرس کالج (WRITERS COLLEGE) بھی کہلاتا تھا اور آگے چل کر یہ فورٹ سینٹ جارج کالج کے نام سے مشہور ہوا۔
یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا تعلیمی ادارہ تھا جہاں جونیر انگریز ملازمین رائٹرس (WRITERS) کی تعلیم و تربیت کا باقاعدہ انتظام کیا گیا تھا۔ کیونکہ انگلستان یا بنگال اور خود کلکتہ میں بھی ان جونیر ملازمین کی تعلیم کا کوئی انتظام نہ تھا۔ 1756ء کے قانون کے ذریعہ جونیر ملازمین کا باقاعدہ تقرر ہونے لگا۔ ان کی بھرتی انگلستان میں ہوتی اور اس عہدہ کے لئے عموماً ایسے نوجوانوں کو منتخب کیا جاتا جو ہندوستان میں ملازمت کے خواہش مند ہوتے اور جن کی عمریں پندرہ سے اٹھارہ سال کے درمیان ہوتیں ان سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ سول (کشوری) اور ملٹری (فوجی) دونوں ذمہ داریاں پوری کریں گے۔
مدراس کے "اعظم الاخبار” نے اپنے ایک اداریے میں مسلمانوں کو انگریزوں سے سبق حاصل کرنے کا مشورہ دیا تھا اور بتایا تھا کہ انگریز اپنے بچوں کی تربیت کی طرف بطور خاص توجہ کرتے ہیں اور کم عمری ہی میں وہ تربیت سے فارغ ہو کر ملازمت کے لئے دوسرے ممالک کو چلے جاتے ہیں۔
چنانچہ اخبار لکھتا ہے :
"انگریزوں کی تربیت دیکھو کہ بارہ سال کی عمر والے، پندرہ سال کی عمر والے تربیت سے فارغ ہو کر اپنا شہر چھوڑ کر پرملک (دوسرے ملک یعنی ہندوستان) کو پیدائش (ملازمت) کے لئے آتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ دیکھے دکھاتے ان کی تربیت کا ڈھب نہیں سیکھتے۔ بیس سال تیس سال کے بعد تربیت پانے کا خیال کرتے ہیں۔ خاک پڑو ایسے خام خیال پر کیا یہی وقت تربیت پانے کا ہے؟” ("اعظم الاخبار مورخہ 4/ دسمبر 1851ء)
فورٹ ولیم کالج کلکتہ
فورٹ سینٹ جارج اسکول کے قیام کے تراسی سال بعد گورنر جنرل لارڈ ویلزلی نے 1800ء میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کی داغ بیل ڈالی۔ اس کالج کے قیام کا مقصد بھی ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ولایت سے نووارد انگریز سول اور فوجی ملازمین کو ہندوستانی زبانوں بالخصوص اردو کی تعلیم دینا تھا۔ تاکہ جہاں بھی وہ تعینات کئے جائیں وہاں کے باشندوں سے گفت و شنید کے ذریعہ نہ صرف کمپنی کی تجارت کو فروغ دے سکیں بلکہ اس کی حکومت کو مستحکم اور پائیدار بھی بنا سکیں۔
اردو نثر اور ڈرامہ کے ارتقاء میں فورٹ ولیم کالج اور فورٹ سینٹ جارج کالج کا حصہ
اردو زبان و ادب خاص طور پر اردو نثر کی ترویج و ترقی کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ اور فورٹ سینٹ جارج کالک مدراس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان اداروں میں نہ صرف بڑی مماثلت اور مشابہت تھی بلکہ دونوں اداروں کے مقاصد بھی یکساں تھے۔ اور انہوں نے ایک جیسے کارنامے انجام دیے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کی وجہ سے اردو نثر کی نشاۃ ثانیہ کا آغاز ہوا۔ اس کالج کے مصنفوں نے اردو نثر کا ایک ایسا اسلوب اختیار کیا جو بعد کے مصنفوں کے لئے چراغ راہ ثابت ہوا۔
یہ تحریک ہندوستان کی سب سے پہلی شعوری و اجتماعی ادبی و لسانی تحریک تھی جس نے اردو نثر کی رفتار ترقی کے لئے مہمیز کا کام کیا اور اسے وہ قوت و توانائی عطا کی کہ نصف صدی کی مختصر مدت میں اردو زبان کے اندر مختلف مضامین و مباحث کامیابی کے ساتھ ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ اسی طرح اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنوبی ہند میں اردو کی ترویج و ترقی اور اشاعت میں فورٹ سینٹ جارج کالج مدراس نے وہی کردار ادا کیا جو شمال مشرقی ہند میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ نے ادا کیا۔ اگر ان میں تفریق و تمیز کی کوشش کی جائے تو محض اس قدر کہا جا سکتا ہے کہ جس زمانے میں فورٹ ولیم کالج شمال مشرقی ہندوستان میں اردو کی تہذیب و ترقی اور ترویج و اشاعت کی خدمات انجام دے رہا تھا فورٹ سینٹ جارج کالج مدراس جنوبی ہند میں اس کی قدیم شکل یعنی "دکنی” کے فروغ کی خاطر سرگرم عمل تھا۔ مجموعی طور پر ان دونوں اداروں نے اردو زبان و ادب کی ترقی و اشاعت میں عہد ساز کارنامے انجام دیے ہیں۔ نہ تو ان کی خدمات سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے اور نہ اردو زبان و ادب کا کوئی مؤرخ ان کے تذکرہ سے دامن کشاں گزر سکتا ہے۔
فورٹ ولیم کالج کلکتہ اور فورٹ سینٹ جارج کالج مدراس کے ارباب اقتدار بہترین تصانیف پر انعام و اکرام کا اعلان کر کے کالج سے متعلق اور غیر متعلق مصنفین کو تصنیف و تالیف کے کام میں عملی شرکت کی طرف راغب کرتے تھے، جس کے نتیجے میں متعدد مفید کارآمد اور غیر فانی شاہ کار وجود میں آئے۔ ان کالجوں کے علاوہ خود ایسٹ انڈیا کمپنی نے مدراس گورنمنٹ کے ایسے ملازم طلبہ کو جو سات مقامی زبانوں میں سے کم از کم دو زبانوں میں مہارت حاصل کر لیتے تھے، انعامات سے نوازا کرتی تھی۔
مدراس کے گورنر سر ہنری پاٹنجر (SIR HENRY POTTINGER) نے سپریم گورنمنٹ کے حکم پر ایک اعلان "یونائٹیڈ سروس گزٹ” میں شائع کروایا تھا۔ اس اعلان کو مدراس کے مشہور اردو اخبار "اعظم الاخبار” نے بھی شائع کیا تھا۔ جو حسب ذیل ہے:
"مدراس کے گورنر سر ہنری پاٹنجر صاحب بہادر سپریم گورنمنٹ کے حکم (کے) موافق اس ملک کے تمام شمشیر بند سرداروں (فوجی ملازمین) کو اطلاع دیتے ہیں کہ اگر کوئی سردار ان سات زبانوں میں سے دو زبان یا زیادہ سیکھ کے امتحان دیوے تو اس کو سرکار کی طرف سے یک مشت (ایک) ہزار روپے انعام ملیں گے۔ سوائے اس کے وے (وہ) لوگ معقول خدمتوں پر مامور ہوں گے۔” (اعظم الاخبار مؤرخہ 22 اپریل 1852ء)
مقامی زبانیں سیکھنے والے عہدیداروں کی حوصلہ افزائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ فورٹ سینٹ جارج کالج کے اکثر "سولجر” (سپاہی)، اردو (ہندی) اور فارسی وغیرہ مختلف السنہ سے اچھی طرح واقف ہوگئے تھے اور ان زبانوں میں وہ اس طرح گفتگو کرتے تھے گویا یہ ان کی مادری زبانیں ہوں۔ چنانچہ "اعظم الاخبار” کے ایڈیٹر اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
"قلعہ (فورٹ سینٹ جارج) میں اکثر سولجر(سپاہی) ہندی (اردو) اور فارسی زبان خوب جانتے تھے اور لکھنے پڑھنے کا بھی اچھا سلیقہ رکھتے تھے چنانچہ کئی سولجروں کو ہم دیکھے کہ وے( وہ) فارسی گفتگو اس طور پر کرتے تھے کہ قابلوں کے سوائے دوسروں کو ان کی تقریرسمجھنا دشوار ہوتا تھا۔” (اعظم الاخبار، مؤرخہ 22/ اپریل 1852ء)
مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد برطانوی سامراج نے دو سو سال کی طویل مدت تک برصغیر ہند و پاک کے وسیع و عریض علاقوں پر حکمرانی کی۔ ایک طرف تو انہوں نے ہندوستان جنت نشاں کی بہت ساری دولت لوٹی اور معاشی حیثیت سے ہندوستان کو پست ماندہ بنا کر چھوڑا۔ لیکن ساتھ ساتھ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے اس سر زمین کی زبانوں، ثقافت اور تاریخ اور زندگی کے دیگر شعبوں کے مطالعہ میں گہری دلچسپی لی۔عوامی رابطے کی حیثیت سے انہوں نے اردو زبان کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے مدراس میں فورٹ سینٹ جارج کالج، کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج اور انگلستان میں ‘ہیلی بری کالج’ کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے جہاں حکمران جماعت کے افراد کو برصغیر کی مقبول عام زبان میں شد بد پیدا کر کے ملکی معاملات انجام دینے کے قابل بنایا وہیں ان تعلیمی اداروں نے اردو زبان و ادب کی ترقی میں جو گراں قدر حصہ لیا ہے اس کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ہندوستان میں طباعت اور صحافت کی ابتدا بھی انگریزوں ہی کی دین ہے۔
اردو میں ڈرامہ کی ابتدا
اردو لٹریچر، ڈرامہ کے عنصر سے بالکل خالی تھا۔ اردو میں ڈرامہ کا لفظ انگریزی زبان کے اثرات اور انگریزوں کی وجہ سے مستعمل ہوتا ہے۔ انگریزوں ہی کی کوششوں سے چند عمدہ ڈرامے تصنیف اور ترجمہ ہوئے۔ پہلی بار فورٹ ولیم کالج کے منتظم اعلی ڈاکٹر جان گلکرٹ کی فرمائش پر 1801ء میں کاظم علی جواں نے للو لال جی کی مدد سے سنسکرت کے مشہور ناٹک "شکنتلا” کو آسان اردو نثر میں منتقل کیا۔ یہ کتاب 1802ء میں فورٹ ولیم کالج کی جانب سے شائع ہوئی اور مقبول ہوئی۔ اس طرح اس ناٹک کی بدولت اردو میں نوٹنکی، سوانگ، رام لیلا، راس لیلا، اور رہس کی ابتدا ہوئی۔ نواب واجد علی شاہ کے رہس، امانت کی اندر سبھا اور دیگر سبھائیں اسی کا نتیجہ ہیں۔
(ماخوذ از کتاب: اردو کا پہلا نثری ڈرامہ اور کیپٹن گرین آوے، مصنف مضمون: ڈاکٹر محمد افضل الدین اقبال)