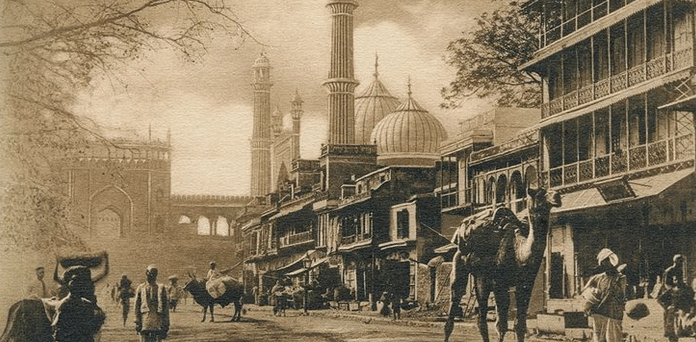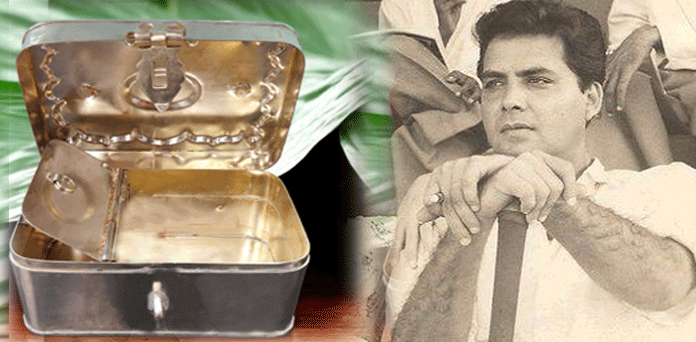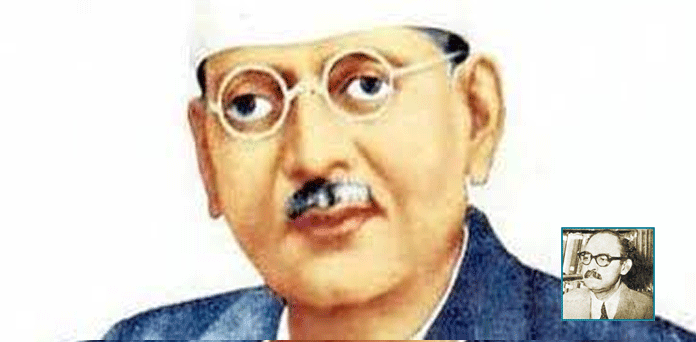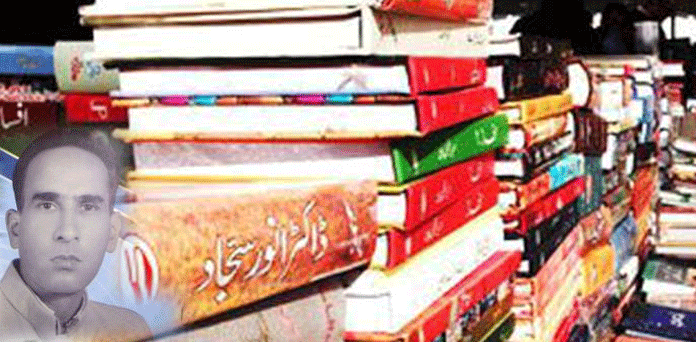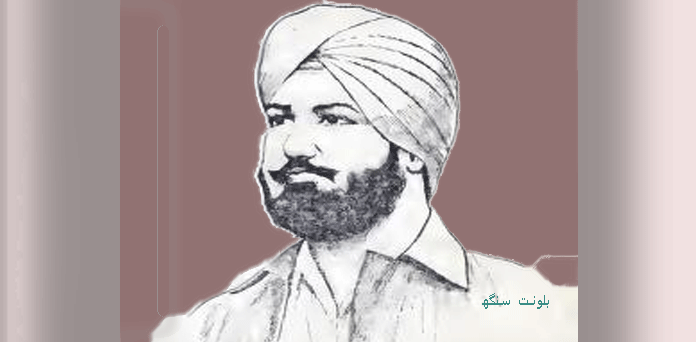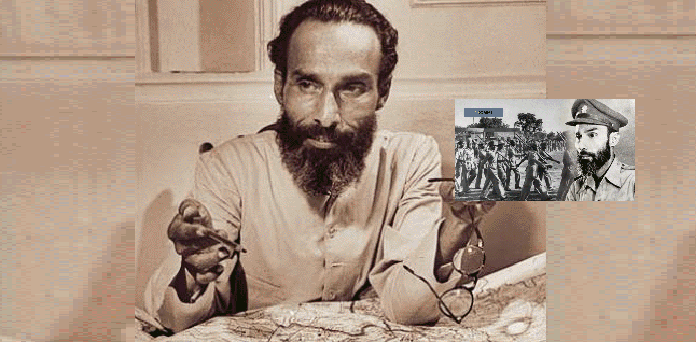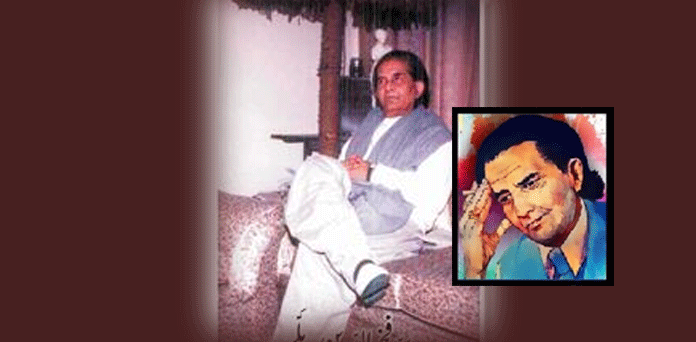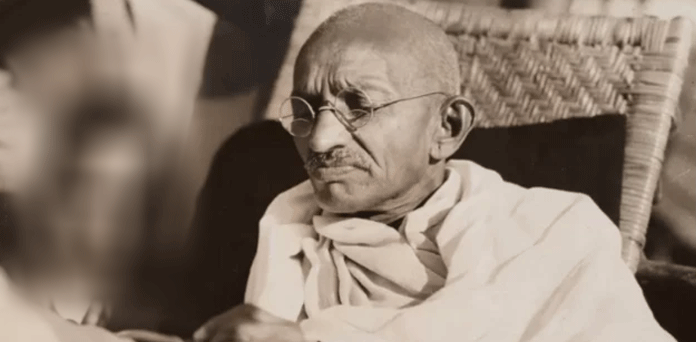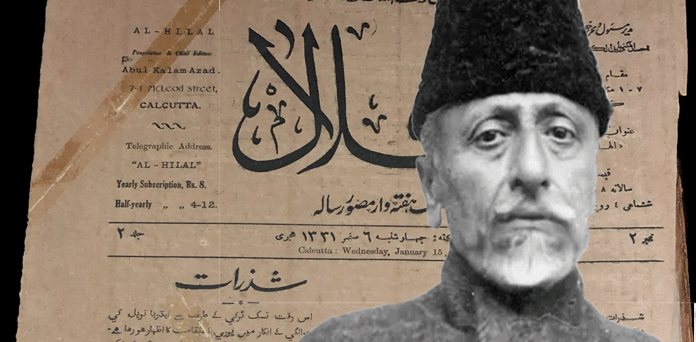شعر و ادب کے حسن و قبح کو پرکھنے کی کسوٹی کسی زمانے میں محض زبان و بیان اور قواعد عروض کے چند بندھے ٹکے اصول تھے۔ مشاعروں، نجی صحبتوں اور ادبی معرکہ آرائیوں سے لے کر درس گاہوں تک انہیں اصولوں کی حکمرانی تھی۔
پھر ایک ایسا دور آیا جب شعری ادبی تحقیقات کو اس تنگنائے سے باہر نکلنے کا موقع ملا اور موضوع و معنی کی قدر و قیمت سے بحث ہونے لگی۔ اردو میں نقد و انتقاد کو صحیح معنوں میں اسی وقت سے پروان چڑھنے کے لیے ایک سازگار فضا میسر آئی مگر یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ ہماری ادبی تنقید نے روز اوّل سے ہی اخلاقی اور افادی اقدار پر اس قدر توجہ کی کہ شعری اور ادبی تصانیف کے فنی حسن اور تخلیقی و جمالیاتی تقاضوں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ ادب کی تخلیق نہایت پیچیدہ عمل ہے۔ بسا اوقات ایک ایسا شعر یا نثر پارہ جو اپنے موضوع کے اعتبار سے نہایت مفید، معقول اور صالح سماجی یا اخلاقی اقدار کا حامل ہو، بے کیف اور بے اثر معلوم ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف داغ اور جرأت کا کوئی فاسقانہ شعر سن کر منھ سے بے اختیار واہ نکل جاتی ہے۔
آخر وہ کون سا جادو ہے جو ایک معمولی اور مبتذل خیال یا تجربے کو حسین بنا دیتا ہے اور وہ کون سا عنصر ہے جس کی غیرموجودگی ایک اعلیٰ و ارفع معنی کو تاثیر اور لذت سے محروم کر دیتی ہے۔ اردو تنقید حالی کی افادی و اخلاقی تنقید سے لے کر موجودہ دور کے ادبی دبستانوں تک نہ جانے کتنی منزلیں طے کرچکی ہے مگر ادبی تخلیق کے اس راز کو دریافت کرنے میں عموماً ناکام رہی ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر شعر و ادب سے لطف اٹھانے اور اس سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہی نہ ہو یا ہماری جمالیاتی اور تخلیقی حس بالکل کند ہو گئی ہو۔ عام طور پر ہمارا رویہ اس سلسلے میں نارمل ہوتا ہے، خاص طور پر اس شخص کا جو محض ادب کا ایک قاری یا سامع ہو اور شعر یا ادبی تحریر اس کی ذہنی تسکین کے لیے غذا کا کام کرتی ہو مگر ہمارے یہاں گزشتہ تیس برس میں جس طور پر اردو کے ادیبوں اور نقادوں کے ادبی مزاج کی تشکیل ہوئی ہے، اس نے ادبی لطف اندوزی کی راہ میں طرح طرح کی دیواریں کھڑی کردی ہیں۔ نظریہ، فلسفہ، عقیدہ، سماجی افادیت، صحت مندی، رجائیت، اجتماعی شعور اور نہ جانے کتنی اصطلاحات جن کو ہم نے ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر طاری کر لیا ہے۔
ہماری ادبی تاریخ کا یہ دور تحریکوں کا دور رہا ہے۔ ادبی تحریکوں سے ادب کے ارتقا میں یقیناً مدد ملتی ہے مگر تحریک زدگی، کبھی کبھی ہم کو اصل ادب سے دور بھی کر دیتی ہے۔ کوئی تحریک اگر چند فارمولوں اور فیشنوں یا چند تنقیدی مفروضات کو ہی ادب کی اساس سمجھنے لگے تو اس تحریک کے سائے میں پروان چڑھنے والا ادیب اور شاعر اپنے شخصی تجربات اور باطنی کیفیات پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اپنے حقیقی جذبات اور دلی وارادت کی نفی کر کے ان خیالات پر اپنی تحریروں کی بنیاد رکھنے لگتا ہے جو دراصل اس کی تخلیقی شخصیت سے فطری مناسبت نہیں رکھتے۔
ترقی پسند ادب کی تحریک کے عروج و زوال سے آج کے ادیبوں کی نسل بہت کچھ سیکھ سکتی ہے۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس تحریک کے سائے میں جس تنقید کو فروغ ہوا وہ شعر یا افسانہ پڑھنے سے پہلے یہ معلوم کرتی تھی کہ یہ ادیب یا شاعر کون ہے؟ اس پر ترقی پسندی کا لیبل لگا ہوا ہے یا نہیں؟ وہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا رکن ہے یا نہیں؟ اگر رکن ہے تو سیاسی جماعت سے کس حد تک وابستہ ہے جس کے نظریے یا فلسفے کو ترقی پسندی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے؟ اگر ان سوالوں کا جواب اثبات میں ہے تو وہ چاہے جس طرح کی چیز لکھے، اس کا ذکر نمایاں طور پر ہوتا تھا۔ اس کی جماعتی وابستگی یا وفاداری اس کے تمام ادبی گناہوں اور فنی کوتاہیوں کا بدل بن جاتی تھی۔
رفتہ رفتہ یہ لے اتنی بڑھی کہ بعض اوقات کسی ادیب کی تحریر کے لیے یہی سند کافی تھی کہ وہ کسی ترقی پسند رسالے میں چھپی ہے۔ بعض رسالے تحریک کے سرکاری آرگن کی حیثیت رکھتے تھے اور اس میں چھپنے والا تمام مواد نقادوں اور ادیبوں کے لیے قابل قبول سمجھا جاتا تھا۔ تحریک پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب بعض رسالوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ گویا ان رسالوں میں لکھنے والا خواہ، اس کی تحریر ترقی پسندہی کیوں نہ ہو، اس کی ترقی پسندی مشکوک سمجھی جائے گی۔ منٹو اور عسکری نے ’’اردو ادب‘‘ کے نام سے رسالہ نکالا تھا یا وہ رسالے جن سے میرا جی اوران کے حلقے کے لوگ وابستہ تھے، اسی ذیل میں آتے تھے۔
ادب میں جدیدیت کا میلان دراصل اسی غیر ادبی مسلک سے انحراف اور رد عمل کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ صحیح معنوں میں جدید ادیب وہ ہے جو زندگی اور اس کے مظاہر کو اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں آزادانہ طور پر دیکھنے اور برتنے کی کوشش کرتا ہے اور تخلیقی عمل کو غیر فطری فارمولوں اور مفروضوں سے الگ رکھ کر فطری نشوونما کا موقع دیتا ہے۔ ایسا ادیب چاہے وہ کسی درجے کا ہو اور اس کے موضوعات کا دائرہ خواہ وسیع ہو یا محدود، سب سے پہلے ادب کے تخلیقی اور جمالیاتی تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کے یہاں اپنے دور کی آگہی اور ہوش مندی ہے اور اس نے زندگی کو رسمی اور روایتی زاویوں سے دیکھنے کے بجائے اس کی حقیقتوں کا از سر نو انکشاف کیا ہے تو اس کی تحریر میں تازگی اور ندرت ضرور ہوگی۔
مگر ہمارے یہاں تحریکوں نے ادبی مزاج پر ایسا گہرا اثر ڈالا ہے کہ بہت سے وہ ادیب بھی جو اپنے آپ کو جدیدیت کا نمائندہ کہتے ہیں، جدیدیت کو ترقی پسندی کی طرح ایک فارمولا یا فیشن سمجھتے ہیں اور ادبی تخلیق میں اسی منصوبہ بندی سے کام لے رہے ہیں جو ترقی پسندوں کی خصوصیت تھی۔ یہی نہیں بلکہ یہ لوگ بھی سوچنے لگے ہیں کہ فلاں شخص جدید ہے یا نہیں یعنی اس نے اپنے جدید ہونے کا اعلان کیا ہے یا نہیں؟ فلاں ادیب کس رسالے میں اپنی چیزیں چھپواتا ہے؟ اگر ایک ادیب یا شاعر مسلسل ’’شب خون‘‘ یا کسی ایسے ہی رسالے میں چھپتا رہا ہو لیکن اتفاق سے ’’گفتگو‘‘، ’’حیات‘‘ یا اسی قبیل کے کسی اور پرچے میں اس کی تحریر چھپ جائے تو اس کی ’’جدیدیت‘‘ مشکوک سمجھی جاتی ہے۔
میرا ذاتی خیال ہے کہ اس طرح کے جدید ادیبوں اور گزشتہ دور کے تحریکی ادیبوں کے ادبی مزاج میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی اپنے پیش روؤں کی طرح ادب کی ایک مصنوعی فضا میں سانس لے رہے ہیں جو ان کے لیے آئندہ چل کر مہلک ثابت ہوگی۔ جدیدیت کا صحیح راستہ تویہ ہوگا کہ کسی پر لیبل نہ لگایا جائے، نہ کسی رسالے کو جدیدیت کا سرکاری ترجمان سمجھا جائے۔ کوئی تحریر اپنے طرز احساس، رویے اور اسلوب اظہار کی بنا پر ہی جدید کہلانے کی مستحق ہوگی۔ اگر ایسی تحریر ہمیں مخدوم، سردار جعفری، کرشن چندر کے قلم سے بھی نظر آئے تو اسے جدید کہنا ہوگا۔ کسی ادیب یا شاعر کو ہم ایسی اکائی نہیں فرضی کرسکتے جو محض ایک خصوصیت کا حامل ہو اور دوسری خصوصیت کبھی اس میں پیدا ہی نہ ہو۔
زندگی کی طرح خود انسان بھی متحرک اور تغیرپذیر ہے۔ ایک ہی ادیب ایک تخلیق میں قدامت کا حامل ہو سکتا ہے تو دوسری تخلیق میں جدیدیت کا۔ اسی طرح اس کی کوئی تحریر ناکام ہوسکتی ہے تو دوسری کامیاب۔ ادب اور ادبی تنقید کو جمالیاتی معیاروں کے علاوہ دوسرے تمام مفروضات سے بالاتر ہونا ہوگا۔ جدید نسل کو اسی ادبی مزاج اور تخلیقی رویے کو آگے بڑھانا ہے ورنہ جدیدیت بھی کچھ دنوں میں ایک تحریک بن کر رہ جائے گی اور اس کے خلاف بھی وہی رد عمل ہوگا جو گزشتہ تحریکوں کے خلاف ہوا۔
(شاعر اور جدید اردو تنقید کے بنیاد سازوں میں سے ایک خلیل الرحمٰن اعظمی کی تحریر)