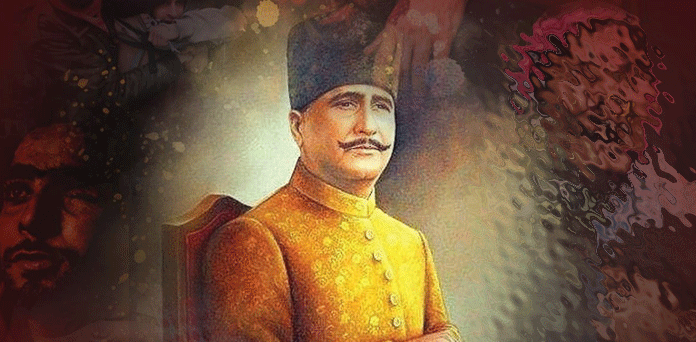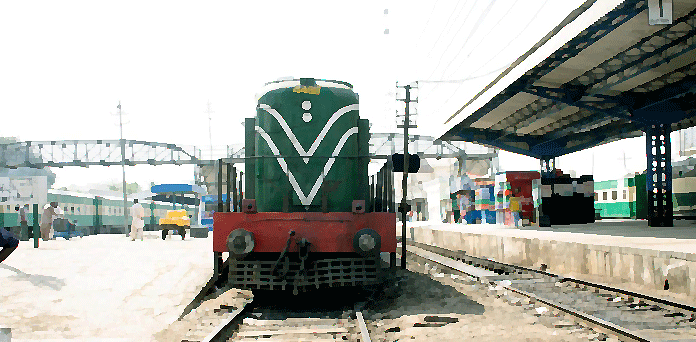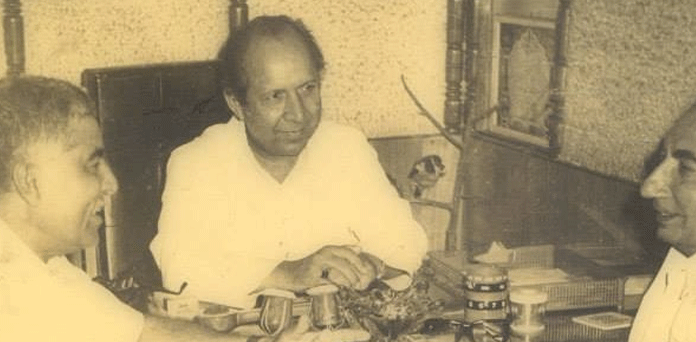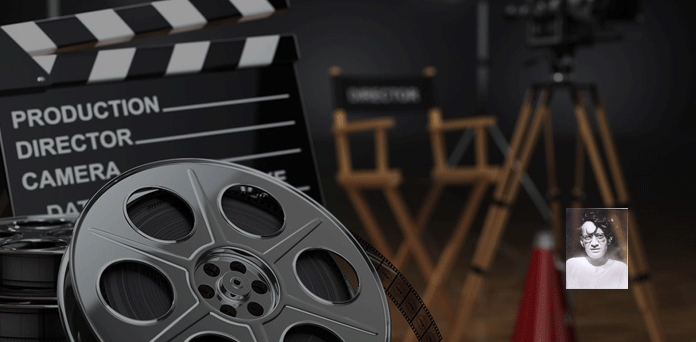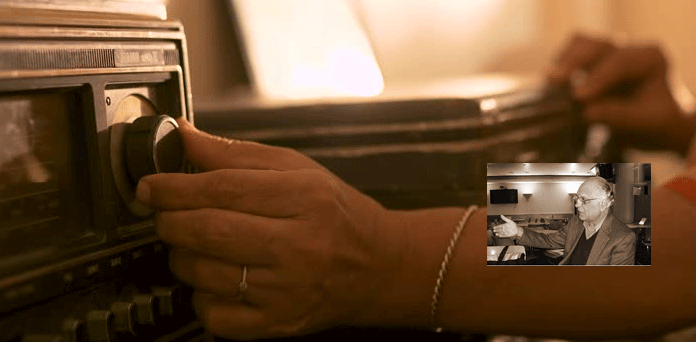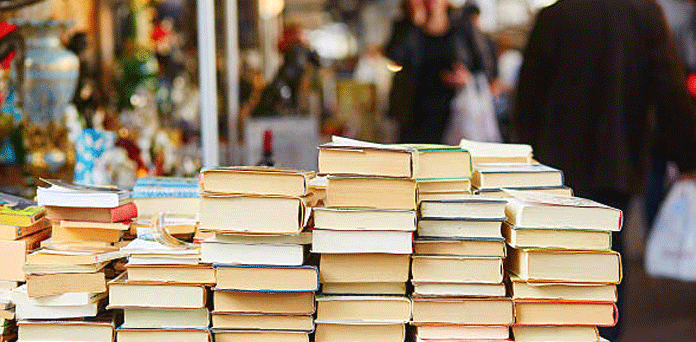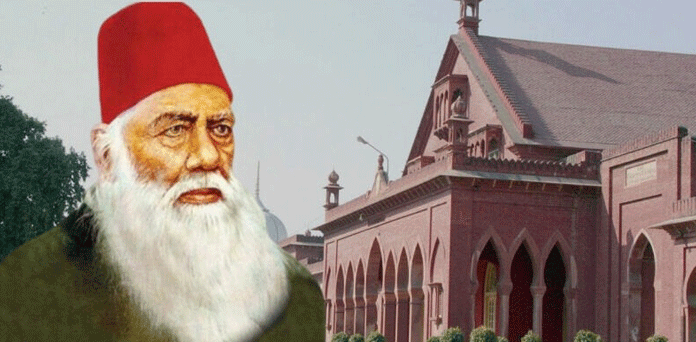سعادت حسن منٹو افسانہ نگاری کےساتھ فلم کی دنیا میں بطور لکھاری بھی مصروف رہے اور ہندوستان کے بڑے نگار خانوں سے وابستگی کے دوران انھوں نے فلم اور فلم سازی کو جس طرح سمجھا اسے اپنے مضامین کی شکل میں پیش کیا۔ ان کی ایک تحریر ہندوستانی صنعت فلم سازی پر ایک نظر کے عنوان شایع ہوئی تھی۔ اسی مضمون سے یہ اقتباس پیش خدمت ہے۔
تیس برس سے ہالی ووڈ کے اربابِ فکر اس بات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلم سازی میں اسٹار کو زیادہ اہمیت حاصل ہے یا خود فلم کو۔
اس مسئلے پر اس قدر بحث کی جا چکی ہے کہ اب اس کے تصور ہی سے الجھن ہونے لگتی ہے۔ آخر متذکرہ صدر سوال کا فیصلہ کن جواب کیا ہو سکتا ہے۔ سوائے اس کے یہ سوال سن کر یوں کہہ دیا جائے، ’’کیا فرمایا آپ نے؟‘‘ مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا؟ اگر اس کا جواب کچھ ہو سکتا ہے تو یقیناً اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ اسٹار زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا خود فلم۔
فرینک کیپرا کولمبیا
فلم کمپنی کے ماہرِ فن ڈائریکٹر نے حال ہی میں اس مسئلے پر اپنے افکار انگریزی اخبارات میں شائع کئے ہیں۔ مسٹر کیپرا کہتے ہیں، ’’میں ان لوگوں کا ہم خیال ہوں جو فلم کو سب سے اہم سمجھتے ہیں۔ فلم، اسٹار بناتے ہیں اور درخشاں سے درخشاں ستارہ کمزور یا برے فلم کو ناکامی سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔‘‘ تجربے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فلم ستارہ ساز ہے اور ستارے کمزور فلم کو تابانی نہیں بخش سکتے، مگر ہمارے یا مسٹر کیپرا کے خیال سے سب متفق نہیں ہو سکتے۔ ایسے سیکڑوں اصحاب موجود ہوں گے جو اپنے نظریے کے جواز میں اور مسٹر کیپرا کے نظریے کے ابطال میں ٹھوس دلائل و براہین پیش کر سکتے ہیں۔
اس ضمن میں سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ ستارے کیوں کر بنتے ہیں یا وہ کون سی چیز ہے جو ستارے بناتی ہے؟
مسٹر کیپرا نے اس سوال کا جواب نہایت دلچسپ انداز میں دیا۔ آپ کہتے ہیں، ’’اگر دنیا کے تمام پروڈیوسر اپنا سرمایہ جمع کر کے میرے حوالے کر دیں (جو یقیناً کافی و وافی ہوگا) اور مجھ سے یہ کہیں کہ ہمارے فلمی آسمان کے لئے تین ستارے چن کر لا دو، تو میں یقیناً خالی الذہن ہو جاؤں گا۔ اس لئے کہ مجھے وہ جگہ معلوم ہی نہیں۔ جہاں سے یہ ستارے مل سکتے ہیں۔‘‘
خاموش فلموں کے زمانے میں ہالی ووڈ کے آسمان فلم کے لئے ستارے عام طور پر ہوٹلوں، کارخانوں اور دفتروں وغیرہ سے آتے تھے، لیکن اب فلموں کی خاموشی تکلم میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس صنعت کو کافی فروغ حاصل ہو چکا ہے۔ ستاروں کی سپلائی بہت کم ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں صنعت فلم سازی کے آغاز میں قحبہ خانے تھیٹر اور چکلے ستارے مہیا کیا کرتے تھے اور اب کہ ہماری صنعت کو کسی قدر فروغ حاصل ہوا ہے، علمی طبقے نے بھی ہمارے فلمی آسمان کے لئے ستارے پیش کرنے شروع کئے ہیں اور مستقبل بعید یا مستقبل قریب میں ایک ایسا وقت آئے گا، جب ہالی ووڈ کی طرح یہاں بھی ستاروں کی سپلائی کم ہو جائے گی۔ مگر ہم یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کون سی شے ہے جو ستارے بناتی ہے؟
مسٹر فرینک کیپرا کی (جن کی ڈائریکشن میں ہالی ووڈ کے بڑے بڑے نامور ستارے کام کر چکے ہیں) رائے ہے کہ کرداروں کی صحیح تقسیم (یعنی موزوں و مناسب کاسٹ) ستارے بناتی ہے۔ ان کے نظریے کے اعتبار سے چینی آدمی کا روپ صرف چینی ہی بطریق احسن دھار سکتا ہے اور لنگڑے یا کبڑے آدمی کا پارٹ صرف لنگڑا یا کبڑا آدمی ہی خوبی سے ادا کر سکتا ہے۔ ہمیں مسٹر کیپرا کے اس نظریے سے اتفاق ہے۔ اسکرین پر کسی کیریکٹر کی ادائیگی کے لئے اتنا ہی زیادہ انہیں کامیابی کا موقع ملے گا، جس آسانی سے ہم اور آپ اپنے آپ یعنی اپنے اصل کو پیش کر سکتے ہیں۔ اس آسانی سے ہم کسی اور کی نقل نہیں کر سکتے جہاں تصنع اور بناوٹ کو دخل ہوگا وہاں اصلیت برقرار نہیں رہ سکتی۔
اس نظریے کے جواز میں مسٹر فرینک کیپرا نے بہت سی مثالیں پیش کی ہیں، جن میں سے ایک گیری کو پر کی ہے۔ آپ کہتے ہیں، گیری کوپر اسکرین پر اپنے آپ کو اصلی رنگوں میں پیش کرتا ہے اور چونکہ وہ ایک خوش ذوق، عالی خیال اور صاحب فہم انسان ہے، اسی لئے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب رہتا ہے۔
ہم یہ کہہ رہے تھے کہ موزوں و مناسب کاسٹ ستارے بناتی ہے، مگر یہ قطعی اور آخری فیصلہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ صرف کاسٹ کا موزوں و مناسب ہونا ہی کسی فلم کو کامیاب نہیں بنا سکتا۔ فلم کی کامیابی کے لئے اور بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے جن کو آپ بخوبی سمجھتے ہوں گے۔ مختصر الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب تک مشینری کے سب پرزے اپنی اپنی جگہ پر اچھا کام نہ کریں گے، فلم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کرداروں اور ٹیکنیشینوں کا باہمی اتحاد پکچر کی صحت کے لئے بہت ضروری ہے۔ جس طرح قیمتی سے قیمتی گھڑی ایک ٹک کرنے سے بھی انکار کر دیتی ہے، ا س لئے کہ اس کے کسی پرزے کے ساتھ میل کا ایک ننھا سا ذرہ چمٹا ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح قیمتی سے قیمتی فلم، ایک حقیر اور معمولی سی فروگزاشت یا غلطی کے باعث فیل ہو جاتے ہیں۔ صحیح کاسٹ ستارے بنانے میں دیگر عناصر سے کہیں زیادہ ممد و معاون ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے غورو فکر کے بعد یقیناً ہمارے ہم نوا ہو جائیں گے، چنانچہ فلموں کو کامیاب بنانے اور ستارے پیدا کرنے کے لئے ہمیں ستارہ شناس نگاہوں کی ضرورت ہے۔