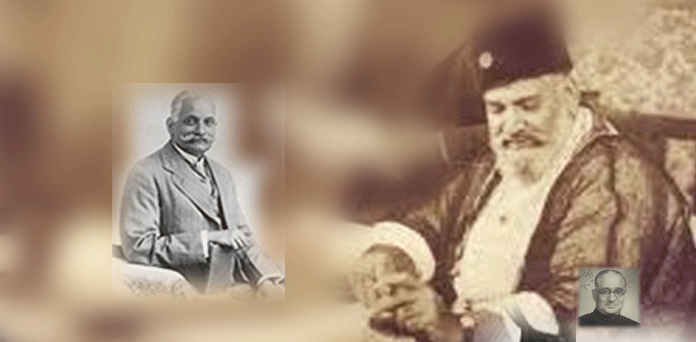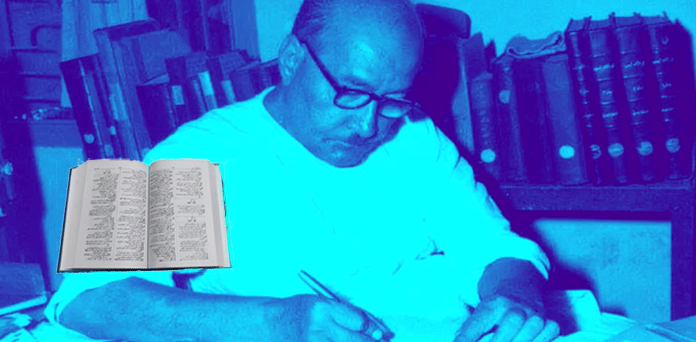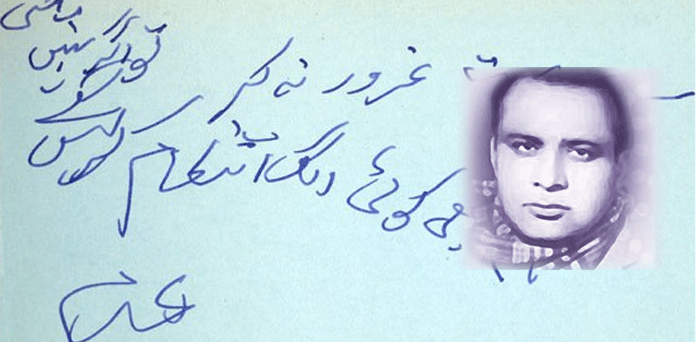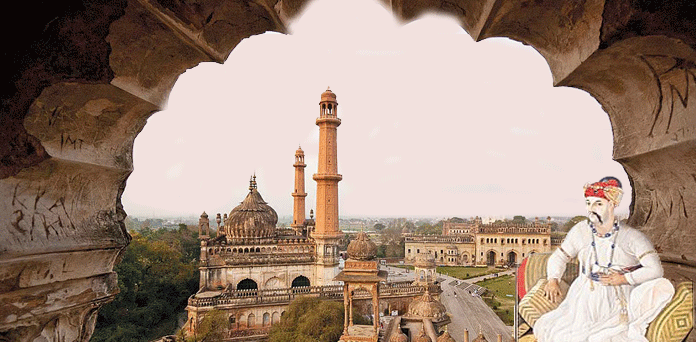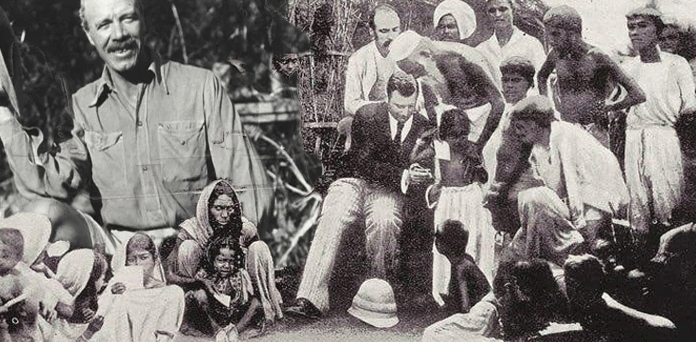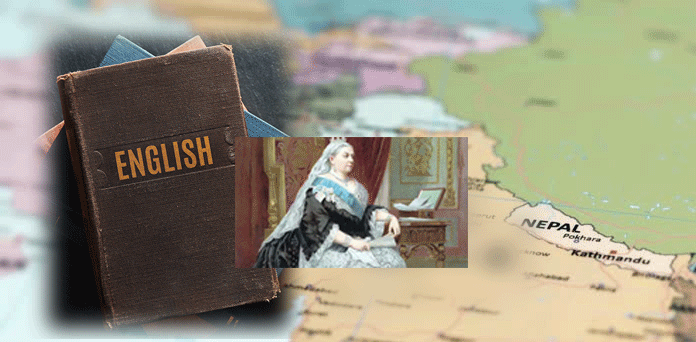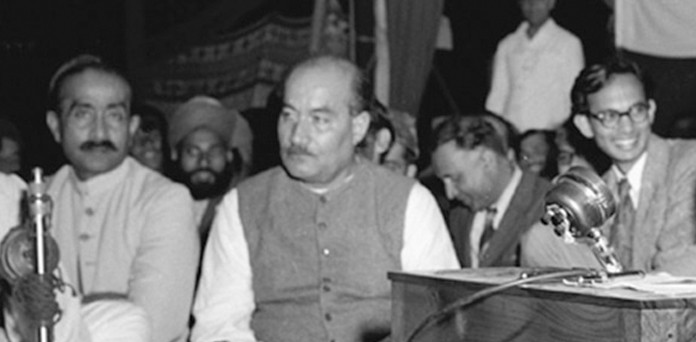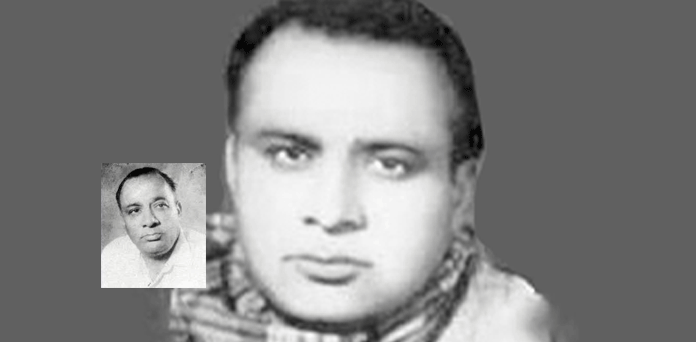جیمز کاربیٹ اور کینیتھ اینڈرسن وہ دو نام ہیں جنھوں نے متحدہ ہندوستان میں برطانوی راج کے دوران بطور انگریز شکاری اور مہم جو نہ صرف اپنی شناخت بنائی بلکہ ہندوستان کے بعض دیہات میں ان کی شہرت عوام کے ہم درد، ایک خیر خواہ اور مددگار کی سی تھی۔ ان شکاریوں نے ہندوستان کے کئی علاقوں میں آدم خور درندوں کا شکار کر کے وہاں کے باسیوں کے دل جیت لیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ان کی ہر بات مانتے تھے اور اپنے مسائل کا حل بھی انہی سے طلب کرتے تھے۔
جیمز کاربیٹ اور اینڈرسن نے شکاریات کے موضوع پر لکھنے کے ساتھ اس دور کے بعض واقعات اور عوامی زندگی کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ یہ ایک ایسا ہی واقعہ ہے جس نے ان شکاریوں کو بھی جذباتی کردیا تھا۔ اسے جیمز کاربیٹ نے رقم کیا تھا جس کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ وہ لکھتے ہیں:
ایک بار موسمِ سرما میں ترائی میں اینڈرسن اور میں مقیم تھے جو کہ ہمالیہ کے دامن میں پٹی ہے۔ ایک بار جنوری میں صبح صبح ہم بندو کھیڑا سے ناشتہ کر کے نکلے اور بکسر کی جانب لمبا چکر کاٹ کر گئے، جو ہمارے اگلے کیمپ کا مقام تھا۔
لمبے چکر کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ملازمین کو خیمے اکھاڑنے، منتقل کرنے اور پھر دوبارہ نصب کرنے کا وقت مل جاتا۔ بندو کھیڑا اور بکسر کے درمیان دو دریا تھے جن پر پُل نہیں تھے اور دوسرے دریا کو عبور کرتے ہوئے ہمارے خیموں والا اونٹ پھسل گیا اور سارا سامان پانی میں ڈوب گیا۔ اس کو نکالنے میں کافی تاخیر ہوئی اور جب ہم پورا دن کالے تیتر کا بہترین شکار کر کے پہنچے تو ہمارا سامان تب جا کر اترنے لگا تھا۔ یہ مقام بکسر کے گاؤں سے چند سو گز دور تھا اور اینڈرسن کی آمد معمولی واقعہ نہیں تھا، اس لیے پورے گاؤں کی آبادی ہمیں خوش آمدید کہنے اور خیموں کی تنصیب میں مدد کرنے آ گئی۔
سر فریڈرک اینڈرسن اس وقت ترائی اور بھابھر کے حکومتی سربراہ تھے اور کئی ہزار مربع میل پر رہنے والے ہر قوم، نسل اور مذہب کے افراد سے ملنے والی محبت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عوام سے کتنے قریب تھے۔ ان کی مہربان طبعیت کے علاوہ اینڈرسن بہت اچھے منتظم تھے اور ان کی یادداشت کا مقابلہ صرف سر ہنری ریمزے سے کیا جا سکتا ہے جو اینڈرسن سے قبل اٹھائیس سال تک اسی جگہ کے حکمران تھے۔ سر ہنری ریمزے کو کماؤں کا غیر علانیہ بادشاہ مانا جاتا تھا۔ ریمزے اور اینڈرسن سکاٹش تھے اور دونوں کے بارے مشہور تھا کہ انہیں کوئی شکل اور نام نہیں بھولتا۔ ہندوستان کے غریب اور مسکین لوگوں سے تعلق رکھنے والا ہر انسان جانتا ہے کہ جب ان لوگوں کو ملاقات پر ان کے نام سے بلایا جائے یا ان سے ملاقات یاد رکھی جائے تو یہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ جب بھی ہندوستان میں برطانوی راج کے عروج و زوال پر لکھا جائے گا، برطانوی راج کے زوال کے اسباب میں سرخ فیتے کی اہمیت پر بھی لکھا جائے گا۔ ریمزے اور اینڈرسن نے جب کام کیا تھا تو اس دور میں سرخ فیتہ دور دور تک نہیں تھا۔ بطور منتظم ان کی شہرت اور ان کی کام یابی کی وجہ ہی یہی تھی کہ ان کے ہاتھ سرخ فیتے سے نہیں بندھے تھے۔
ریمزے کماؤں کے جج، میجسٹریٹ، پولیس، فارسٹ آفیسر اور انجینیر بھی تھے اور ان کی ذمہ داریاں مختلف النوع تھیں اور اکثر ایک کیمپ سے دوسرے کو چلتے ہوئے وہ انہیں سرانجام دیتے جاتے تھے۔ عموماً ان کے ساتھ لوگوں کا ہجوم چلتا تھا اور اسی دوران وہ فوجداری اور دیوانی مقدمات کا فیصلہ کرتے جاتے تھے۔ پہلے مدعی اور گواہان کو سنا جاتا اور پھر ملزم اور اس کے گواہان کو اور پھر مناسب سوچ بچار کے بعد فیصلہ سنایا جاتا جو قید یا جرمانہ بھی ہو سکتا تھا۔ کبھی ان کے فیصلے پر اعتراض نہ ہوا اور نہ ہی جس بندے کو انہوں نے قید یا جرمانے کا فیصلہ سنایا ہو، نے فوراً خزانے جا کر جرمانہ نہ بھرا ہو یا عام قید یا بامشقت کی صورت میں بھی جا کر خود کو نزدیکی جیل داخل نہ کرایا ہو۔ ترائی اور بھابھر کے سپرنٹنڈنٹ ہونے کی وجہ سے انہیں سابق منتظم یعنی سر ریمزے کی نسبت کم ذمہ داریاں ملی ہوئی تھیں مگر ان کے اختیارات زیادہ وسیع تھے۔ شام کو جب بکسر کے کیمپنگ گراؤنڈ میں ہمارے خیمے لگ رہے تھے تو اینڈرسن نے لوگوں کو جمع کر کے سامنے بٹھایا اور کہا کہ وہ ان کی شکایات سننا چاہتے ہیں۔ پہلی شکایت بکسر کے ساتھ والے دیہات کے نمبردار کی تھی۔ اگلی شکایت پیش ہوئی۔
یہ شکایت چاڈی نے پیش کی کہ کالو نے اس کی بیوی تلنی کو اغوا کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ تین ہفتے قبل کالو نے اس کی بیوی کی طرف پیش قدمی کی اور نتیجتاً اس کی بیوی اس کا گھر چھوڑ کر کالو کے گھر رہنے چلی گئی ہے۔ جب اینڈرسن نے پوچھا کہ کالو کہاں ہے تو ہمارے سامنے نیم دائرے کے ایک کنارے سے بندہ اٹھ کر بولا کہ وہ کالو ہے۔
جب اینڈرسن نے کالو سے پوچھا کہ آیا وہ الزام کو تسلیم کرتا ہے تو اس نے بتایا کہ تلنی اس کے گھر رہ رہی ہے مگر اس نے اغوا کی بات سے یکسر انکار کیا۔ جب اینڈرسن نے پوچھا کہ کیا تلنی اپنے شوہر کے پاس واپس بھیج دی جائے تو اس نے بتایا کہ تلنی اپنی مرضی سے آئی ہے، سو وہ اسے واپس جانے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اینڈرسن نے پوچھا: ‘تلنی کہاں ہے؟‘ عورتوں سے ایک لڑکی اٹھ کر سامنے آئی اور بولی: ‘میں تلنی ہوں۔ فرمائیے۔‘
تلنی اٹھارہ برس کی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے بال ترائی کی خواتین کی مانند سر پر ایک فٹ اونچے منارے کی شکل میں تھے اور اس نے سفید گوٹے والی کالی ساڑھی پہن رکھی تھی اور سرخ قمیض، خوبصورت رنگوں والی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ جب اینڈرسن نے پوچھا کہ وہ اپنے شوہر کو کیوں چھوڑ آئی ہے تو اس نے چاڈی کی طرف اشارہ کیا اور بولی: ‘اسے دیکھیں۔ یہ کتنا غلیظ ہے اور کنجوس بھی۔ دو سال سے میں اس کی بیوی ہوں اور اس نے ایک بار بھی کپڑے یا زیور نہیں دیے۔ یہ جو کپڑے اور زیورات آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے کالو نے دیے ہیں۔‘ اس کا اشارہ چاندی کی چوڑیوں اور شیشے کے موتیوں کے کئی ہاروں کی جانب تھا۔ جب اینڈرسن نے پوچھا کہ آیا وہ اپنے شوہر چاڈی کے پاس جانا چاہتی ہے تو اس نے صاف انکار کیا اور بولی کہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں جائے گی۔
یہ مقامی قبیلہ ترائی کے مضرِ صحت مقام پر آباد تھا اور ان کی دو خوبیاں مشہور تھیں۔ ایک ان کی صاف ستھرا رہنے کی عادت اور دوسرا خواتین کا آزاد ہونا۔ ہندوستان کے کسی دوسرے مقام پر لوگ ترائی کی مانند بے داغ کپڑے پہنے نہیں دکھائی دیتے اور نہ ہی کسی اور جگہ کوئی لڑکی اتنی ہمت کرتی کہ مرد و زن کے ہجوم کے سامنے کھڑی ہوتی جس میں دو سفید فام اس کا مقدمہ سن رہے ہوں، اسے اس بات کی اجازت بھی مل پاتی۔ پھر اینڈرسن نے چاڈی سے پوچھا کہ وہ کیا تجویز کرتا ہے تو اس نے جواب دیا: ‘حضور، آپ میرے مائی باپ ہیں۔ میں آپ کے پاس انصاف کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ میری بیوی کو واپس لوٹنے پر مجبور نہیں کر سکتے تو مجھے اس کا معاوضہ دلائیں۔‘ اینڈرسن نے پوچھا: ‘کیا معاوضہ چاہتے ہو؟‘ چاڈی بولا: ‘مجھے ایک سو پچاس روپے چاہییں۔‘ اس پر مجمعے میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ ‘بہت زیادہ ہے۔ ‘اتنا زیادہ معاوضہ؟‘ ‘اس کی یہ قیمت غلط ہے۔‘ جب اینڈرسن نے کالو سے پوچھا کہ آیا وہ تلنی کے لیے ڈیڑھ سو روپے ادا کرنے کو تیار ہے تو اس نے جواب دیا کہ یہ قیمت بہت زیادہ ہے اور بتایا کہ بکسر کے ہر انسان کو علم ہے کہ چاڈی نے تلنی کے ایک سو روپے دیے تھے۔ اس نے دلیل دی کہ ایک سو روپے ‘کنواری‘ کے تھے اور چونکہ اب وہ کنواری نہیں ہے، سو وہ محض پچاس روپے ادا کرے گا۔ اب مجمع دو حصوں میں بٹ گیا۔ کچھ کا خیال تھا کہ ڈیڑھ سو روپے بہت زیادہ ہیں اور کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ پچاس روپے بہت کم ہیں۔
آخرکار دونوں اطراف کی باتیں سن کر، جن میں انتہائی باریک اور ذاتی تفاصیل بھی شامل تھیں اور جنہیں تلنی نے انتہائی دلچسپی سے سنا، اینڈرسن نے تلنی کی قیمت 75 روپے مقرر کی، جو کالو نے چاڈی کو دینے تھے۔ کالو نے نیفے سے تھیلی نکال کر اینڈرسن کے سامنے قالین پر خالی کر دی۔ کل رقم چاندی کے باون کلدار روپے بنی۔ پھر کالو کے دو دوست اس کی مدد کو آئے اور تیئس روپے شامل کر دیے اور اینڈرسن نے چاڈی کو رقم لینے کا کہا۔ جب اس نے رقم گن کر تسلی کر لی تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت جو بہت کمزور تھی اور انتہائی تکلیف سے چل کر گاؤں سے ہماری جانب آئی تھی اور دیگر لوگوں سے ہٹ کر بیٹھی رہی، بمشکل اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی: ‘اور میرا کیا ہوگا مائی باپ؟‘ اینڈرسن نے پوچھا: ‘تم کون ہو؟‘ اس نے جواب دیا: ‘میں کالو کی بیوی ہوں۔‘
یہ طویل قامت اور انتہائی کمزور خاتون تھی جس کے تن سے جیسے تمام تر لہو نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا اور انتہائی بڑھی ہوئی تلی کی وجہ سے اس کا پیٹ نکلا اور پیر سوجے ہوئے تھے جو ملیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ترائی میں ملیریا کی بیماری عام ہے۔ تھکی ہوئی آواز میں اس نے بتایا کہ اب کالو نے دوسری بیوی خرید لی ہے تو وہ بے گھر ہو جائے گی۔ چونکہ اس کے کوئی رشتہ دار اس گاؤں میں نہیں رہتے اور بیماری کی وجہ سے وہ کام کے قابل بھی نہیں رہی تو وہ عدم توجہی اور بھوک سے مر جائے گی۔ پھر اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا اور سسکیاں لینے لگی۔ اس کا پورا بدن لرز رہا تھا اور آنسو نیچے گر رہے تھے۔
یہ غیر متوقع اور پیچیدہ صورتحال تھی اور اینڈرسن کے لیے اس کا حل نکالنا آسان نہ تھا۔ جتنی دیر کالو کا مقدمہ چلتا رہا، کسی نے اشارتاً بھی کالو کی پہلی بیوی کا نہیں بتایا تھا۔ اس عورت کی تکلیف دہ سسکیوں کو زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ تلنی جو ابھی تک کھڑی تھی، بھاگ کر اس بیچاری عورت کے قریب گئی اور اسے اپنی بانہوں میں لے کر بولی: ‘بہن، رو مت۔ ایسے مت کہو کہ تم بے گھر ہو، میں کالو کے دیے ہوئے جھونپڑے میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور میں خود تمہارا خیال رکھوں گی اور کالو جو بھی مجھے دے گا، اس میں سے آدھا تمہارا ہوگا۔ میری بہن، مت رو۔ آؤ میرے ساتھ میرے جھونپڑے کو چلو۔‘
جب تلنی اور بیمار خاتون چلی گئیں تو اینڈرسن نے کھڑے ہو کر زور سے اپنا ناک صاف کیا اور کہا کہ پہاڑی ہوا بہت سرد ہے اور آج کی سماعت یہیں تمام ہوتی ہے۔ شاید پہاڑی ہوا نے دیگر افراد پر بھی اینڈرسن کی طرح اثر کیا تھا کیونکہ بہت سارے دیگر لوگ بھی اپنا ناک صاف کر رہے تھے۔ مگر سماعت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ چاڈی اینڈرسن کے پاس پہنچ کر بولا کہ وہ اپنا مقدمہ واپس لیتا ہے۔ اس نے اپنی عرضی پھاڑ ڈالی اور اپنے نیفے سے پچہتر روپے نکال کر بولا: ‘کالو اور میں ایک ہی گاؤں سے ہیں اور اب چونکہ اس نے دو پیٹ بھرنے ہیں اور ایک کو زیادہ طاقت والی خوراک درکار ہے، سو اسے یہ رقم درکار ہوگی۔ مائی باپ، آپ کی اجازت سے میں یہ رقم اسے واپس کرتا ہوں۔‘
سرخ فیتے سے قبل اینڈرسن نے باہمی اتفاق سے سیکڑوں، بلکہ ہزاروں ایسے مقدمات نمٹائے تھے جن میں فریقین کو ایک پائی کی فیس بھی ادا نہیں کرنی پڑی۔ چونکہ اب سرخ فیتہ متعارف ہو چلا ہے، سو ان مقدمات کو عدالت لے جانا پڑتا ہے اور اس دوران فریقین سے بھاری خراج وصول کیا جاتا ہے جہاں سے نفرت اگتی ہے اور نتیجتاً مزید مقدمات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو غریب، سادہ اور ایماندار محنت کشوں کو دیوالیہ اور وکلاء کو امیر بناتا جاتا ہے۔