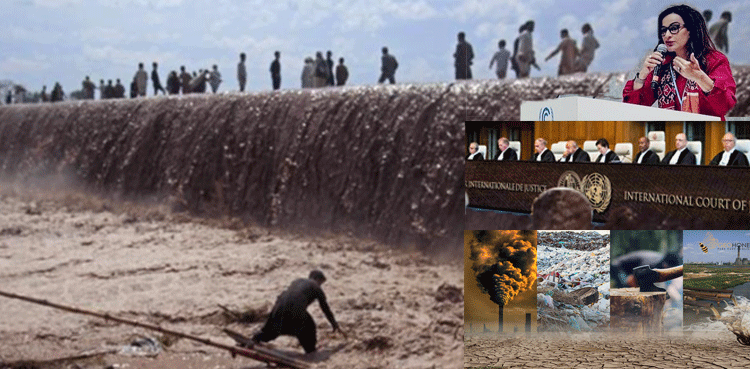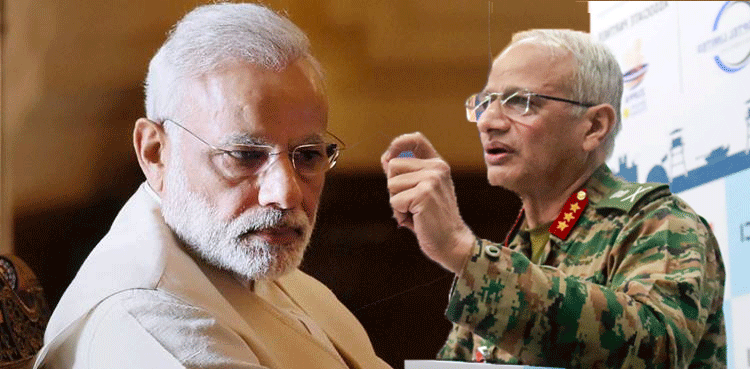کراچی شہر ملک کی ترقی کا انجن ہے اور اسے ملک کا سب سے بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ دنیا میں جو شہر ایسی اہمیت اور حییثت رکھتے ہیں وہاں کی حکومتیں ان کے انفرااسٹرکچر پر خاص توجہ دیتی ہیں اور ان کی تعمیر کی جاتی ہے۔ مگر کراچی کیا ہے اس کا اندازہ آپ 19 اگست کی برسات سے لگا سکتے ہیں۔
اس دن میں معمول کے مطابق دفتر پہنچا اور کام میں مشغول ہوگیا۔ ہمارے دفتر کی ایک ساتھی نے جب بلانئنڈز ہٹائے تو شیشے کے پیچھے سے گہرے کالے رنگ کے بادل ہمیں گھور رہے تھے۔ آن کی آن میں ان بادلوں نے برسنا بھی شروع کر دیا۔ اس قدر جم کر برسے کہ چند ہی منٹ میں جل اور تھل ایک ہوگیا۔ انتظامیہ نے دفتر کو بند کرنے اور تمام ملازمین کو گھرجانے کی اجازت دے دی۔ ابھی بارش جاری تھی کہ میں نے گھر کی راہ لی کیونکہ خدشہ تھا کہ جس قدر تیز بارش ہوئی ہے اس کے بعد شہر کی سب سے بڑی سڑک، شارع فیصل سے گزرنا محال ہوجائے گا۔ جیسے تیسے بلوچ کالونی کے راستے شارع فیصل پر داخل ہوا تو ٹریفک سست روی کا شکار تھا۔ کارساز پر آکر دیکھا تو میرے اوسان ہی خطا ہوگئے۔ سر شاہ سلمان روڈ سے پانی ریلے کی صورت میں شارع فیصل پر آرہا ہے۔ اور پانی اس قدر تیزی سے آرہا ہے کہ چھوٹی اور کم وزنی گاڑیاں تو بہنے لگی ہیں۔
اس صورتحال میں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر تو سفر کرنا ناممکن تھا۔ موٹر سائیکل بند کی۔ اور پانی میں اپنا سفر شروع کر دیا۔ اس دن اندازہ ہوا کہ گھٹنوں گھٹنوں پانی میں 150 سی سی موٹر سائیکل کو گھسیٹنا کتنا مشکل کام ہے۔ پانی کی وجہ سے گاڑیاں بند ہو رہی تھیں جن میں خواتین، بچے، مرد، بوڑھے سب ہی بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ اسکول کے بچوں کی وینز بھی پانی میں پھنسی تھیں۔ مگر وہ پریشان ہونے کے بجائے اس صورتحال کا خوب لطف لے رہے تھے۔ بہرحال موٹر سائیکل کو گھسیٹتے گھسیٹتے بڑھتا رہا اور جہاں پانی کم دیکھا وہاں اسے اسٹارٹ کر کے سوار ہوجاتا۔ مگر کارساز پر تو سیلاب کا صرف ایک ریلا تھا۔ اصل سیلاب تو ڈرگ روڈ جنکشن پر منتظر تھا۔ جہاں پہنچ کر موٹر سائیکل احیتاطاً بند کر دی اور اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔
اس بارش اور سیلابی صورت حال میں وہ لوگ جن کے پاس ڈبل کیبن یا ایس یو وی گاڑیاں تھیں مزے سے پانی میں گاڑیاں چلا رہے تھے۔ ان گزرتی گاڑیوں سے اس سیل رواں میں مزید لہریں پیدا ہوتیں اور ہم جیسے سڑک چھاپوں کی مشکل بڑھ جاتی۔ ایک موقع پر تو لہر اس قدر تیزی سے آئی کہ ہاتھ سے بائیک چھوٹ کر پانی میں ڈوب گئی۔ ایک لڑکے نے نہ صرف موٹر سائیکل کو اٹھانے میں مدد کی بلکہ کچھ دور دھکیل کر کسی قدر راحت بھی پہنچائی۔ پیدل چلتے چلتے کالونی گیٹ پہنچے جہاں ہمارے ایک جاننے والے کی دکان تھی۔ ان سے درخواست کی اور موٹر سائیکل کو وہیں کھڑا کر دیا اور ریلوے لائن پر چڑھ کر گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ اس ریلوے لائن پر سیکڑوں لوگ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ان میں خواتین بھی شامل تھیں جو پیدل سامان اٹھائے اور کچھ بچے سنبھالے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھیں۔
ریلوے لائن پر چلتے چلتے جب میں گھر کے قریب پہنچا تو اندازہ ہوا کہ ابھی مشکل ختم نہیں ہوئی ہے۔ ایئر پورٹ کی طرف سے آنے والا بارش کے پانی کا ریلا گھر کے اندر بھی داخل ہوچکا ہے۔ اور گراؤنڈ فلور پر کئی کئی فٹ پانی کھڑا تھا۔ مگر اس صورت حال کے باوجود میں نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ میں گھر پہنچ گیا تھا۔ جب کہ میرے دفتر کے چند ساتھی رات گئے تک سڑکوں پر برے حال میں پھسنے رہے اور بہت تکلیف اٹھا کر کسی وقت گھر پہنچ سکے۔
شہر میں ہونے والی تیز بارش کے بعد شارع فیصل مکمل طور پر بند ہوگئی تھی اور ایئر پورٹ، اور دونوں بندرگاہوں کا راستہ گویا منقطع ہو گیا تھا۔ کئی پروازیں عملے اور مسافروں کے نہ پہنچنے کی وجہ سے منسوخ کر دی گئی تھیں۔ کم و بیش یہی صورت حال شہر کے دیگر علاقوں کی سڑکوں کی تھی۔
گھر کا کیا حال سنائیں رات گئے جیسے ہی پانی اترا تو وہ اپنے پیچھے ڈھیروں مٹی اور کیچڑ چھوڑ گیا جس کو صاف کرنے میں چند دن لگے۔ فرنیچر اور دیگر اشیاء کا نقصان الگ ہوا۔ نقصان جتنا بھی ہو اور مشکلات جیسی بھی ہوں زندگی رکتی نہیں ہے۔ اس بارش اور اس تکلیف دہ صورت حال کے چند روز بعد اسلام آباد اور لاہور کا سفر کرنا تھا۔ اسلام آباد کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر معلوم چلا کہ بادل تو وہاں بھی برسا ہے اور خوب جم کر برسا ہے۔ مگر کوئی سڑک زیر آب نہیں آئی، کہیں گڑھے میں کوئی گاڑی پھنسی نہیں تھی۔ دل نے کہا یہ تو اسلام آباد ہے اصل مشکل کا سامنا تو لاہور میں ہوگا۔
جب لاہور کے لیے سفر شروع ہوا راستے میں اطلاع ملی کہ راوی بپھر گیا ہے۔ اور جو لوگ اس کو دریا کے بجائے گندا نالہ کہہ رہے تھے۔ راوی انہیں اپنی بپھری ہوئی موجوں سے بتا رہا تھا کہ وہ راوی ہے جس کے کنارے پر لاہوریوں کی تہذیب اور تمدن نے جنم لیا ہے۔
لاہور میں سیلاب کا سن کر ہمارے دل پر ایک خوف چھا گیا کہ کہیں کراچی جیسا حشر نہ ہو۔ مگر لاہور میں جیسے ہی داخل ہوئے تو کہیں بھی سیلاب کا شائبہ تک نہ تھا۔ ٹی وی لگایا تو خبریں یہی چل رہی تھیں کہ لاہور ڈوب گیا ہے۔ ہم نے سوچا کہ شاید ہم جہاں ٹھرے ہیں وہاں سیلاب نہ ہو۔ مگر اگلے دن لاہور کے مخلتف علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ کہیں ایسی سیلابی صورت حال نہ تھی۔ نشیبی اور اولڈ ایریاز خواہ کراچی کے ہوں یا لاہور کے تیز بارش سے ضرور متاثر ہوتے ہیں، مگر جب ہم بات کرتے ہیں مرکزی شاہ راہوں اور سڑکوں کی تو ان شہروں میں صورت حال بالکل مختلف دیکھی گئی۔ لاہور میں سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں تھا۔ سیلاب صرف راوی دریا کے پاٹ کے اندر قبضہ کر لینے والوں کے لیے تھا، چاہے وہ شاہدرہ کا علاقہ ہو یا پھر نجی ہاؤسنگ سوسائیٹیز، یہ سب پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ راوی کا موجیں مارتا دریا ان لوگوں کو منہ چڑا رہا تھا جو کہتے تھے کہ راوی ایک گندا نالہ بن گیا ہے۔ بہتر ہے کہ اس کے پاٹ میں زراعت اور مویشی پروری کرنے والوں کو بے دخل کر کے وہاں ہاؤسنگ سوسائیٹیز بنائی جائیں۔
دوسرے دن کراچی کی طرح بادل جم کر برسنے لگے تو سوچا کہ اب تو آج کی تمام میٹنگز منسوخ کر کے جیم خانہ کے کمرے میں ہی دن گزارنا ہوگا۔ مگر بارش کے باوجود سڑک پر پانی نہ ہونے کے برابر تھا۔ جب کہ ٹریفک تقریباً معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ ڈرائیور بھی سڑک پر گڑھا ہونے کے خوف کے بغیر گاڑی کو چلا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ لاہور لاہور ہے۔ اس پر گزشتہ 30 سال میں جو سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ اس نے ایک دیہی شہر کو ایک ایسے قابل رہائش شہر میں تبدیل کر دیا ہے جہاں بارش سے خوف زدہ ہونے کے بجائے لطف اٹھایا جاسکتا ہے۔
اسلام آباد اور لاہور میں مصروفیات ختم ہوئیں تو اپنے شہر کراچی کے لیے روانہ ہوا۔ گھر کے راستے میں ٹریفک جام پایا۔ دریافت کرنے پر انکشاف ہوا کہ بارش کو ہوئے دوسرا ہفتہ ہے مگر شارع فیصل کو ملیر ہالٹ کے مقام سے موٹر وے سے ملانے والی سڑک کچھ جگہ سے بیٹھ گئی ہے۔ سڑک پر گڑھے پڑے ہیں جن میں بارش اور بارش کی وجہ سے ابلنے والے گٹروں کا پانی موجود ہے جس کی وجہ سے گھنٹوں ٹریفک جام رہنے لگا ہے۔
یہ حال ملک کے دو شہروں کا ہے، ایک میں اگر بارش ہوجائے تو زندگی مفلوج ہوجاتی ہے۔ دوسرے میں شہر میں مرکزی راستے اور سڑکوں پر زندگی رواں دواں رہتی ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ لاہور والوں نے راوی کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، اس کا بدلہ راوی نے اس مرتبہ لے لیا ہے۔ ادھر کراچی کے شہری اپنے شہر کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے ہیں، اس کا بدلہ شہر میں ہونے والی ہر بارش لیتی ہے۔