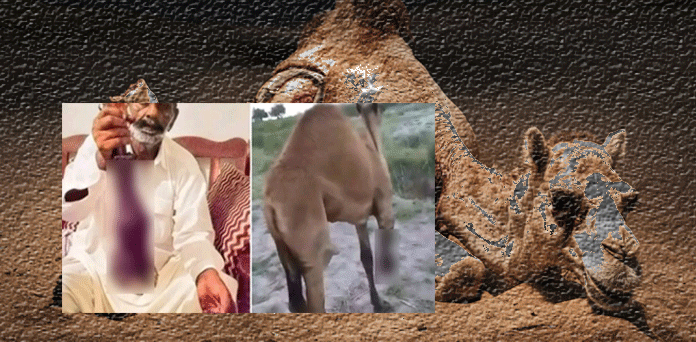دنیا بھر میں مقبولیت کا نیا اور منفرد ریکارڈ قائم کرنے والی یہ ویب سیریز شوگن ہمیں سترہویں صدی کے جاپان میں لے جاتی ہے جہاں حکمرانی اور اثر و رسوخ کے لیے طاقت کا استعمال دکھایا گیا ہے اور کرداروں کے ذریعے کہانی آگے بڑھتے ہوئے آپ کی توجہ اور دل چسپی سمیٹ لیتی ہے۔
 دنیا بھر میں اس وقت یہ ویب سیریز دیکھی جارہی ہے اور اس نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ 80 کی دہائی میں اسی کہانی پر ایک مختصر ڈراما سیریز بنی تھی، جس کو پاکستان ٹیلی وژن پر بھی قسط وار دکھایا گیا تھا۔ سترہویں صدی کے جاپان پر مبنی امریکی ویب سیریز کا اردو میں یہ واحد مفصل تجزیہ اور باریک بینی سے کیا گیا تبصرہ پیشِ خدمت ہے۔
دنیا بھر میں اس وقت یہ ویب سیریز دیکھی جارہی ہے اور اس نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ 80 کی دہائی میں اسی کہانی پر ایک مختصر ڈراما سیریز بنی تھی، جس کو پاکستان ٹیلی وژن پر بھی قسط وار دکھایا گیا تھا۔ سترہویں صدی کے جاپان پر مبنی امریکی ویب سیریز کا اردو میں یہ واحد مفصل تجزیہ اور باریک بینی سے کیا گیا تبصرہ پیشِ خدمت ہے۔
شوگن کیا ہے؟
جاپانی تاریخ میں شوگن کی اصطلاح، فوجی سربراہ کے لیے بطور لقب استعمال ہوتی تھی اور یہی ملک کا حقیقی حکمران ہوا کرتا تھا۔ یہ لقب سب سے پہلے ہئین دور میں استعمال ہوا، جو کسی کامیاب جنگی مہم کے بعد متعلقہ جنرل کو دیا گیا۔ جب 1185ء میں میناموتویوری تومو نے جاپان پر فوجی کنٹرول حاصل کیا، تو اقتدار سنبھالنے کے سات سال بعد انہوں نے شوگن کا لقب اختیار کیا۔ جاپان کی قدیم تاریخ میں شوگن سے مراد ملک کا سربراہ اور دھرتی کا سب سے طاقتور فرد ہوا کرتا تھا۔ جاپان میں 1867ء کو سیاسی انقلاب برپا ہونے اور جاگیر دارانہ نظام کے خاتمے تک، یہ لقب اور اس سے جڑے افراد، جاپانی تاریخ کے اصل حکمران اور فوجی طاقت کا محور ہوئے۔ مذکورہ ویب سیریز کی کہانی میں ایسی ہی چند طاقت ور شخصیات کی اس اہم ترین عہدے کو پانے اور قائم رکھنے کے لیے لڑائیاں اور تصادم دکھایا گیا ہے۔
پرانی ڈراما سیریز شوگن اور نئی ویب سیریز شوگن کا موازنہ
یہ ذہن نشین رہے کہ پروڈکشن کے شعبے میں ڈراما سیریز کے لیے اب نئی اصطلاح، ویب سیریز ہے۔ اس میں فرق اتنا ہے کہ پہلے کسی بھی کہانی کو اقساط کی صورت میں ٹیلی وژن کے لیے تیار کیا جاتا تھا اور اب اس کو کسی اسٹریمنگ پورٹل کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے۔ 80 کی دہائی کی شوگن اور عہدِ حاضر میں بنائی گئی شوگن میں بڑا فرق کہانی کی طوالت کا ہے۔
پرانی شوگن محدود اقساط پر مبنی ڈراما سیریز تھی، جب کہ موجودہ شوگن کے تین سیزن تیار کیے جائیں گے۔ ابھی پہلا سیزن بعنوان شوگن ہولو اسٹریمنگ پورٹل پر ریلیز کیا گیا ہے۔ اس مساوی کہانی کے دو مختلف پروڈکشن میں 64 ایسے نکات ہیں، جن کو تبدیل کیا گیا ہے، اس فرق کو سمجھانے کے لیے ہم نیچے ایک لنک دے رہے ہیں جس پر کلک کر کے آپ یہ فرق آسانی سے سمجھ سکیں گے۔
پروڈکشن اور دیگر اہم تفصیلات
امریکی پروڈکشن ادارے ایف ایکس نے پرانی کہانی پر ہی دوبارہ شوگن بنانے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس ویب سیریز کی مکمل پروڈکشن چار بڑی کمپنیوں کے اشتراک سے ممکن ہوئی ہے۔ ان چار کمپنیوں کے نام بالترتیب ڈی این اے فلمز، ایف ایکس پروڈکشنز، گیٹ تھرٹی فور پروڈکشنز اور مچل ڈے لوسا ہیں۔ اس کے لیے دس سے زائد پروڈیوسروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، جن میں مذکورہ ویب سیریز میں مرکزی کردار نبھانے والے جاپانی فلمی ستارے ہیروکی سنادا بھی شامل ہیں۔ اس ویب سیریز کی پروڈکشن ٹیم کا بڑا حصہ امریکی اور جاپانی فلم سازوں کے بعد اسکاٹش اور آئرش فلم سازوں پر مشتمل ہے، جو دل چسپ بات ہے۔ اس ویب سیریز کو جاپان اور کینیڈا میں پونے دو سال کے عرصہ میں فلمایا گیا ہے۔ شوگن، امریکی پروڈکشن ہاؤس ایف ایکس کی تاریخ کی سب سے مہنگی پروڈکشن ہے، اور اسے امریکی ٹیلی وژن ایف ایکس کے ساتھ ساتھ اسٹریمنگ پورٹلز اسٹار پلس، ڈزنی پلس اور ہولو پر ریلیز کیا گیا ہے۔

جاپان سمیت پوری دنیا میں اس ویب سیریز کو بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔ اس ویب سیریز کے پروڈیوسرز میں سے ایک جاپانی پروڈیوسر اور عالمی شہرت یافتہ اداکار ہیروکی سنادا کا کہنا ہے، "ہالی ووڈ میں بیس سال کے بعد، میں ایک پروڈیوسر ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، کسی بھی وقت۔ میرے پاس پہلی بار ایک ٹیم تھی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر، مجھے خوشی تھی۔” انہوں نے شو کو جاپانی تاریخ کے تناظر میں مستند حالات و واقعات سے مربوط رکھنے پر توجہ دی۔ "اگر کہانی میں کچھ غلط ہے تو لوگ ڈرامے پر توجہ نہیں دے سکتے۔ وہ اس قسم کا شو نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہمیں مستند کام کرنے کی ضرورت ہے۔” ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ کچھ ڈرے ہوئے تھے کہ نجانے جاپانی ناظرین اسے کس طرح سے دیکھیں گے، لیکن ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ جاپانی ناظرین اسے اتنا پسند کریں گے۔ وہ جاپان میں اس مقبولیت پر بے حد مسرور ہیں۔ اس ویب سیریز کے بنیادی شعبوں میں آرٹسٹوں اور ہنرمندوں نے متاثرکن کام کیا ہے، خاص طورپر موسیقی، ملبوسات، صوتی و بصری تاثرات، تدوین اور چند دیگر شعبہ جات اس میں شامل ہیں۔
مقبولیت کے نئے پیمانے
فلموں کی معروف ویب سائٹ آئی ایم ڈی بی پر اس ویب سیریز کی درجہ بندی دس میں سے آٹھ اعشاریہ سات ہے۔ فلمی ناقدین کی ویب سائٹ روٹین ٹماٹوز پر اسے 100 میں سے 99 فیصد کے غیرمعمولی تناسب سے پسند کیا گیا ہے اور بہت کم فلموں کے لیے یہ شرح تناسب دیکھنے میں آتا ہے۔ فلم افینٹی جو امریکی و برطانوی فلمی ویب سائٹ ہے، اس نے درجہ بندی میں اس ویب سیریز کو 10 میں سے 7.6 فیصد پر رکھا ہوا ہے۔ گوگل کے صارفین کی بات کریں تو وہاں ویب سیریز کی شرحِ پسندیدگی کا تناسب سو میں سے پچانوے فیصد ہے اور ویب سیریز کی یہ ستائش اور پذیرائی بھی انتہائی غیر معمولی ہے اور تادمِ تحریر یہ ویب سیریز مقبولیت اور پسندیدگی کی بلندیوں کی طرف ہی بڑھ رہی ہے اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مقبولیت کی نئی تاریخ رقم ہوگی۔ ویب سیریز کے ناظرین کی پسندیدگی تو ایک طرف، دنیا بھر کے فلمی ناقدین بھی اس ویب سیریز کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔
ڈائریکشن اور اسکرپٹ
اس ویب سیریز کے ڈائریکٹر امریکی فلم ساز ٹم وین پیٹن ہیں، جن کے کریڈٹ پر گیمز آف تھرونز اور سیکس اینڈ سٹی جیسے تخلیقی شاہکار ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دی وائر اور بلیک مرر جیسی ویب سیریز کے بھی ہدایت کار رہ چکے ہیں۔ ریچل کوندو اور جسٹن مارکس کے تخلیق کردہ اس شاہکار کو اپنی ہدایت کاری سے انہوں نے گویا چار چاند لگا دیے ہیں۔
ویب سیریز کی کہانی کا مرکزی خیال 1975ء میں شائع ہونے والے ناول شوگن سے لیا گیا، جس کے مصنف جیمز کلیویل ہیں۔ یہ دوسری عالمی جنگ میں، برطانیہ کی طرف سے سنگاپور میں جاپانیوں سے لڑے اور وہاں جنگی قیدی بھی بنے۔ شاید یہی ان کی زندگی کا موقع تھا، جس کی وجہ سے انہیں جاپانی تاریخ سے دل چسپی پیدا ہوئی اور انہوں نے جاپان کے تناظر میں چھ ناولوں کی ایک سیریز لکھی، جن میں سے ایک ناول شوگن کے نام سے شائع ہوا۔ اس ناول پر ویب سیریز کا اسکرپٹ لکھنے والوں میں آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والے اسکرپٹ رائٹر رونن بینٹ کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔

مرکزی خیال و کہانی
اس ویب سیریز کی کہانی کا آغاز سنہ 1600ء کے جاپان سے ہوتا ہے اور یہ اس کا پہلا سیزن ہے۔ فلم ساز ادارے نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مزید دو سیزن بنیں گے، تو میرا یہ اندازہ ہے کہ اس ویب سیریز کی کہانی کو جاپان میں جاگیردارانہ نظام کے خاتمے تک فلمایا جائے گا۔
پہلے سیزن میں اُس دور کی ابتدا کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اُس وقت کے جاپان کے مرکزی رہنما کی رحلت کے بعد سیاسی طاقت پانچ ایسے نگرانوں میں مساوی تقسیم ہو جاتی ہے، جن کو ریجنٹس کہا گیا ہے، کیونکہ وہ پانچوں اس مرکزی حکمران کے بچے کی حفاظت پر مامور ہیں، جو اوساکا کے شاہی قلعہ میں پرورش پا رہا ہے۔ اس کے بالغ ہونے تک یہ طاقت ان پانچ نگرانوں کے پاس ہے اور وہ ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔
اس منظر نامے میں ایک انگریز ملاح بھی اس وقت شامل ہو جاتا ہے، جب اس کا ولندیزی جہاز، ایک سمندری طوفان کے نتیجے میں بھٹک کر جاپان کے ساحل کی طرف آ نکلتا ہے۔ یہ کردار انگریز جہاز راں ولیم ایڈمز سے منعکس ہے۔ دکھایا گیا ہے کہ اس برطانوی جہاز راں کو گرفتار کرلیا جاتا ہے لیکن وہ جاپان کے سیاسی منظر نامے کی اہم ترین شخصیت اور پانچ نگراں حکمرانوں کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی بعض خوبیوں اور بالخصوص عسکری مہارتوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ اس حکمران کی قربت حاصل کرنے میں کام یاب ہوجاتا ہے یہ وہ نگران حکمران ہے جس کا تعلق ایدو (ٹوکیو کا قدیم نام) سے ہے، اور دوسرے نگراں حکمران اس کے بڑے سخت مخالف ہیں، اور یہ اُن سے نبرد آزما ہے۔ ایدو سے تعلق رکھنے والے اس حکمران کی سپاہ میں بھی جہاز راں کی عسکری مہارتوں کا چرچا ہوتا ہے اور وہ ان کی نظر میں بھی مقام حآصل کرلیتا ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ اسے ایک اعلٰی عسکری عہدہ سونپ دیا جاتا ہے جس کے بعد وہ ان کے ساتھ مل کر جنگی مہمات کا حصہ بنتا ہے۔ اس طرح ایک غیر جاپانی کو سمورائی کا درجہ مل جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ایدو سے تعلق رکھنے والا یہ پہلا شوگن ہے، جس کی زندگی کو مدنظر رکھتے ہوئے اس پہلے سیزن کی کہانی کا تانا بانا بنا گیا ہے۔

اس طرح کہانی میں آگے چل کر یہ پانچوں نگراں و مساوی حکمراں، انگریز جہاز راں، پرتگالی تاجر، کیتھولک چرچ کے نمائندے، سیاسی اشرافیہ سے وابستہ دیگر ذیلی کردار شامل ہوتے ہیں اور خاص طور پر ایک جاپانی خاتون کا کردار جو لیڈی تودا مریکو کہلاتی ہے، بھی اس کہانی میں نمایاں ہے اور یہ کردار ناظرین کو اپنے ساتھ اس طرح جوڑے رکھتا ہے کہ دس اقساط کب تمام ہوئیں، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ان حکمرانوں کی کہانی میں جو روانی اور ربط ہے، اس پر اگر اس ویب سیریز کے لکھاری قابل ستائش ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ وہ ناول نگار قابلِ تعریف ہے، جس نے جاپان کی تاریخ میں اتر کر، کہانی کو اس کی بنیاد سے اٹھایا۔ کہنے کو تو یہ خیالی کہانی (فکشن) ہے، مگر اس کے بہت سارے کردار اور واقعات جاپانی تاریخ سے لیے گئے ہیں اور وہ مستند اور حقیقی ہیں۔
 اداکاری
اداکاری
اس ویب سیریز میں مرکزی کرداروں کی بات کی جائے تو وہ تعداد میں درجن بھر ہیں۔ ان میں سے جن فن کاروں نے بے مثال کام کیا، ان میں ہیروکی سنادا (لارڈ یوشی توراناگاوا)، کوسمو جارویس (جان بلیک تھرون)، اننا ساوائی (لیڈی تودامریکو)، تادانوبو (کاشی گی یابوشیگے) تاکے ہیرو ہیرا (اشیدوکازوناری) اور دیگر شامل ہیں۔ ذیلی کرداروں میں دو درجن کردار ایسے ہیں، جنہوں نے اپنی اداکاری سے اس تاریخی ویب سیریز میں انفرادیت کے رنگ بھر دیے ہیں۔برطانوی اداکار کوسمو جارویس اور جاپانی اداکارہ اننا ساوائی کو اس کہانی کا ہیرو ہیروئن مان لیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے کہانی میں ناظرین کی دل چسپی برقرار رہتی ہے جب کہ ہیروکی سنادا اور تادانوبو نے بھی ناظرین کو اپنی شان دار اداکاری کی بدولت جکڑے رکھا۔ دو مزید جاپانی اداکاراؤں موئیکا ہوشی اور یوکاکووری نے بھی متاثر کن اداکاری کی ہے۔ ان کو داد نہ دینا بڑی ناانصافی کی بات ہو گی۔ مجموعی طور پر اس ویب سیریز میں سیکڑوں فن کاروں نے حصہ لیا، جن میں اکثریت جاپانی اداکاروں کی ہے۔ سب نے بلاشبہ اپنے کرداروں سے انصاف کیا، یہی وجہ ہے کہ ویب سیریز نے ناظرین کے دل میں گھر کر لیا۔
حرف آخر
قارئین، اگر آپ عالمی سینما اور خاص طور پر کلاسیکی سینما کے پسند کرنے والے ہیں اور اس پر مستزاد آپ کو جاپان کی کلاسیکی ثقافت میں بھی دل چسپی ہے تو پھر یہ ویب سیریز آپ کے لیے ہی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے آپ جاپان کی قدیم معاشرت، سیاست، ثقافت اور تہذیب کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھ سکیں گے۔ خوبصورت جاپان کے ساتھ اس ویب سیریز میں آپ جاپانی عورتوں کا حسن و جمال اور خوب صورتی بھی دیکھیں گے۔ ویب سیریز کے اس تعارف اور تفصیلی تبصرے کو میری طرف سے اس عید پر ایک تحفہ سمجھیے۔ اسے ضرور دیکھیے، آپ کی عید کی چھٹیوں کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔