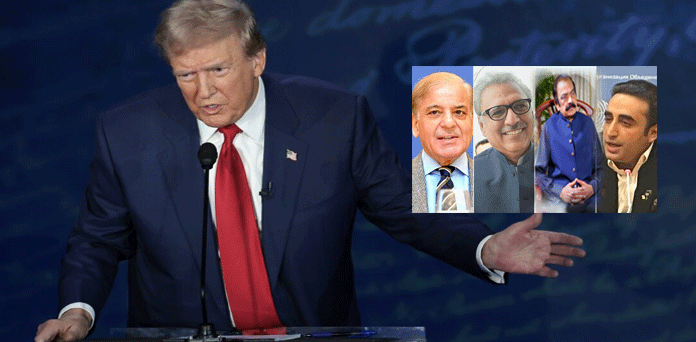جاپان ایک ایسا ایشیائی ملک ہے، جہاں ایک صدی سے زیادہ عرصہ سے اردو کی تدریس جاری و ساری ہے۔ جاپان کے دو بڑے شہر اردو زبان کے فروغ کا مرکز رہے ہیں، جن کے نام ٹوکیو اور اوساکا ہیں اور یہاں کی جامعات سے اب تک سیکڑوں طلبا اردو کے مضمون میں سند یافتہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے آگے چل کر تدریس، سفارت کاری سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی میں نام کمایا۔ آج جاپان اور پاکستان کے درمیان مضبوط تعلق کی ایک وجہ زبان بھی ہے۔
جاپان میں اردو کے ابتدائی نقوش
اردو کا اوّلین مرکز ٹوکیو ہے، جہاں باقاعدہ طور پر 1908 میں تدریس کی غرض سے ٹوکیو اسکول آف فارن لینگویجز کی بنیاد رکھی گئی، جس میں دنیا بھر کی زبانوں سمیت اردو کی تعلیم کے لیے ’شعبۂ ہندوستانی‘ قائم ہوا، جس میں داخلہ لینے والے جاپانی طلبا کی تعداد پانچ تھی۔ 1911 میں شعبۂ ہندوستانی کو ترقی دی گئی اور اس کے پہلے مہمان استاد مولانا برکت اللہ تھے جو معروف علمی شخصیت محمود الحسن کے کہنے پر جاپان تدریس کی غرض سے گئے تھے۔
جاپان میں ٹوکیو اسکول آف فارن لینگویجز کے شعبۂ ہندوستانی کے اوّلین استاد پروفیسر انوئی تھے جو تین برس تک اس شعبے سے وابستہ رہے، پھر ان کے بعد نمایاں استاد پروفیسر ریچی گامو ہیں، جن کا 1925 میں باقاعدہ طور پر جاپانی پروفیسر کی حیثیت سے شعبۂ اردو کے لیے تقرر ہوا۔ وہ اردو کی کلاسیکی داستان ’باغ و بہار‘ کے مترجم بھی تھے۔ جاپان میں پروفیسر گامو کو قبل از تقسیم ‘بابائے اردو’ کہا جاتا تھا۔ ان کے بعد پروفیسر تاکیشی سوزوکی بھی اردو تدریس کا ایک بڑا نام ہیں، جنہوں نے پہلی اردو جاپانی لغت پر کام کیا، اور تقسیمِ ہند کے بعد جاپان میں "بابائے اردو” کہلائے۔ ان دونوں بڑی شخصیات کے بعد غالب، اقبال، فیض کے کلیات کے جاپانی مترجم اور منٹو سمیت کئی بڑے ادیبوں کی کہانیوں کو جاپانی زبان میں ڈھالنے والے اردو اسکالر پروفیسر ہیروجی کتاؤکا ہیں، جن کی اردو سے وابستگی کا عرصہ پانچ دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔
1947 میں برِصغیر کی تقسیم کے بعد شعبۂ ہندوستانی کا نام تبدیل ہو کر شعبۂ اردو ہو گیا۔ 1949 میں ٹوکیو اسکول آف فارن لینگویجز کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا، جس میں شعبۂ ہندوستانی، دو مختلف شعبوں شعبۂ ہندی اور شعبۂ اردو میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب یہ تعلیمی ادارہ ٹوکیو یونیورسٹی آف فارن اسٹڈیز کہلاتا ہے، جس کے موجودہ سربراہ شعبۂ اردو جناب کین ساکو مامیا ہیں۔

ٹوکیو اور اوساکا میں جو دیگر اردو کے جاپانی استاد نمایاں رہے، ان میں پروفیسر ساوا، پروفیسر جین، پروفیسر ہیروشی کان گایا، پروفیسر تسونیو ہماگچی، پروفیسر ہیروشی ہاگیتا، پروفیسر اسادا، پروفیسر میتسومورا، پروفیسر سویامانے اور دیگر شامل ہیں۔
کراچی میں کین ساکو مامیا سے ملاقات
سترہویں عالمی اردو کانفرنس میں شرکت کے لیے کین ساکو مامیا کراچی تشریف لائے، تو راقم نے بطور میزبان کانفرنس میں ان کے ساتھ ایک سیشن میں گفتگو کی جو بعنوان "جاپان، اردو کی زرخیز سرزمین” منعقد کیا گیا تھا۔ اس سیشن میں جاپان میں اردو اور پاکستان میں جاپانیوں کی حسین یادوں کا احاطہ کیا گیا۔ بعد میں کین ساکو مامیا نے اے آر وائی کی ویب سائٹ کے لیے اردو زبان میں خصوصی انٹرویو ریکارڈ کروایا۔ اس خصوصی انٹرویو کو آپ یہاں سن سکتے ہیں۔
کین ساکو مامیا 1984ء میں اسکول کے طالبِ علم تھے جب انہوں نے پاکستان کی شاہراہ ریشم پر بنی ہوئی ایک دستاویزی فلم جاپانی زبان میں دیکھی اور اس ملک نے ان کی توجہ حاصل کی۔ بعد میں کین ساکو مامیا نے جامعہ کی سطح پر تعلیم حاصل کرنے کے دوران جنوبی ایشیا کو نقشے پر غور سے دیکھا اور پاکستان کے بارے میں مزید جاننے کا فیصلہ کیا۔یہ 1988 کی بات ہے، جب وہ ٹوکیو یونیورسٹی آف فارن اسٹڈیز میں ایم اے کے طالبِ علم تھے۔
ایک موقع پر کین ساکو مامیا پاکستان آئے اور یہاں کے سب سے بڑے شہر کراچی، پھر لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور بھی گئے۔ آخر میں ان کا انتخاب حیدر آباد ٹھہرا، اور انہوں نے سندھ یونیورسٹی، جام شورو سے ایم فل کیا۔ اس سلسلہ میں پاکستان میں اپنے دو سالہ قیام کے دوران وہ کراچی اور سندھ کے دیگر شہروں میں بھی آتے جاتے رہے اور پاکستانی ثقافت سے بھی واقف ہوئے۔ پاکستان کا شہر اسلام آباد ان کو اب سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے چار سال وہاں گزارے ہیں۔ وہ اسلام آباد میں قائم جاپانی سفارت خانے میں کام کرتے تھے۔
اردو زبان کے عاشق اور جاپان میں اردو کے استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے کین ساکو مامیا کا خیال ہے کہ جاپانیوں کو اردو زبان بولنے میں کوئی دقت نہیں ہے، البتہ اردو کا رسمُ الخط اور حروفِ تہجّی محنت سے سیکھا جاتا ہے۔ بالکل یہی صورتحال ان پاکستانیوں کو درپیش ہوگی، جو جاپانی زبان سیکھنا چاہتے ہیں۔ لسانیات کے اصولوں کے اعتبار سے دونوں زبانیں ایک دوسرے سے صوتی اعتبار سے کافی قریب ہیں۔ کین ساکو مامیا یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے شعبۂ اردو میں تدریسی اور روایتی تعلیم کے طور طریقوں کے ساتھ تخلیقی اور فنی پہلوؤں سے بھی طالبِ علموں کو اردو سے روشناس کروایا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اردو زبان میں اسٹیج ڈرامے بھی پیش کرتے ہیں، جن میں اردو زبان سیکھنے والے جاپانی طلبا حصہ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی فلموں کی نمائش کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم جاپان میں اپنے طلبا کو شعیب منصور کی فلم "خدا کے لیے” سمیت کئی پاکستانی اور ہندوستانی فلمیں بھی دکھا چکے ہیں۔ ہندوستانی فلموں میں نندیتا داس کی فلم "منٹو” بھی شامل ہے۔

کین ساکو مامیا پاکستان میں گزشتہ انتخابات کے موقع پر بطور آبزور تشریف لائے۔وہ پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں اور یہاں کے تمام بڑے شہروں سے بخوبی واقف ہیں۔ سندھ کی ثقافت میں ان کی دل چسپی اس قدر بڑھی کہ سندھی زبان بھی سیکھی۔ اردو زبان کے قواعد اور لسانی اصولوں میں گہری دل چسپی رکھتے ہیں۔ اردو ادب اور خاص طور پر شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے طلبا کو بھی پڑھاتے ہیں۔
اگر کبھی آپ ٹوکیو جائیں اور کین ساکو مامیا سے ملاقات کرنے کے لیے یونیورسٹی پہنچیں تو وہاں ان کا کمرہ آپ کو ایک چھوٹا سا پاکستان محسوس ہوگا۔ اس کمرے میں آپ کو اردو، سندھی اور پاکستان کی دیگر زبانوں کے نقش ملیں گے، کتابیں اور دیگر ثقافتی علامتیں سجی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اپنے حالیہ دورۂ کراچی میں مرز اسد اللہ خاں غالب کا یہ شعر کین ساکو مامیا نے اکثر مواقع پر پڑھا اور میں اس ملاقات کا یہ احوال اسی شعر پر ختم کرنا چاہوں گا:
مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے
جوشِ قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے
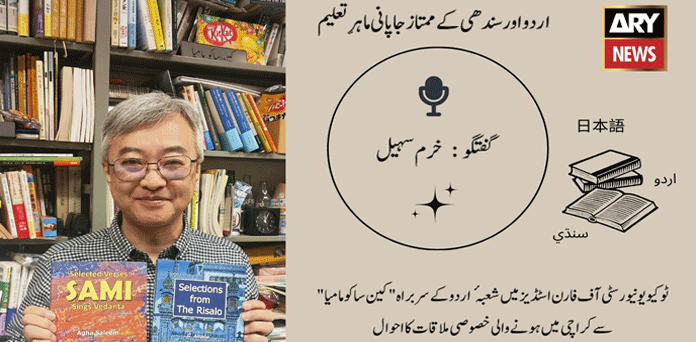




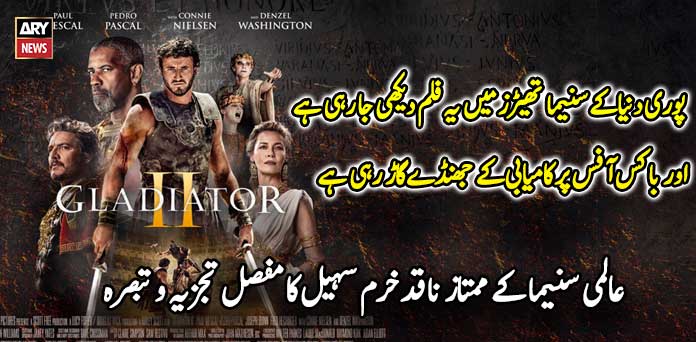






 یہ تحریر نہ تو آذربائیجان کا سفرنامہ ہے اور نہ ہی باکو شہر کے بارے میں کوئی فیچر رپورٹ۔ میں باکو کے دو بڑے قدیم ترین اور تاریخی اہمیت کے حامل مقامات کی مختصر معلومات کے ساتھ وہ مسرت بھری اور کچھ حیرت انگیز یادیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، جو میرے نزدیک اہم ہیں۔ میں نے باکو کو جدید طرز کی عمارتوں اور بہترین انفرااسٹرکچر کے ساتھ قدیم و جدید روایت اور ثقافت کا ایسا شہر پایا جو بلاشبہ قابلِ ذکر ہے۔ اس سے بڑھ کر میں نے یہاں کے ماحول اور طرزِ تعمیر میں بڑی کشش محسوس کی اور پھر پاکستان کے بڑے شہر کراچی کی حالتِ زار پر کڑھنے لگی۔
یہ تحریر نہ تو آذربائیجان کا سفرنامہ ہے اور نہ ہی باکو شہر کے بارے میں کوئی فیچر رپورٹ۔ میں باکو کے دو بڑے قدیم ترین اور تاریخی اہمیت کے حامل مقامات کی مختصر معلومات کے ساتھ وہ مسرت بھری اور کچھ حیرت انگیز یادیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، جو میرے نزدیک اہم ہیں۔ میں نے باکو کو جدید طرز کی عمارتوں اور بہترین انفرااسٹرکچر کے ساتھ قدیم و جدید روایت اور ثقافت کا ایسا شہر پایا جو بلاشبہ قابلِ ذکر ہے۔ اس سے بڑھ کر میں نے یہاں کے ماحول اور طرزِ تعمیر میں بڑی کشش محسوس کی اور پھر پاکستان کے بڑے شہر کراچی کی حالتِ زار پر کڑھنے لگی۔
 کہتے ہیں کہ چھٹی صدی قبل مسیح میں آبادی نے اپنی فکر اور خیالات کے مطابق ایک مذہب اپنایا اور وہ مختلف ادوار میں اور سلطنتوں کے عروج و زوال کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہا اور آذربائیجان میں کئی قدیم قربان گاہیں، مندر اور آتش کدے بنائے گئے جن کے آثار آج بہت کم دیکھے جاسکتے ہیں۔ بہرحال، یہ طے ہے کہ اس سرزمین کے آتش کدوں اور ان کے بھڑکتے رہنے کی ایک وجہ زمین کی سطح پر تیل کا جمع ہوجانا ہے جن میں سورج یا کسی دوسری وجہ سے آگ بھڑک اٹھتی اور پھر شعلے بھڑکتے رہتے۔ زرتشتوں نے ان پر آتش کدے تعمیر کیے جو ان کے لیے خدائی صفات سے معمور مقام اور ایک روحانی مرکز ہیں۔ ہم نے دو بڑے آتش کدوں ینار دگ اور مشہور ترین آتش گاہ سورا خانی کی سیر کی۔ آتش گاہ دارالحکومت باکو سے تقریباً تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور ایک ایسی کھلی وسیع دالان والی عمارت ہے جس میں پتھروں کی دیوار بنائی گئی ہے اور ان کے ساتھ قدیم دور میں حجرے بھی تعمیر کیے گئے تھے جہاں یقیناً عبادت کرنے والے اور زیارت کے لیے آنے والے قیام کرتے ہوں گے۔ اسے عام طور پر آتش گاہ کہتے ہیں۔ ہم باکو سے نکلے تو کچھ کلومیٹر سفر کرنے کو بعد سور خانی کے علاقے میں تھے۔ وہاں ایک معبد یا مندر موجود تھا جسے مقامی لوگ صرف آتش گاہ کہتے ہیں۔ یہ یونیسکو کے ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ اس کی عمارت کے اطراف جو کمرے ہیں، ان میں عبادت اور رہائش کے لیے مخصوص کمروں کے علاوہ اناج اور دوسری اشیاء ذخیرہ و محفوظ کرنے والے کمرے بھی بنائے گئے تھے۔ میرے لیے باکو کے یہ دو آتش کدے بہت پراسرار، اور دل چسپی کے حامل رہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر میں نے شہر کے ماحول، ثقافت اور انفراسٹرکچر کو بھی بہت توجہ اور دل چسپی سے دیکھا جس کا تذکرہ میں یہاں کررہی ہوں۔
کہتے ہیں کہ چھٹی صدی قبل مسیح میں آبادی نے اپنی فکر اور خیالات کے مطابق ایک مذہب اپنایا اور وہ مختلف ادوار میں اور سلطنتوں کے عروج و زوال کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہا اور آذربائیجان میں کئی قدیم قربان گاہیں، مندر اور آتش کدے بنائے گئے جن کے آثار آج بہت کم دیکھے جاسکتے ہیں۔ بہرحال، یہ طے ہے کہ اس سرزمین کے آتش کدوں اور ان کے بھڑکتے رہنے کی ایک وجہ زمین کی سطح پر تیل کا جمع ہوجانا ہے جن میں سورج یا کسی دوسری وجہ سے آگ بھڑک اٹھتی اور پھر شعلے بھڑکتے رہتے۔ زرتشتوں نے ان پر آتش کدے تعمیر کیے جو ان کے لیے خدائی صفات سے معمور مقام اور ایک روحانی مرکز ہیں۔ ہم نے دو بڑے آتش کدوں ینار دگ اور مشہور ترین آتش گاہ سورا خانی کی سیر کی۔ آتش گاہ دارالحکومت باکو سے تقریباً تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور ایک ایسی کھلی وسیع دالان والی عمارت ہے جس میں پتھروں کی دیوار بنائی گئی ہے اور ان کے ساتھ قدیم دور میں حجرے بھی تعمیر کیے گئے تھے جہاں یقیناً عبادت کرنے والے اور زیارت کے لیے آنے والے قیام کرتے ہوں گے۔ اسے عام طور پر آتش گاہ کہتے ہیں۔ ہم باکو سے نکلے تو کچھ کلومیٹر سفر کرنے کو بعد سور خانی کے علاقے میں تھے۔ وہاں ایک معبد یا مندر موجود تھا جسے مقامی لوگ صرف آتش گاہ کہتے ہیں۔ یہ یونیسکو کے ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ اس کی عمارت کے اطراف جو کمرے ہیں، ان میں عبادت اور رہائش کے لیے مخصوص کمروں کے علاوہ اناج اور دوسری اشیاء ذخیرہ و محفوظ کرنے والے کمرے بھی بنائے گئے تھے۔ میرے لیے باکو کے یہ دو آتش کدے بہت پراسرار، اور دل چسپی کے حامل رہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر میں نے شہر کے ماحول، ثقافت اور انفراسٹرکچر کو بھی بہت توجہ اور دل چسپی سے دیکھا جس کا تذکرہ میں یہاں کررہی ہوں۔
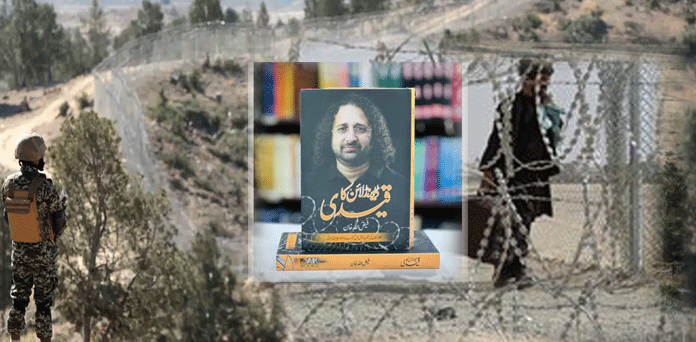
 اس کتاب میں ایسی کئی چیزیں ہیں جن پر کافی تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن میری یہ تحریر ایک تعارفی تحریر ہے جس میں میں نے اس کے متن کو تنقیدی نگاہ سے بھی دیکھا ہے۔ اس کتاب کا عنوان برطانوی سامراج کو قبول نہ کرنے کا ایک علامتی اظہار ہے۔ برطانیہ نے کالونی میں اپنے مفادات کی خاطر یہ لائن کھینچ کر قبائل کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ آج بھی، جب کہ یہ لائن نو آبادیاتی یادگار ہے، دونوں طرف کے قبائل اسے تسلیم کرنے سے اصولی طور پر انکاری ہیں۔ لیکن کتاب کا یہ عنوان اپنے ساتھ اتنے واضح علامتی معنی لیے ہونے کے باوجود اس کے ناشر زاہد علی خان نے ’’عرض ناشر‘‘ میں افغانوں سے متعلق حقیقت سے عاری اور حماقت سے بھری ایسی باتیں لکھی ہیں، کہ گمان گزرتا ہے کہ وہ زمینی حقائق کے ڈائناسارز کو جان بوجھ کر نظر انداز کر کے، من پسند اور مخصوص سوچ کی تشکیل کردہ ایسے معنی کے ہاتھوں اغوا ہو رہے ہیں، جو ہے تو مچھر اتنا لیکن پیش کیا جاتا ہے نمرود کے قاتل کے طور پر!
اس کتاب میں ایسی کئی چیزیں ہیں جن پر کافی تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن میری یہ تحریر ایک تعارفی تحریر ہے جس میں میں نے اس کے متن کو تنقیدی نگاہ سے بھی دیکھا ہے۔ اس کتاب کا عنوان برطانوی سامراج کو قبول نہ کرنے کا ایک علامتی اظہار ہے۔ برطانیہ نے کالونی میں اپنے مفادات کی خاطر یہ لائن کھینچ کر قبائل کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ آج بھی، جب کہ یہ لائن نو آبادیاتی یادگار ہے، دونوں طرف کے قبائل اسے تسلیم کرنے سے اصولی طور پر انکاری ہیں۔ لیکن کتاب کا یہ عنوان اپنے ساتھ اتنے واضح علامتی معنی لیے ہونے کے باوجود اس کے ناشر زاہد علی خان نے ’’عرض ناشر‘‘ میں افغانوں سے متعلق حقیقت سے عاری اور حماقت سے بھری ایسی باتیں لکھی ہیں، کہ گمان گزرتا ہے کہ وہ زمینی حقائق کے ڈائناسارز کو جان بوجھ کر نظر انداز کر کے، من پسند اور مخصوص سوچ کی تشکیل کردہ ایسے معنی کے ہاتھوں اغوا ہو رہے ہیں، جو ہے تو مچھر اتنا لیکن پیش کیا جاتا ہے نمرود کے قاتل کے طور پر! یہ کتاب اگرچہ ایک اچھی دستاویز کی طرح ہے تاہم افغان سماج کا تجزیہ ایک زیادہ غیر جانب دار رویے کا طالب ہے۔ اوپر صفحہ 185 کا جو اقتباس پیش کیا گیا ہے، اس کے بعد افغان میڈیا میں پاکستان کی مخالفت کا خصوصی ذکر موجود ہے لیکن جس سماجی تجزیے کی ضرورت تھی وہ موجود نہیں۔ مثال کے طورر پر اس اقتباس سے قبل سرمایہ کاری (بالخصوص انفراسٹرکچر میں) کے حوالے سے بھارت افغانستان دو طرفہ تعلقات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک اچھا سماجی تجزیہ کار یہ بنیادی سوال اٹھائے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جغرافیائی، سماجی اور ثقافتی قربت اور اشتراک کے باوجود اس سرمایہ کاری کی طرف پاکستان نہیں گیا؟ افغانستان صرف ڈیورنڈ لائن ہی پر نہیں، ملک کے اندر مداخلت پر بھی شاکی رہا ہے۔ طویل عرصے تک اس مداخلت کے باوجود پاکستان کا یہ کردار افغانستان کے اندر تعمیر و ترقی کی طرف کیوں نہیں گیا؟ اس تجزیے کی عدم موجودی کے باعث ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے افغان میڈیا کا یہ پاکستان مخالف رویہ کسی پراسرار قوت کے طابع ہو۔ حالاں کہ یہ سامنے کی بات ہے کہ اگر چودہ اگست کو یہ میڈیا پاکستان کے حوالے سے کوئی خبر نہیں چلاتا اور پندرہ کو ہندوستان کی آزادی پر خصوصی نشریات ترتیب دیتا ہے تو اسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ وہ افغانستان کا کاروباری اور سرمایہ کاری پارٹنر ہے، سوال یہ ہے کہ ہم نے وہاں کس چیز میں سرمایہ کاری کی ہے؟
یہ کتاب اگرچہ ایک اچھی دستاویز کی طرح ہے تاہم افغان سماج کا تجزیہ ایک زیادہ غیر جانب دار رویے کا طالب ہے۔ اوپر صفحہ 185 کا جو اقتباس پیش کیا گیا ہے، اس کے بعد افغان میڈیا میں پاکستان کی مخالفت کا خصوصی ذکر موجود ہے لیکن جس سماجی تجزیے کی ضرورت تھی وہ موجود نہیں۔ مثال کے طورر پر اس اقتباس سے قبل سرمایہ کاری (بالخصوص انفراسٹرکچر میں) کے حوالے سے بھارت افغانستان دو طرفہ تعلقات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک اچھا سماجی تجزیہ کار یہ بنیادی سوال اٹھائے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جغرافیائی، سماجی اور ثقافتی قربت اور اشتراک کے باوجود اس سرمایہ کاری کی طرف پاکستان نہیں گیا؟ افغانستان صرف ڈیورنڈ لائن ہی پر نہیں، ملک کے اندر مداخلت پر بھی شاکی رہا ہے۔ طویل عرصے تک اس مداخلت کے باوجود پاکستان کا یہ کردار افغانستان کے اندر تعمیر و ترقی کی طرف کیوں نہیں گیا؟ اس تجزیے کی عدم موجودی کے باعث ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے افغان میڈیا کا یہ پاکستان مخالف رویہ کسی پراسرار قوت کے طابع ہو۔ حالاں کہ یہ سامنے کی بات ہے کہ اگر چودہ اگست کو یہ میڈیا پاکستان کے حوالے سے کوئی خبر نہیں چلاتا اور پندرہ کو ہندوستان کی آزادی پر خصوصی نشریات ترتیب دیتا ہے تو اسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ وہ افغانستان کا کاروباری اور سرمایہ کاری پارٹنر ہے، سوال یہ ہے کہ ہم نے وہاں کس چیز میں سرمایہ کاری کی ہے؟