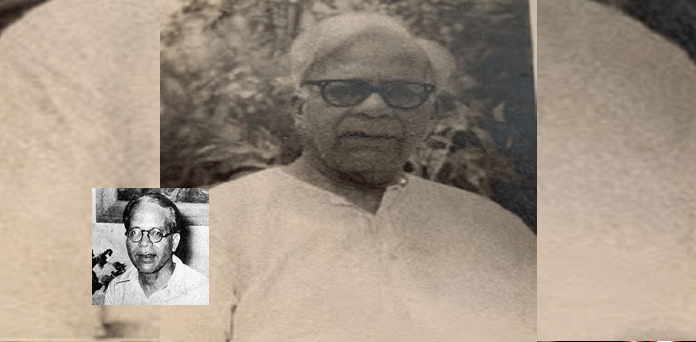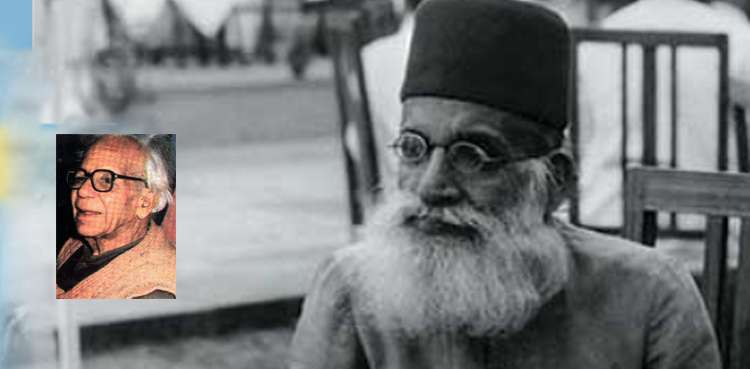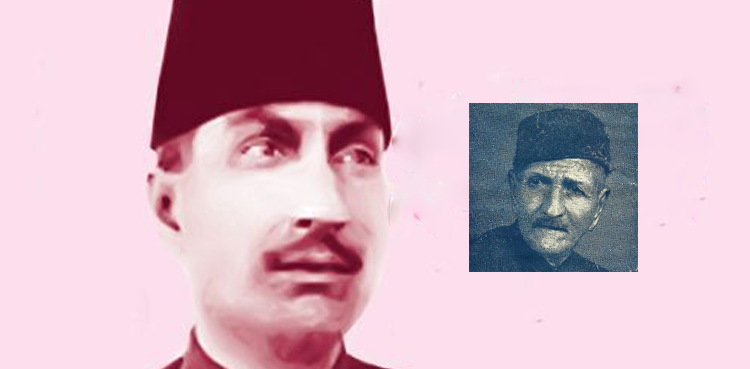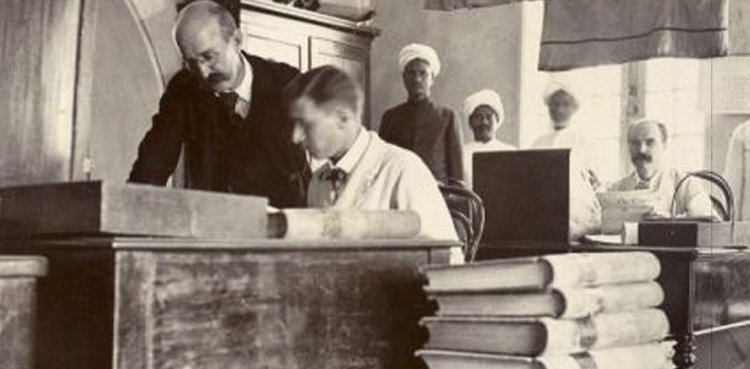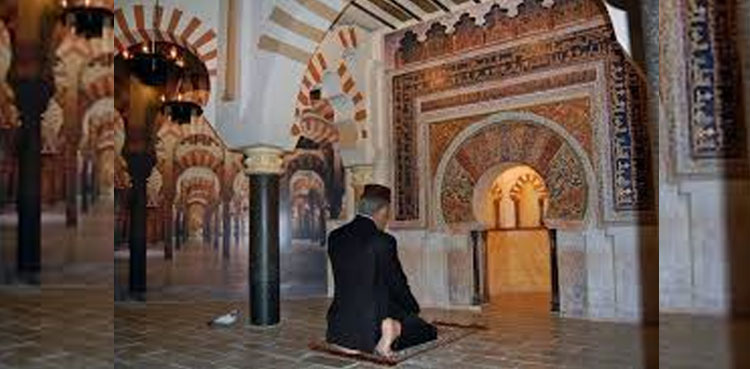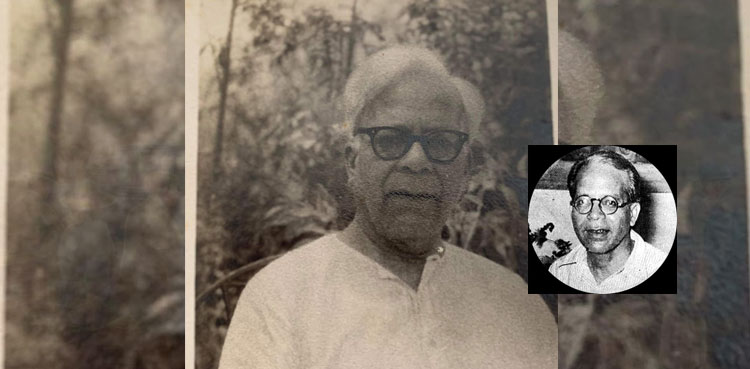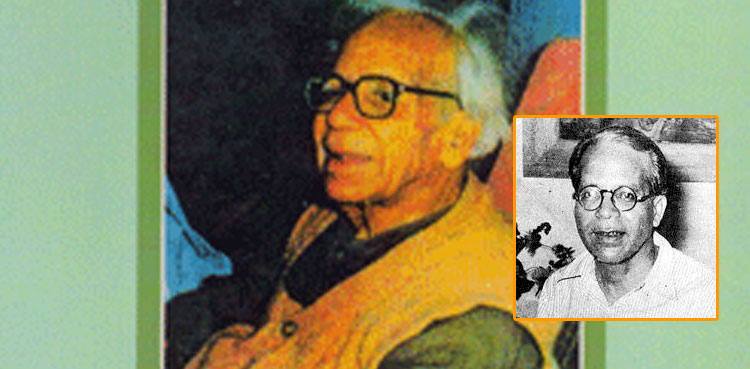آل احمد سرور اردو کے سر بر آوردہ نقاد تھے جن کے تنقیدی مضامین نے ایک نسل کے ادبی مذاق کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا اور آج بھی ان کی تحریریں اردو ادب کا سرمایہ تصور کی جاتی ہیں۔
9 فروری 2002ء پروفیسر آل احمد سرور اس دنیائے فانی سے رخصت ہوگئے تھے۔ آج ان کی برسی ہے۔ آل احمد سرور کے مطالعہ کی وسعت، فکر کی گہرائی، تخیل کی بلندی، تجزیاتی سوچ بوجھ اور طرزِ تحریر نے انھیں اردو ادب میں ممتاز کیا۔ ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کی ترویج و توسیع میں بھی ان کا حصہ رہا اور جب جدیدیت اپنا رنگ جمانے لگی تو سرور صاحب اس کے ہراول دستے میں رہے۔ آلِ احمد سرور نے ترقّی پسند تحریک، حلقۂ اربابِ ذوق اور جدیدیت تینوں ادوارِ ادب کو دیکھا اور ان کا اثر قبول کیا، لیکن کسی ایک تحریک سے بندھے نہیں۔ سرور صاحب کی علمی و ادبی خدمات کا دائرہ از حد وسیع ہے۔ انہوں نے اردو زبان میں تنقید کی نئی شمعیں روشن کیں۔ نقاد و مصنّف، شاعر اور ماہرِ اقبالیات ہی نہیں بحیثیت ادبی صحافی بھی انھوں نے خوب کام کیا۔ وہ اردو ادب، ہماری زبان اور کئی دوسرے جرائد سے وابستہ رہے۔
سرور صاحب 9 ستمبر 1911ء کو شمالی ہند کی ریاست اتر پردیش کے علاقہ پیلی بھیت کے ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے۔ ایک انٹرویو میں آل احمد سرور نے اپنے وطن کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا: "شاید یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ میرا آبائی وطن بدایوں ہے۔ بدایوں ایک تاریخی شہر ہے اور وہاں کے کھنڈر اور ٹوٹی پھوٹی حویلیاں اب بھی اُس کی گزشتہ عظمت کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ بستی قدیم زمانے سے علماء و فضلا، شعرا اور صوفیائے کرام کا مرکز رہی ہے۔ میرے بچپن کا زمانہ وہیں گزرا۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو گھر گھر شعر و شاعری کا چرچا تھا۔ آئے دن مشاعرے ہوتے جس میں باہر سے مشہور شعرا شریک ہونے کے لیے آتے اور بدایوں کے چھوٹے بڑے سبھی اپنا کلام سناتے۔”
آل احمد سرور کا بچپن اور نوعمری کا دور پیلی بھیت کے علاوہ بجنور، سیتا پور، گونڈہ اور غازی پور میں گزرا۔ کیونکہ اُن کے والد کرم احمد کو ملازمت کے سلسلے میں مختلف علاقوں میں سکونت اختیار کرنی پڑی تھی۔ ابتدائی تعلیم بدایوں میں ہوئی اور بعد میں اسکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوتی رہی۔ غازی پور کے کوئن وکٹوریہ ہائی اسکول سے آل احمد سرور نے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔
سرور نے اپنی خود نوشت سوانح "خواب باقی ہیں” میں اپنے بچپن کے واقعات بیان کیے ہیں۔ جس سے اُن کے عادات و اطوار اور علمی استعداد و مشاغل کا پتہ چلتا ہے۔ ان کا حافظہ بہت تیز تھا۔ پڑھائی میں آگے رہتے تھے۔ عام بچوں کی طرح ابتداً کھیل کود سے دل چسپی رہی لیکن آہستہ آہستہ مطالعہ کی طرف زیادہ مائل ہوگئے۔ یہ وہ دور تھا جس میں ہر طرف شعر و ادب کا چرچا تھا۔ تعلیم یافتہ لوگوں کے گھروں میں مطالعہ اور بیت بازی کا رواج تھا اور اسی کا شوق سرور صاحب میں بھی پیدا ہوگیا۔ وہ کتب بینی کے عادی ہوگئے۔ ان کے والد کی انگریزی اور اُردو کی کتابیں مطالعہ کا ذوق بڑھاتی رہیں۔ بعد میں وہ اپنے چچا کے گھر آگرہ منتقل ہو گئے۔ سینٹ جانسن کالج میں ایف۔ ایس۔ سی (انٹرمیڈیٹ سائنس) میں داخلہ لیا۔ آگرہ میں لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کردیا اور کالج میگزین میں اپنی تخلیقات شائع کروانے لگے جس نے انھیں ساتھی طالبِ علموں میں ممتاز کیا اور کالج میں ادبی انجمن کے ذمہ دار بنا دیے گئے۔ ایک موقع پر انجمن کے سالانہ مشاعرے میں سرور صاحب کی ملاقات فانی بدایونی، یاس یگانہ چنگیزی، میکش اکبر آبادی سیماب اکبر آبادی، مخمورؔ اکبر آبادی اور مانیؔ جائسی جیسے با کمال شعرا سے ہوئی۔ اسی دوران سینٹ جانسن کالج کے زیر اہتمام انعامی مباحثہ ہوا جس میں سرور صاحب نے حصہ لے کر دوسرا انعام اپنے نام کیا۔ یوں حوصلہ افزائی ہوئی اور پھر وہ بی- ایس۔ سی کا امتحان درجہ دوم میں پاس کرکے انگریزی میں ایم۔ اے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلے گئے۔ دراصل یہاں ان کے والد کا بھی تبادلہ چکا تھا۔ یہاں سرور نے علمی و ادبی مقابلوں اور مذاکروں سبھی میں بڑھ چڑھ کر حصّہ لیا۔ سرور نے جس وقت علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا اُس وقت سر راس مسعود یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ اور یونیورسٹی میں اُن کے زیر نگرانی زائد از نصابی سرگرمیاں بھی عروج پر تھیں۔ سرور کے ادبی ذوق کو دیکھتے ہوئے انھیں علی گڑھ میگزین (اُردو ) کا ایڈیٹر مقرر کردیا گیا۔ انگریزی میں بڑی دستگاہ تھی اور یونیورسٹی میں ہونے والے مباحثوں میں وہ انعامات حاصل کرتے رہے۔ اس بارے میں سرور لکھتے ہیں: "ہر سال ایک انگریزی میں اور ایک اردو میں آل انڈیا ڈبیٹ ہوا کرتا تھا۔ 1933ء کے آخر میں جب انعامی مقابلے ہوئے تو سب سے زیادہ مجھے اور میرے بعد خواجہ احمد عباس کو انعام ملے۔”
آل احمد سرور نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم۔ اے انگریزی کرنے کے بعد شعبۂ انگریزی میں بہ حیثیت لکچرر اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔ بعد میں ایم۔ اے اُردو کیا۔ اور پھر یونیورسٹی کے شعبۂ اردو میں لکچرر ہوئے۔ اسی زمانے میں ریڈیو پر تقاریر کے لیے بلایا جانے لگا۔ سرور کی ریڈیو پر پڑھی گئی تقاریر کافی مقبول ہوئیں۔ بعد میں یہ زیور طباعت سے آراستہ کی گئیں۔ شعبۂ اُردو سے سبکدوشی کے بعد آل احمد سرور انجمن ترقی اُردو کی سرگرمیوں میں مشغول رہے۔ پھر انہیں شملہ کے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ایڈوانسڈ اسٹڈیز میں وزیٹنگ فیلو مقرر کیا گیا۔ وہ بھارت کے کئی شہروں میں آتے جاتے رہے اور اس دوران ان کے تنقیدی مضامین، شاعری اور مقالہ جات اردو دنیا میں ان کی شناخت اور پہچان بنتے رہے۔
پروفیسر آل احمد سرور کے مضامین کی کتابی شکل اور ان کی دوسری تصانیف میں پہچان اور پرکھ، خواب باقی ہیں (خود نوشت سوانح)، خواب اور خلش (شعری مجموعہ)، خطبے کچھ، کچھ مقالے، دانشور اقبال، ( مجموعہ تنقیدات، اور افکار کے دیے، نئے اور پرانے نظریے، تنقید کیا ہے، ادب اور نظریہ، مسرت سے بصیرت تک، اقبال کا نظریہ اور شاعری، ذوقِ جنوں (شاعری) شامل ہیں۔
بھارت میں اردو زبان و ادب کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والے آل احمد سرور کو ان کی خدمات کے اعتراف میں کئی جامعات نے سند و اعزاز سے نوازا جب کہ اتر پردیش اُردو اکیڈمی نے چار مرتبہ اور ساہتیہ اکیڈمی نے ایک انعام ان کو دیا۔ 1992 میں حکومتِ ہند نے آل احمد سرور کو پدم بھوشن کا خطاب دیا تھا۔