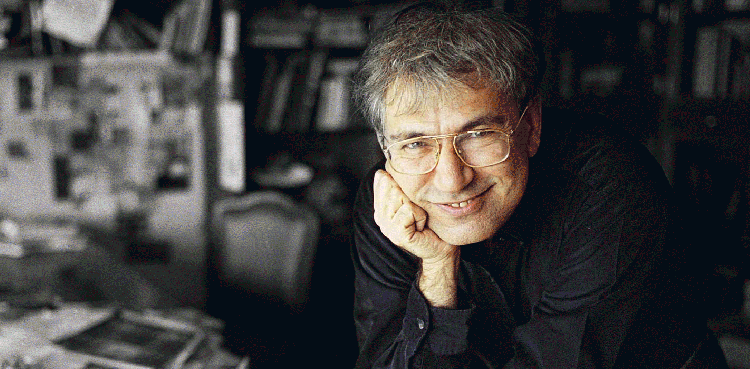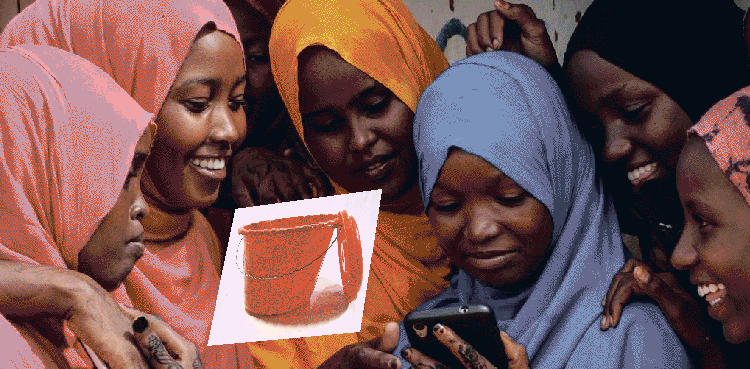فیدل کاسترو اور مارکیز، دونوں کا شمار مشاہیر میں کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک نام وَر انقلابی اور مدبّر سیاست داں تھا اور دوسرا شہرۂ آفاق ناولوں کا خالق۔ آج یہ دونوں ہی اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کا نظریہ اور ان کی تخلیق آج بھی انھیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔
لاطینی امریکہ کی ان معتبر شخصیات نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو اپنے افکار و نظریات سے متأثر کیا اور اپنی جرأت و صداقت کے سبب ان کا بڑا احترام کیا جاتا ہے۔
کیوبا کے انقلابی راہ نما اور صدر فیدل کاسترو کی بات کی جائے تو وہ ایک زبردست مقرر بھی تھے۔ وہ فنِ خطابت ہی میں ماہر نہیں تھے بلکہ کتب بینی کا شوق رکھنے والے اور اعلیٰ پائے کے قلم کار تھے۔ کاسترو ایک کالم نویس بھی تھے اور کیوبا کے اخبارات میں باقاعدگی سے ان کی تحریریں شایع ہوتی تھیں۔ سیاست کے ساتھ ساتھ کاسترو کو ادب سے گہری دل چسپی تھی۔ وہ انگریزی اور ہسپانوی ادب کے قاری ہی نہیں بلکہ نقّاد بھی تھے۔ کئی ادیبوں سے ان کی دوستی تھی۔ لاطینی امریکہ کے منفرد اسلوب کے حامل ادیب مارکیز سے بھی کاسترو کا تعلق رہا۔ مارکیز کولمبیا کے ناول نگار اور صحافی تھے جن کی کہانیوں اور مضامین کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ گبریئل گارشیا مارکیز کا مشہور ناول ”تنہائی کے سو سال‘‘ کاسترو کو بہت پسند تھا۔ مارکیز بھی کاسترو کو ایک زبردست قاری اور بہترین نقّاد مانتے تھے اور مشہور ہے کہ اس ادیب نے اپنے کئی مسودے تنقیدی جائزہ لینے کی غرض سے کاسترو کے سامنے رکھے تھے۔
مارکیز نے اپنے سوانحی انٹرویوز پر مبنی کتاب میں کاسترو کی تنقیدی بصیرت کا تذکرہ کیا ہے جس سے ایک دل چسپ پارہ ہم یہاں نقل کر رہے ہیں۔ اجمل کمال نے مارکیز کی کتاب کا اردو ترجمہ "امرود کی مہک” کے نام سے کیا تھا۔ اسی ترجمہ سے یہ انتخاب پیشِ خدمت ہے جو اپنے وقت کی ایک غیر معمولی ذہین اور مدبّر شخصیت فیدل کاسترو کے علمی و ادبی ذوق کی گواہی بھی ہے۔
”فیدل کاسترو” سے میری قریبی اور دِلی دوستی کا آغاز ادب کے حوالے سے ہوا۔ 1960ء کی دہائی میں ”پرینسا لاطینا” میں ملازمت کے دنوں میں، میں اسے سرسری طور پر جاننے لگا تھا، لیکن مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ ہمارے درمیان کچھ زیادہ چیزیں مشترک ہیں۔
بعد میں جب میں ایک مشہور ادیب اور وہ دنیا کا معروف ترین سیاست داں بن چکا تھا، ہماری کئی بار ملاقات ہوئی، مگر تب بھی، باہمی احترام اور خیر سگالی کے باوجود، میں نے محسوس نہیں کیا کہ اس تعلق میں سیاسی ہم آہنگی سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہوسکتی ہے۔
چھے برس پہلے ایک روز صبح منہ اندھیرے اس نے مجھ سے اجازت چاہی، کیوں کہ اسے گھر جاکر بہت سا مطالعہ کرنا تھا۔ اس نے کہا کہ اگرچہ یہ کام اسے لازماً کرنا پڑتا ہے لیکن بیزار کن اور تھکا دینے والا کام لگتا ہے۔ میں نے مشورہ دیا کہ اس لازمی مطالعے کی تھکن دور کرنے کے لیے وہ کوئی ایسی چیز پڑھا کرے جو ذرا ہلکی پھلکی ہو، مگر اچھا ادب ہو۔ میں نے مثال کے طور پر چند کتابوں کے نام لیے، اور یہ جان کر حیران ہوا کہ نہ صرف اس نے یہ تمام کتابیں پڑھ رکھی تھیں بلکہ اس پر اچھی نگاہ تھی۔
اُس رات مجھ پر اِس بات کا انکشاف ہوا جس سے چند ہی لوگ واقف ہیں کہ فیدل کاسترو بے حد پُرجوش پڑھنے والا ہے کہ اسے ہر زمانے کے اچھے ادب سے محبت ہے، اور یہ کہ وہ اس کا نہایت سنجیدہ ذوق رکھتا ہے۔ دشوار ترین حالات میں بھی، فرصت کے لمحات میں پڑھنے کے لیے اس کے پاس ایک نہ ایک عمدہ کتاب ضرور رہتی ہے۔
اس شب رخصت ہوتے ہوئے میں نے اسے پڑھنے کے لیے ایک کتاب دی۔ اگلے روز 12 بجے میں اس سے دوبارہ ملا تو وہ اسے پڑھ چکا تھا۔ وہ اس قدر محتاط اور باریک بیں قاری ہے کہ وہ نہایت غیر متوقع مقامات پر تضادات اور واقعاتی غلطیوں کی نشان دہی کر دیتا ہے۔
میری کتاب ”ایک غرقاب شدہ جہاز کے ملاح کی داستان” پڑھنے کے بعد وہ صرف یہ بتانے کے لیے میرے ہوٹل آیا کہ میں نے کشتی کی رفتار کا حساب لگانے میں غلطی کی ہے، اور اس کے پہنچنے کا وقت ہرگز وہ نہیں ہوسکتا جو میں نے بیان کیا ہے۔ اس کی بات درست تھی۔ اس لیے” ایک پیش گفتہ موت کی روداد” کو شائع کرانے سے پہلے میں مسودہ اس کے پاس لے گیا، اور اس نے شکاری رائفل کی خصوصیات کے بارے میں ایک غلطی کی نشان دہی کی۔
لگتا ہے اسے ادب کی دنیا سے محبت ہے، یہاں اس کا جی لگتا ہے، اور اسے اپنی بے شمار تحریر شدہ تقریروں کے ادبی اسلوب پر محنت کرنے میں لطف آتا ہے۔ ایک موقعے پر اس نے حسرت زدہ انداز میں، مجھے بتایا: ” اپنے اگلے جنم میں میں ایک ادیب بننا چاہتا ہوں۔