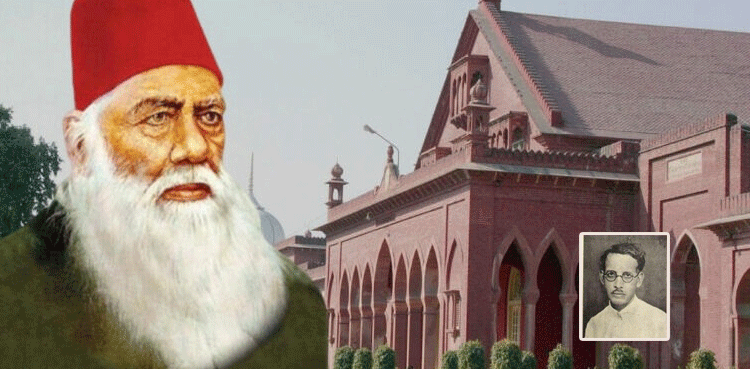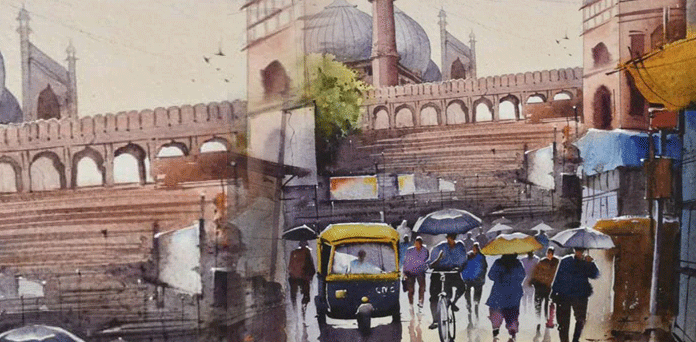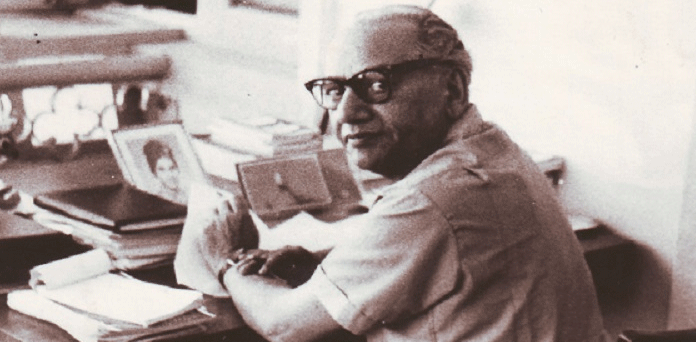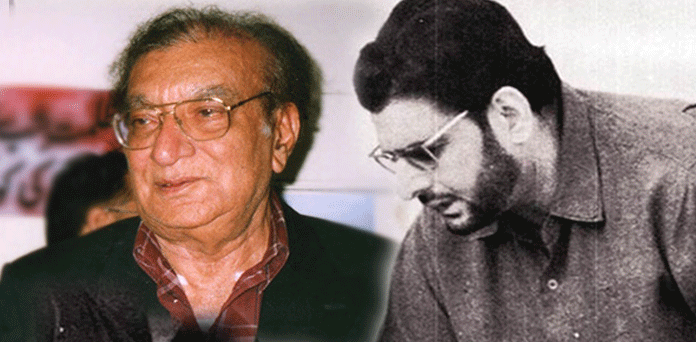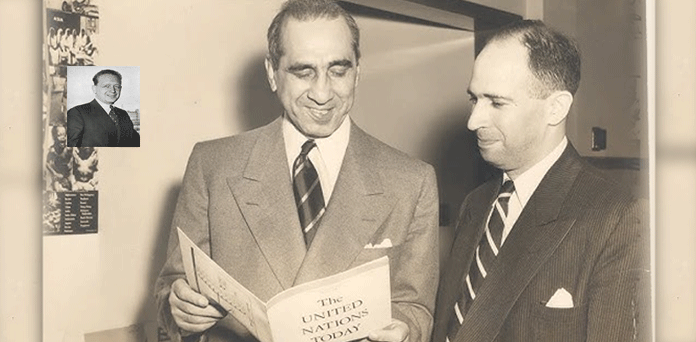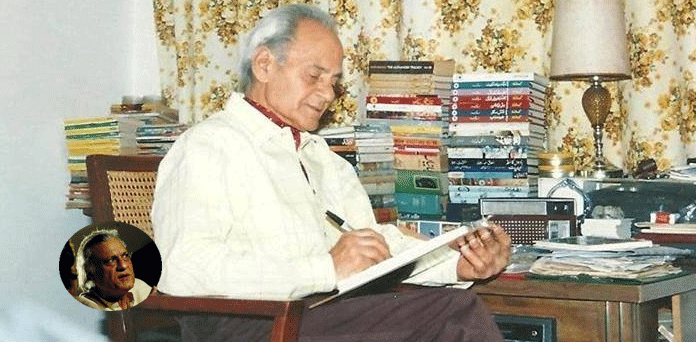پکالیں پیس کر دو روٹیاں تھوڑی سی جو لانا
ہماری کیا ہے اے بھائی نہ مسٹر ہیں نہ مولانا
مجھ مسکین بے نوا کے حسب حال تو مولانا اکبر حسین کا وہ شعر ہے جو اس تحریر کا زیب عنوان ہے اور یہ بر سبیل انکسار نفس نہیں، بلکہ از راہ حقیقت۔ لیکن وائے بر حال ان حضرات کے جن کے ناموں کے پہلے دکن ریویو میں مولوی کا لفظ لکھا دیکھ کر ہمارے دیرینہ کرم فرما مولانا وبالفضل اولیٰنا مولوی ثناء اللہ صاحب ایڈیٹر اہل حدیث کو اس قدر طیش آیا کہ آپ نے ایک طویل مضمون ان کی شان میں لکھنے کی زحمت گوارا فرمائی۔
مولانا نے اپنی شان ثقاہت کو بالائے طاق کر بہ تقلید روش عوام کالانعام اپنے مضمون میں جا بجا اشعار بھی درج کئے ہیں جن کا مقصود ان کے زعم میں اظہار شوخی یا تفنن طبع ہو تو لیکن ہماری دانست میں اس مضمون کے حصہ نثر کا سب سے بڑا وصف اس کی تلخی اور حصہ نظم کی سب سے بڑی صنعت اس کی بے نمکی ہے۔
معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کی شان جلالی کو سب سے زبردست تحریک اس خیال نے پہونچائی کہ مولوی کا لقب و عرف عام میں ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو زبان عربی میں دینی معلومات پر عبور رکھتے ہوں کیوں ایسے لوگوں کے نام کے ساتھ استعمال کیا گیا جن پر مولوی کی یہ پرانی دقیانوسی تعریف صادق نہیں آتی۔ چنانچہ اسی حالت عتاب و بر افروختگی میں آپ دکن ریویو کے مولویوں کی نسبت فرماتے ہیں:
گر مولویت ہمیں است کہ ایشاں وارند
وائے گر پس امروز بو و فردا
بہتر ہوتا کہ مولانا شاعر کے مشہور شعر
اگر اسلام ہمیں است کہ واعظ دارد
وائے گر از پس امروز بود فردائے
میں اپنے مجتہدانہ تصرف سے فن عروض کو یوں زیر بار احسان نہ فرماتے۔ اور سکتہ متواتر و زحاف مسلسل کے جدید صنائع کی ایجاد سے مشرقی شاعری کو جو نکتہ چینوں کی نظروں میں پہلے ہی تصنع کے بوجھ کے تلے بہت کچھ دبی ہوئی ہے اور زیادہ گرانبار نہ کرتے۔
چونکہ ہمارا عمل ظن المومنین خیرا کے اصول پر ہے اس لئے ہم یہ تو نہ کہیں گے کہ مولانا کے مضمون زیر بحث کا تعریضی حصہ اس معتدل نکتہ چینی کا جواب ہے جو اسلام نمبر سلک اوّل میں رحمۃ للعالمین کی شرح کرتے وقت ہم نے مولانا کی مراتب فضیلت و مدارج مولویت کا ادب قائم رکھ کر کی تھی خواہ ہمارے پاس اصول مذکور کی عمومیت میں شان استثنا پیدا کرنے کے لئے یہ دلیل موجود ہی ہو کہ اس سے پہلے دکن ریویو میں لفظ مولوی کا استعمال علی الرغم استدلال مولانا ہوا ہے۔ لیکن مولانا کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوا البتہ اتنا ضرور کہیں گے کہ مولانا نے اس لفظ کو ایک خاص گروہ اور ایک خاص طبقہ سے مخصوص کرنے میں اس بخل سے کام لیا ہے جس کی ہمیں ان کی سی روشن خیال اور زمانہ شناس عالم سے توقع نہ تھی۔ زمانہ سدا ایک نہیں رہتا۔ جو حالت قدیم سے چلی آرہی تھی ممکن نہیں کہ وہ بدستور قائم رہے اور زمانے کے گوناگوں انقلابات کے سانچہ میں ڈھل کر نئی شکل نہ پیدا کرے۔
جہاں نے ساز بدلا ساز نے نغموں کی گت بدلی
گتوں نے رنگ بدلا رنگ نے یاروں کی مت بدلی
فلک نے دور بدلا دور نے انسان کو بدلا
گئے ہم تم بدل قانون بدلا سلطنت بدلی
(اکبر الہ آبادی)
اب وہ وقت آگیا ہے کہ پرانے رسمی عقیدے چھوڑے جائیں اور نئے عقائد زمانہ کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے لحاظ سے قائم کئے جائیں۔ اور انہیں ضرورتوں اور مصلحتوں کا ایک اقتضا یہ بھی ہے کہ لفظ مولوی جس کا اطلاق پہلے صرف عربی جاننے والوں پر ہوتا تھا تعلیم یافتہ گروہ کے ان مسلمان افراد پر ہو جن کی تعداد بفضل خدا روز بہ ترقی کر رہی ہے اور جو اپنے ناموں کے ساتھ لفظ مسٹر کا یورپین اور بدیہی دم چھلا لگانے کے مقابلہ میں اپنی ہی زبان کا کوئی لفظ استعمال کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔
لفظ مولوی کی صرفی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ اصل میں مولائی تھا جس کے معنی تھے میرے آقا۔ لیکن بوتہ تعلیل میں پگھل کر مولوی ہوگیا اور عرف عام کی توجہ سے پیرایۂ معنی سے عاری ہو کر یہ خود تو صدرہ اور شمس بازغہ کی رٹنے والوں کا علم ہوگیا اور ریائے متکلم علم بردار بن گئی ۔اس سے واضح ہوگا کہ مولوی محض ایک اعزازی لقب تھا جس کا استعمال مخاطب یا غائب کے نام کے ساتھ بلحاظ اوس کے علو شان کے تکریماً کیاجاتا تھا، عام اس سے کہ وہ شان دینی ہو یا دنیوی۔ چنانچہ اب تک بھی سلطان مراکو مولائی کہلاتے ہیں۔ اور سلطان المعظم کو بھی مولانا کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے ۔ البتہ چونکہ اسلام نے ہمیشہ علم و فضل کا بہت بڑا مرتبہ مانا ہے اسی لئے لفظ مولوی خصوصیت کے ساتھ تعلیم یافتہ اشخاص کے لئے استعمال ہونے لگا۔ اور چونکہ تعلیم کی حصول کا ذریعہ مسلمانوں کے لئے زبان عربی ہی تھی اس لئے مولوی وہی کہلاتے تھے جو عربی میں دستگاہ رکھتے تھے۔
لیکن اس زمانہ میں جب کہ حصول علم کے ذرایع عربی ہی تک محدود نہیں جب کہ اردو ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی اور ملکی زبان بن کر روز افزوں ترقی کر رہی ہے، جب کہ انگریزی فارسی، عربی اردو ایک مسلمان نوجوان کی تعلیم میں منفرداً یا مجتمعا کافی حصہ لے رہی ہیں۔ جب کہ لسانی عصبیت کا تقاضا ہورہا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ملکی زبان میں انہیں زبانوں کے الفاظ کی آمیزش جائز رکھی جائے جن سے اس کا زیادہ قریب کا رشتہ ہے ۔ لفظ مولوی کو صرف ان چند لوگوں کے لئے مخصوص کر دینا جو ضرب یضرب ضرباً کی حد سے ایک انچ آگے نہ بڑھ سکے ہوں اس لفظ پر سخت ظلم کرنا ہے۔
ہمارے اس بیان سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم خدا نخواستہ عربی کے مخالف ہیں۔ گو ہم خود شومی قسمت سے اس زبان میں اتنی مہارت نہیں رکھتے کہ مولانا ابوالوفا کے معیار کے لحاظ سے لقب مولوی کے مستحق قرار پا سکیں لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس شخص کو انگریزی کے ساتھ عربی نہیں آتی وہ صحیح معنوں میں تعلیم یافہت نہیں کہاجاسکتا۔ انگلستان میں تعلیم یافتہ ہونے کے لئے فرانسیسی و لاطینی جاننا لازمی ہے ۔ دنیائے اسلام میں یہی لزوم عربی کی طرف منتقل ہوجاتا ہے، لیکن اس سے پھر بھی یہ نہیں لازم آتا کہ مولوی کا اعزازی و تکریمی لقب کسی مسلمان گریجویٹ یا انڈر گریجویٹ یا کسی اور لکھے پڑھے مسلمان کو نہ دیا جائے ۔ ہماری رائے میں وہ وقت آگیا ہے کہ مولویت اور عربیت میں تفریق کردی جائے ۔ دونوں لازم و ملزوم نہیں ہیں۔ نئی تعلیم یافتہ جماعت میں کثرت سے ایسے لوگ گنائے جا سکتے ہیں جو مسٹر کہلانا پسند نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے لئے کون سا اعزازی لقب تجویز کیا جائے ۔ اردو میں صرف دو لفظ ایسے ہیں جو موزوں طور پراس ضرورت کو رفع کرتے ہیں۔ منشی اور مولوی۔ ان دونوں میں زیادہ جامع مولوی ہے۔ منشی سے انشا پرداز مراد ہے۔
مولوی سے مراد ہے مخدومی اور اس لئے وہ انگریزی مسٹر کا صحیح مرادف و بدل ہوسکتا ہے۔ لفظ مسٹر کی تاریخ بھی انگریزی میں وہی ہے جو عربی میں مولوی کی ہے۔ یہ پہلے ماسٹر تھا جس کے معنی مالک یا آقا کے ہیں۔ بدلتے بدلتے مسٹر ہوگیا۔ انگلستان کی قومی یک رنگی و یکجہتی کو دیکھئے کہ مسٹر کے لقب کا مستحق ادنی سے اعلیٰ تک اپنے اپنے طبقہ میں ہر شخص ہے ۔ جان مارلے با ایں ہمہ جلالت قدر و تبحر علمی مسٹر کہلاتے ہیں اور ایک ادنی درجہ کا جاہل گورا جس کا باپ لندن کی گلیوں میں بوٹ صاف کرتے کرتے مر گیا وہ بھی مسٹر ہی کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔
ہمارے ملک میں ابھی تک اتنی آزادی نہیں آئی اور اس کے علاوہ لفظ مولوی کا پرانا مفہوم لوگوں کے ذہن میں اس قدر راسخ ہوگیا ہے کہ ابھی توقع نہیں ہے کہ اس کا استعمال ہر کس و ناکس کے نام کے ساتھ کیا جائے ۔ لیکن جیسا کہ ہم اوپر بیان کرچکے ہیں وہ وقت ضرور آگیا ہے کہ تعلیم یافتہ مسلمان عام اس سے کہ وہ عربی جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں آپس میں ایک دوسرے کو مولوی کے لقب سے مخاطب کیا کریں۔ ریاست حیدرآباد دکن میں یہ راز اچھی طرح سمجھ لیا گیا ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس بارہ میں ہندوستان کے دوسرے حصے اس کی تقلید نہ کریں۔
مولانا ابو الوفا اور ان کے ہم خیال علما اگر ہماری اس تحریر کو اپنے حقوق میں غاصبانہ دست اندازی سے تعبیر کریں تو ہم ان کی خدمت بابرکت میں نہایت ادب سے عرض کریں گے کہ ان کے مقدس گرو کے لیے مولانا اور علماء کے مہتم بالشان القاب موجود ہیں جن کے استعمال میں ہم عامیوں اور جاہلوں کی مجال نہیں کہ ان کے شریک و سہیم ہوسکیں۔ مولوی میں ی صیغہ واحد متکلم کی ہے اور اگر ایک شخص دوسرے شخص کو مولوی کہے تو اخلاق محمدی کے لحاظ سے اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی قباحت ہی نہیں بلکہ ہر طرح اولیٰ و انسب ہے ۔ بر خلاف اس کے مولانا میں نا جمع متکلم ہے۔ اور اس کا استعمال اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ مخاطب مخدوم انام ہے اور یہ ایک ایسا درجہ ہے جو حقیقت میں علمائے کرام ہی کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ طبقہ علما کے لئے علامی و فہامی اور حکیم و مجتہد کے القاب کیا کچھ کم موجود ہیں جو انہیں مولوی کے لقب سے جدائی اختیار کرنا بھی شاق گذرے۔
از: فقیر
(ماخوذ از رسالہ: دکن ریویو سلسلۂ جدید (اسلام نمبر، سلک دوم 1907)