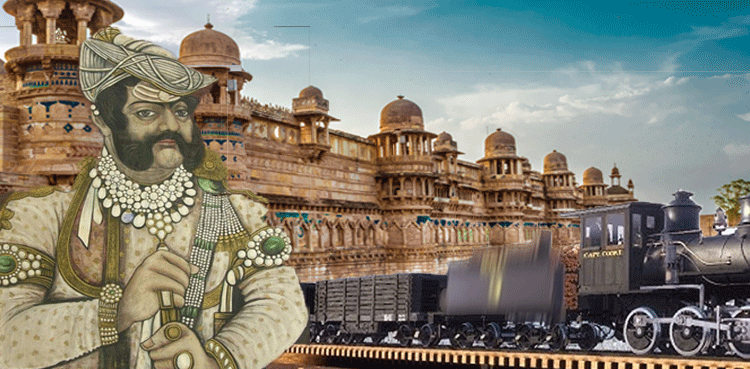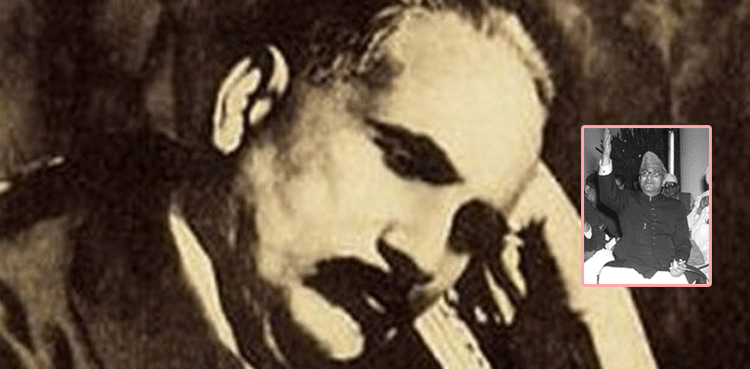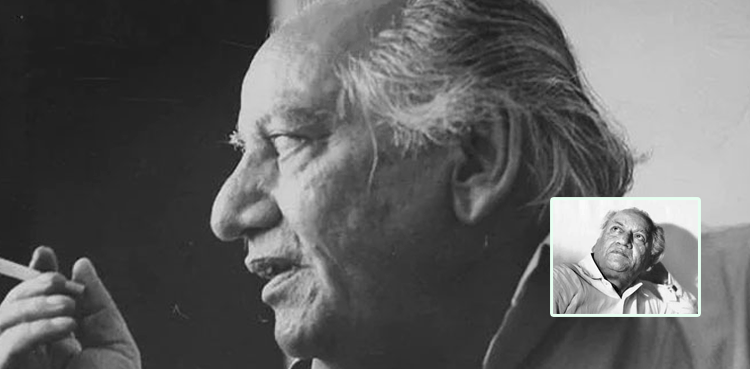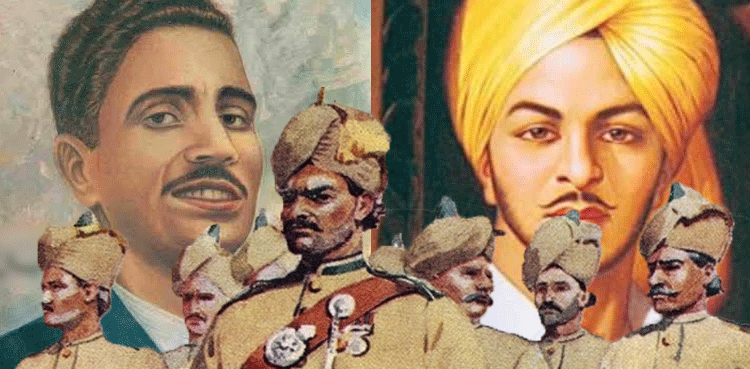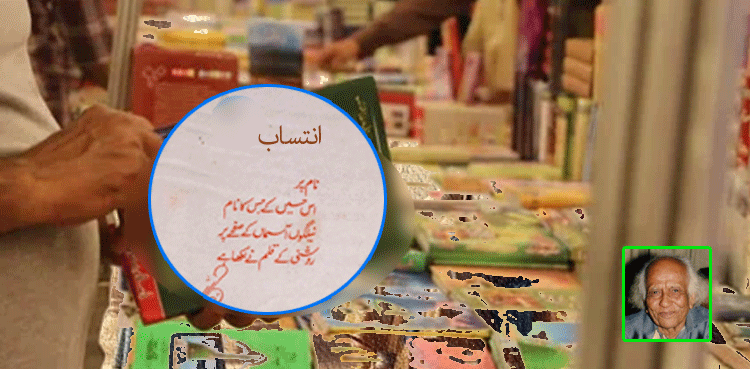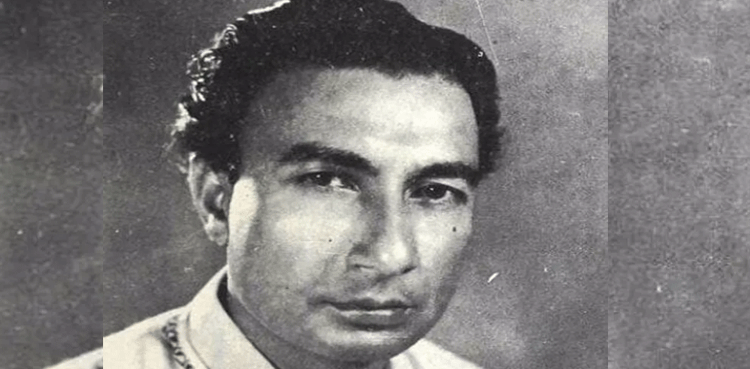’میرا ہندوستان‘ اینگلو انڈین مہم جو، شکاری اور مصنّف جم کاربٹ کی کتاب ہے جو متحدہ ہندوستان کے پسے ہوئے اور مجبور طبقات کی زندگی کو ہمارے سامنے لاتی ہے۔
فن و ادب سے متعلق مزید تحریریں پڑھیں
جم کاربٹ لکھتے ہیں، ’’میرا ہندوستان‘‘ میں، میں نے اُس ہندوستان کے بارے بات کی ہے جو میں جانتا ہوں اور جس میں چالیس کروڑ انسان آباد ہیں اور ان میں نوے فیصد انتہائی سادہ، ایماندار، بہادر، وفا دار اور جفا کش ہیں اور روزانہ عبادت کرتے ہیں۔ یہ لوگ بلاشبہ غریب ہیں اور انہیں ’ہندوستان کی بھوکی عوام‘ کہا جاتا ہے اور ان کے درمیان میں نے زندگی گزاری ہے اور مجھے ان سے محبت ہے۔‘‘
اس کا ترجمہ محمد منصور قیصرانی نے کیا ہے۔ جم کاربٹ نے اپنی اس کتاب میں ایک نوجوان جوڑے کی درد ناک کہانی بیان کی ہے، جس کے دادا بنیے کے جال اور سود کی دلدل میں پھنس گئے تھے اور اسے بھی اپنے والد کی موت کے بعد یہ رقم اتارنے پر مجبور کیا جارہا تھا۔
بدھو ذات کا اچھوت تھا اور جتنے سال وہ میرے پاس کام کرتا رہا، ایک بار بھی نہیں مسکرایا کہ اس کی زندگی اتنی مشکل تھی۔
اس کی عمر پینتیس برس تھی اور لمبا اور دبلا تھا۔ اس کی بیوی اور دو بچّے بھی اس کے ساتھ تھے جب وہ میرے پاس ملازمت کے لیے آیا۔ چوں کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ کام کرے، سو میں نے اسے واحد ممکن کام پر لگا دیا جو براڈ گیج سے میٹر گیج والی بوگیوں میں کوئلے کی منتقلی تھا۔ دونوں بوگیوں میں چار فٹ کی ڈھلوان ہوتی تھی اور کوئلہ کچھ تو پھینک کر اور کچھ ٹوکریوں میں اٹھا کر منتقل کیا جاتا تھا۔
یہ کام انتہائی دشوار تھا کہ پلیٹ فارم پر چھت نہیں تھی۔ سردیوں میں یہ لوگ شدید سردی میں کام کرتے اور اکثر کئی کئی روز مسلسل بارش میں بھیگتے رہتے اور گرمیوں میں اینٹوں کے پلیٹ فارم اور دھاتی بوگیوں سے نکلنے والی شدید گرمی ان کے ننگے پیروں پر چھالے ڈال دیتی۔ اپنے بچوں کے لیے روٹی کے حصول کی خاطر نووارد کے ہاتھوں میں بیلچہ انتہائی ظالم اوزار ہے۔ پہلے روز کے کام کے بعد کمر درد سے ٹوٹ رہی ہوتی ہے اور ہتھیلیاں سرخ ہو چکی ہوتی ہیں۔ دوسرے روز ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں اور کمر کا درد اور بھی شدید تر ہو جاتا ہے۔ تیسرے روز چھالے پھٹ جاتے ہیں اور ان میں پیپ پڑ جاتی ہے اور کمر سیدھی کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہفتے یا دس دن انسان محض ہمت کے بل بوتے پر کام جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ بات میں اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں۔
بدھو اور اس کی بیوی انہی مراحل سے گزرے اور اکثر انہیں سولہ گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا اور بمشکل خود کو گھسیٹ کر وہ اس کوارٹر تک جاتے جو میں نے انہیں رہائش کے لیے دیا تھا۔ میں نے انہیں کئی بار بتایا کہ یہ کام ان کے بس سے باہر ہے اور وہ کوئی دوسرا اور نسبتاً آسان کام دیکھیں، مگر بقول بدھو، اس نے آج تک اتنے پیسے نہیں کمائے تھے، سو میں نے انہیں کام جاری رکھنے کی اجازت دی۔ مگر ایک دن آ گیا کہ ان کی کمر کا درد ختم ہو گیا اور وہ کام سے جاتے ہوئے اتنے خوش ہوتے جتنا کام پر آتے ہوئے ہوتے تھے۔
اُس وقت میرے پاس دو سو افراد کوئلے کی منتقلی کے لیے کام کر رہے تھے کہ کوئلے کی مقدار بہت زیادہ تھی اور کوئلہ ہمیشہ گرمیوں میں زیادہ بھیجا جاتا ہے۔ ہندوستان اُس دور میں سامانِ تجارت برآمد کر رہا تھا سو غلّے، افیون، نیل، کھالوں اور ہڈیوں سے بھری ویگنیں کلکتہ جاتیں اور واپسی پر ان میں کوئلہ لدا ہوتا اور کانوں سے کوئلہ آتا۔ اس میں سے پانچ لاکھ ٹن موکمہ گھاٹ سے گزرتا۔
ایک روز بدھو اور اس کی بیوی کام پر نہ آئے۔ کوئلے والے مزدوروں کے نگران چماری نے بتایا کہ انہیں پوسٹ کارڈ ملا اور وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ جتنی جلدی ممکن ہوا، واپس لوٹ آئیں گے۔ دو ماہ بعد دونوں واپس لوٹے اور اپنے کوارٹر میں رہنے اور کام کرنے لگے۔ اگلے سال تقریباً اسی وقت یہ لوگ پھر غائب ہو گئے۔ تاہم اب ان کی صحت بہتر ہو گئی تھی۔ اس بار وہ لوگ تین ماہ غائب رہے اور واپسی پر تھکے ماندہ اور پریشان حال آئے۔ میری عادت ہے کہ جب تک مشورہ نہ لیا جائے یا کوئی اپنے حالات خود نہ بتائے، میں اپنے عملے کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ ہندوستانیوں کے لیے یہ دکھتی رگ ہوتی ہے۔ اس لیے مجھ علم نہ ہو سکا کہ ہر سال پوسٹ کارڈ ملنے پر بدھو کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ میرے ملازمین کی ڈاک ان کے نگرانوں کو دے دی جاتی تھی جو متعلقہ بندے کو پہنچاتے تھے۔ اس لیے میں نے چماری کو ہدایت کی کہ جب بھی بدھو کو اگلا پوسٹ کارڈ ملے، وہ بدھو کو میرے پاس بھیج دے۔ نو ماہ بعد جب کوئلے کی آمد و رفت معمول سے زیادہ تھی اور ہر آدمی اپنی بساط سے بڑھ کر کام کر رہا تھا، بدھو پوسٹ کارڈ لیے میرے کمرے میں داخل ہوا۔
پوسٹ کارڈ کی زبان مجھے نہیں آتی تھی سو میں نے بدھو سے کہا کہ وہ پڑھ کر سنائے۔ تاہم وہ خواندہ نہیں تھا اس لیے اس نے بتایا کہ چماری نے پڑھ کر اسے سنایا تھا کہ اس کے مالک کی فصل تیار تھی اور وہ فوراً اسے بلا رہا تھا۔ پھر بدھو نے اس روز مجھے اپنی کہانی سنائی جو ہندوستان کے لاکھوں غریبوں کی کہانی ہے۔
’’میرا دادا کھیت مزدور تھا اور اس نے گاؤں کے بنیے سے دو روپے ادھار لیے تھے۔ بنیا نے ایک روپیہ ایک سال کے سود کے طور پر پیشگی رکھوا لیا اور میرے دادا سے بہی کھاتے پر انگوٹھا لگوا لیا (حساب کتاب کا کھاتہ)۔ جب بھی ممکن ہوتا، میرا دادا چند آنے سود کے نام پر ادا کرتا رہا۔ دادے کی وفات پر یہ ادھار میرے باپ کو منتقل ہوا اور اُس وقت تک یہ ادھار پچاس روپے بن چکا تھا۔ اس دوران بوڑھا بنیا بھی مر گیا اور اس کے بیٹے نے اس کی جگہ سنبھالی اور کہا کہ چونکہ ادھار بہت بڑھ گیا ہے، سو نئے سرے سے معاہدہ کرنا ہوگا۔ میں نے یہ معاہدہ کیا اور چونکہ میرے پاس اسٹامپ پیپر کے لیے پیسے نہیں تھے، سو بنیے کے بیٹے نے وہ بھی سود اور اصل رقم کے ساتھ لکھ لیے جو اب ایک سو تیس روپے سے زیادہ تھا۔ بنیے کے بیٹے نے ایک شرط پر سود کی شرح پچیس فیصد کرنے کی پیشکش کی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہر سال اس کی فصلیں کاٹنے کے لیے آیا کروں۔ جب تک سارا ادھار اتر نہ جائے، ہمیں یہ کام کرتے رہنا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق مجھے اور میری بیوی کو بنیے کی فصلیں مفت میں کاٹنی ہوتی ہیں جو الگ کاغذ پر لکھا گیا تھا اور اس پر میرا انگوٹھا لگایا گیا۔ ہر سال کام کے بعد بنیے کا بیٹا کاغذ کی پشت پر حساب کتاب کر کے میرے انگوٹھے لگواتا ہے۔ علم نہیں کہ ادھار اب کتنا بڑھ چکا ہوگا کیونکہ میں نے ابھی تک کوئی پیسہ واپس نہیں کیا۔ اب چونکہ میں آپ کے پاس کام کر رہا ہوں، سو میں نے پانچ، سات اور تیرہ، کل مل ملا کر پچیس روپے ادا کیے ہیں۔‘
بدھو نے کبھی اس ادھار کی ادائیگی سے انکار کا سوچا بھی نہیں۔ ایسی سوچ ممکن بھی نہیں تھی کہ اس طرح نہ صرف اس کا منہ کالا ہوتا بلکہ اس کے آباؤ اجداد کے نام پر بھی دھبہ لگ جاتا۔ اس طرح وہ نقد اور محنت، ہر ممکن طور پر ادھار کی ادائیگی کرتا رہا اور اسے علم تھا کہ کبھی اس ادھار کو ادا نہیں کر پائے گا اور یہ اس کے بیٹے کو منتقل ہو جائے گا۔
بدھو سے پتہ چلا کہ بنیے کے دیہات میں ایک وکیل بھی رہتا ہے، میں نے اس کا نام اور پتہ لیا اور بدھو کو کام پر لوٹ جانے کا کہا اور اسے یقین دلایا کہ میں بنیے کا معاملہ سنبھالتا ہوں۔ اس کے بعد وکیل سے طویل خط و کتابت شروع ہو گئی۔ وکیل مضبوط اعصاب کا برہمن تھا جسے بنیے سے نفرت تھی کہ بنیے نے اسے گھر سے باہر بلا کر اس کی بے عزتی کی تھی اور کہا تھا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے۔ وکیل نے بتایا کہ بہی کھاتا جو وراثت میں ملا تھا، وہ عدالت میں پیش نہیں کیا جاسکتا کہ اس پر لگے انگوٹھوں والے افراد مر چکے ہیں۔
بنیے نے بدھو کو دھوکہ دے کر اس سے نئے کاغذ پر دستخط کرائے جس کے مطابق بدھو نے بنیے سے پچیس فیصد شرح سود پر ڈیڑھ سو روپے ادھار لیے تھے۔ وکیل نے بتایا کہ اس کاغذ کو ہم نظرانداز نہیں کر سکتے کہ بدھو اس کی تین قسطیں ادا کر چکا تھا اور ان قسطوں کے ثبوت کے طور پر اس کے انگوٹھے بھی لگے تھے۔ جب میں نے وکیل کو پورے ادھار کی رقم اور پچیس فیصد سود کی رقم بھی بھیجی تو بنیے نے سرکاری کاغذ تو دے دیا مگر وہ ذاتی معاہدہ دینے سے انکار کر دیا جس کے مطابق بدھو اور کی بیوی اس کی فصلیں مفت کاٹتے۔
جب وکیل کے مشورے پر میں نے بنیے کو بیگار کے مقدمے کی دھمکی دی تو پھر جا کر اس نے معاہدہ ہمارے حوالے کیا۔
جتنی دیر ہماری خط و کتابت ہوتی رہی، بدھو بہت پریشان رہا۔ اس نے مجھ سے اس بارے ایک لفظ بھی نہیں کہا مگر جس طور وہ مجھے دیکھتا تھا، واضح کرتا تھا کہ اس نے طاقتور بنیے کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے مجھ پر شاید بھروسہ غلط کیا ہے۔ اسے یہ بھی فکر ہوگی کہ اگر کسی وقت بنیا آ کر اس سے پوچھے کہ یہ سب کیا ہے تو وہ کیا جواب دے گا۔ ایک روز مجھے مہر لگا ایک موٹا لفافہ ملا جس میں انگوٹھوں کے نشانات سے بھرے کاغذات تھے اور وکیل کی فیس کی ایک رسید بھی شامل تھی اور بدھو کے لیے ایک خط بھی، کہ وہ اب آزاد ہو چکا ہے۔ اس سارے معاملے پر مجھے سوا دو سو روپے ادا کرنے پڑے۔
اس روز شام کو بدھو کام سے گھر جا رہا تھا کہ میں اسے ملا اور لفافے سے کاغذات نکال کر اسے دیے اور ایک ماچس بھی دی کہ اسے جلا دے۔ اس نے کہا: ‘نہیں صاحب۔ آپ ان کاغذات کو نہ جلائیں۔ آج سے میں آپ کا غلام ہوں اور خدا جانتا ہے کہ ایک روز میں آپ کا ادھار واپس کر دوں گا۔‘ بدھو نہ صرف کم گو تھا بلکہ کبھی مسکرایا بھی نہیں تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ وہ انہیں جلانا نہیں چاہتا تو اپنے پاس رکھ لے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر میرے پاؤں چھوئے اور جب سیدھا ہو کر گھر جانے کو مڑا تو اس کے کوئلے سے بھرے چہرے سے آنسوؤں کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔
تین نسلوں سے غلامی کی زنجیر میں جکڑا ایک انسان آزاد ہوا مگر لاکھوں ابھی تک قید تھے۔ مگر مجھے اس سے زیادہ کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی الفاظ بدھو کے خاموش جذبات سے ہوئی تھی جب وہ آنسو بھری آنکھوں سے ٹھوکریں کھاتا اپنی بیوی کو یہ بتانے گیا کہ بنیے کا ادھار اتر چکا ہے اور وہ اب آزاد ہیں۔