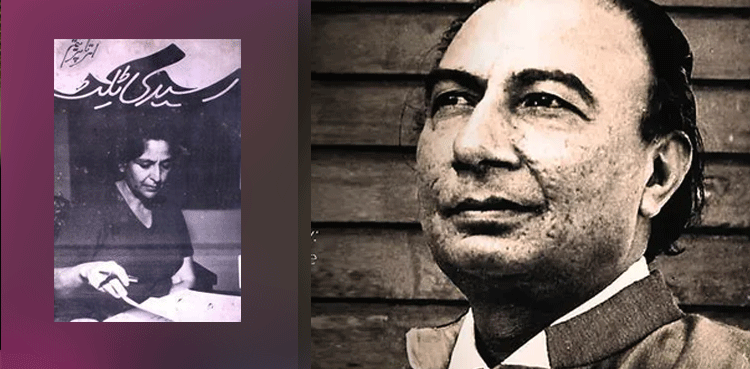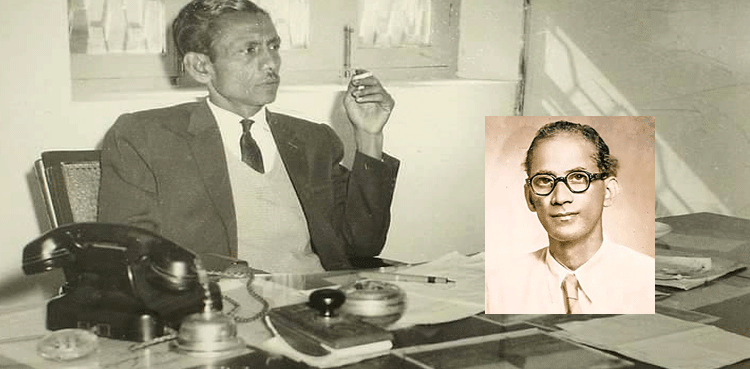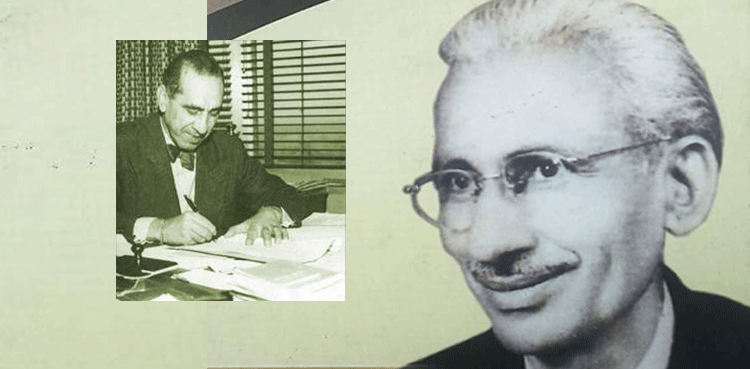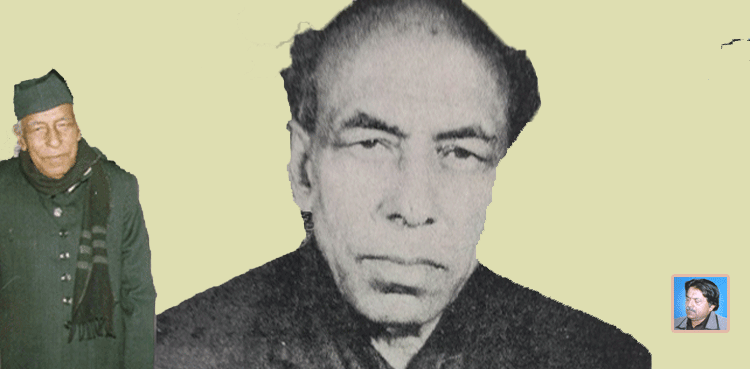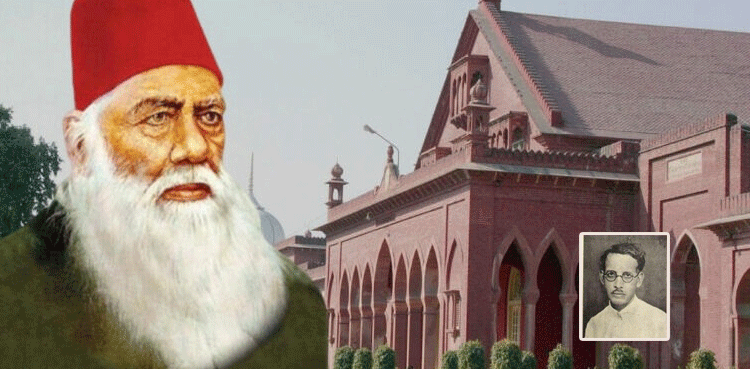معین احسن جذبی کا نام اردو ادب کے معتبر اور نمایاں شاعروں میں شامل ہے جن کی غزلوں کے متعدد اشعار کو ضرب المثل کا درجہ حاصل ہوا اور جذبی کو بہت سراہا گیا۔
ادبی مضامین اور مشاہیر کی تحریریں پڑھنے کے لیے لنک کھولیں
معین احسن جذبی 13 فروری 2005ء کو ہندوستان کے مشہور شہر علی گڑھ میں انتقال کر گئے تھے۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے شاعر، نقاد اور فکشن رائٹر جو غضنفر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، انھوں نے معین احسن جذبی سے اپنی ایک ملاقات کا مختصر احوال اور ان کے فن و شخصیت پر ایک مضمون سپردِ قلم کیا تھا جس سے کچھ پارے ہم یہاں نقل کر رہے ہیں۔ غضنفر لکھتے ہیں:
کچھ نام ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسرے ناموں میں بھی جذب ہو جاتے ہیں اور اس طرح جذب ہوتے ہیں کہ دوسرے نام جب بھی لیے جاتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ خودبخود سامنے آجاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام جذبی کا ہے، جو فیضؔ، جوشؔ، اور مجازؔ کے ناموں کے ہمراہ اپنے آپ ابھر آتا ہے، مگر جوش، فیض اور مجاز کے ساتھ جذبی کا نام یوں ہی نہیں ابھرتا بلکہ اس لیے اپنی صدا بلند کرتا ہے کہ میدانِ شعر و سخن میں جذبی نے بھی وہی جذب و مستی دکھائی ہے اور اسی جوش و خروش کا مظاہر ہ کیا ہے جس کا نظارہ جوش، فیض اور مجاز کے شعری کارناموں میں نظر آتا ہے۔
یہ اور بات ہے کہ جذبی ان سے مختلف ہیں کہ جوش، فیض اور مجاز کی شہرت کے اسباب کچھ دوسرے بھی ہیں جب کہ جذبی صرف اور صرف اپنی شعری کاوشوں کے بل بوتے پر مشہور ہوئے۔ جذبی نے جوش کی طرح سر پر یادوں کا سہرا باندھ کر اپنی کوئی بارات نہیں نکالی۔ نہ ہی وہ فیض کی صورت دیگر سرگرمیوں میں سرگرم ہوئے اور زنجیر گھسیٹتے ہوئے پا بہ جولاں کوئے یار سے سوئے دار گئے۔ مجاز کی مانند مجنوں بن کر انھوں نے کسی لالہ رخ کے کاشانے کے چکّر بھی نہیں لگائے اور نہ ہی اپنی رودادِ سخنِ مختصر میں بلا نوشی کے قصّے جوڑے۔ وہ تو بس مثلِ ملنگ ایک گوشے میں پڑے رہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے گدازِ شب میں اپنی شاعری کی شمع فروزاں کرتے رہے۔ خلوت میں پڑے پڑے شعری کشف کے ذریعے حیات و کائنات سے پردے اٹھاتے رہے اور یہ انکشافات کرتے رہے،
دل کو ہونا تھا جستجو میں خراب
پاس تھی ورنہ منزلِ مقصود
تجھے آسماں ناز ہے ایک شفق پر
زمیں پر تو ہیں کتنے خونیں نظارے
یہ سوچتا ہوں کہ بدلا بھی ہے نظامِ الم
یہ دیکھتا ہوں کہ موجِ نشاط بھی ہے کہیں
اے موجِ بلا ان کو بھی ذرا دو چار تھپیڑے ہلکے سے
کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفاں کا نظارہ کرتے ہیں
اپنے ان محسوسات و انکشافات کی شمعِ فروزاں سے صدر جمہوریۂ ہند اندر کمار گجرال اور امریکہ کے سابق وزیرِ خارجہ میڈلین البرائٹ تک کے ذہن و دل کو روشن کرنے والے جذبی کی اپنی زیست کا چراغ بچپن سے لے کر پیری تک ہمیشہ آندھیوں کی زد پہ رہا۔ کبھی باپ کی بے رخی اور بے توجہی کے جھونکے اٹھے، کبھی بے مہری حالات کے جھکّڑ چلے، کبھی ناقدریوں اور بے اعتنائیوں کے گرد باد گردش میں آئے۔ کبھی ناانصافیوں اور زیادتیوں کے بگولے کھڑے ہوئے، ان سب کے زور اور شور سے چراغِ حیاتِ جذبی ٹمٹمایا تو بہت مگر جذبی نے اپنے وجود کی لو کو مدھم نہیں ہونے دیا۔ ایسا بھی نہیں کہ ان حملوں کو وہ چپ چاپ سہہ گئے۔ کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لیا۔ انھوں نے ایک ایک سے انتقام لیا البتہ ان کے انتقام کا طریقہ الگ تھا۔ بدلہ لینے کا انھوں نے نرالا انداز نکالا۔
باپ کی بے رخی کا بدلہ لینے کے لیے انھوں نے اپنے بیٹے پر توجہ مرکوز کر دی اور ایسی توجہ مرکوز کی کہ بیٹے نے تعلیم سے لے کر ملازمت تک کے سارے مراحل ایک مرکز پر رہ کر طے کر لیے۔ ملازمت کے وہ تمام مدراج بھی جو تدریسی شعبوں میں حاصل کیے جاتے ہیں۔ جذبی نے اپنی طرح اپنے بیٹے کو یہاں وہاں اور ادھر اُدھر بھٹکنے نہیں دیا۔ گویا اپنی توجہ سے سہیل کو یمن کے بجائے علی گڑھ کے افق سے طلو ع کردیا۔
اپنی ناقدریوں کا انتقام یوں لیا کہ صبر و تحمل کو ہتھیار بنالیا اور اسے ایسا صیقل کیا کہ غالب ایوارڈ، اقبال سمّان، کل ہند بہادر شاہ ظفر ایوارڈ وغیرہ جیسے انعامات خود بخود ان کی جھولی میں آگرے۔ اپنے اسی صبر و تحمل سے انصاف پسندوں کو اپنے ساتھ کیا اور ان کے ذریعے اپنے دشمنوں کو بنا کچھ بولے اور کچھ کیے ذلیل و خوار بھی کر دیا اور ان کے اسی تحمل کی بدولت ان کی تخلیقات مجموعوں سے نکل کر پرائمری سطح سے لے کر ایم۔ اے تک کے نصابات میں داخل ہوگئیں اور ان کے بعض اشعار ایک ایک صاحبِ ذوق کی روح کا حصہ بن گئے۔
مجھے افسوس ہے کہ میں بہت قریب رہ کر بھی اس صوفی منش شاعرِ ملنگ اور مردِ آہن سے تقریباً دو ڈھائی سال کی مدّت میں ایک بار بھی نہ مل سکا۔ اور ملا بھی تو علی گڑھ سے باہر سیوان کے ایک مشاعرے میں۔ جذبی سے نہ ملنے کے دو اسباب تھے۔ ایک تو ان کے ادبی قد کا رعب جو عموماً قد شناس طالب علموں کے دل و دماغ پر طاری رہتا ہے اور دوسرے ان کی گوشہ نشینی اور اس گوشہ نشینی کے باعث یونی ورسٹی کیمپس کی فضاؤں میں پھیلی ہوئی ان کی بد دماغی کی افواہ۔ میں جذبی سے اس لیے بھی ملنا چاہتا تھا کہ انھیں کے ہم عصر شاعر فراقؔ گورکھپوری کا یہ شعر میری خواہش بن کر میرے ذہن میں گونجا کرتا تھا کہ،
آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم عصرو
جب یہ کہو گے ان سے تم کہ ہم نے فراق کو دیکھا تھا
مگر میں جب بھی ان کے گھر جانے کا ارادہ کرتا تو کبھی ان کے ادبی قد کا جنّ آگے بڑھ کر میرا راستہ روک دیتا تھا تو کبھی ان کی بد دماغی کی افواہ کا دیو میری راہ میں آکھڑا ہوتا حالاں کہ جب میں ان سے ملا تو ان کے ارد گرد نہ کوئی جنّ تھا اور نہ کوئی دیو۔ وہاں تو ایک ایسا مخلص، ملنسار اور باغ و بہار انسان تھا جو طالب علموں کے ساتھ بھی برابری کا سلوک اور دوستانہ برتاؤ کر رہا تھا اور خردوں کی صحبت میں بھی پوری طرح کھل کر ہنسی مذاق کے گل کھلارہا تھا اور لطف و انبساط کے گوہر لٹا رہا تھا۔
احمد جمال پاشا نے جب میرا تعارف کرایا تو جذبی صاحب اس درجہ خوش ہوئے جیسا کہ کوئی مشفق استاد یا شفیق باپ ہوتا ہے۔ مجھ سے ان کے خوش ہونے کی میرے خیال میں تین وجہیں رہی ہوں گی، پہلی وجہ یہ کہ میں اس شعبے کا طالب علم تھا جسے جذبی نے اپنا گھر سمجھا۔ دوسری یہ کہ میں اس زبان میں ریسرچ کررہا تھا جو انھیں اپنی جان کی طرح عزیز تھی اور تیسری شاید یہ کہ میرے اندر بھی وہ صلاحیت موجود تھی جس کی بدولت کوئی تخلیقی فن کار کسی کو اپنے قبیلے کا فرد سمجھنے لگتا ہے۔ ان میں قوی تر سبب یہ تھا کہ میں ان کے شعبے کا طالبِ علم تھا جو اس حقیقت کا غماز بھی تھا کہ اُن کو اپنے شعبے سے کس درجہ لگاؤ تھا، مگر افسوس کہ اس شعبے نے ان کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا اور اس حد تک گزند پہنچائی کہ انھوں نے برسوں اس کی طرف رخ نہیں کیا۔ یہ شعبے کی کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ روایت پہلے سے چلی آرہی تھی اور بعد تک باقی رہی۔ اس روایت کی آگ میں رشید احمد صدیقی بھی جلے، آلِ احمد سرور بھی جھلسے اور کئی دوسرے بھی اس کی لپٹوں میں لپیٹ لیے گئے۔ اس شعبے کی ایک مثبت اور مضبوط روایت بھی رہی۔ وہ یہ کہ بہت دنوں تک اس میں تخلیقیت کا بول بالا رہا۔ رشید احمد صدیقی، مجنوں گورکھ پوری، آلِ احمد سرور، معین احسن جذبی، خورشید الاسلام، خلیل الرحمان اعظمی، راہی معصوم رضا، شہریار، قاضی عبدالستار ایک سے ایک مشہورِ زمانہ تخلیق کار اس سے وابستہ رہے اور اپنے فن پاروں سے اس کے نام میں چار چاند لگاتے رہے مگر دل کو گداز کرنے، ذہن کو بالیدہ بنانے اور روح کو گرمانے والی اس روایت کو کسی کی نظر لگ گئی۔ غیر تخلیقیت کے سحر نے اس کے ارد گرد ایسا حصار کھڑا کیا کہ تخلیقیت کا داخلہ بند ہوگیا۔ تخلیقیت کے اکّے دکّے نمائندے کسی طرح داخل ہونے میں کام یاب ہوئے بھی تو وہ ہمیشہ غیر تخلیقی بلاؤں کی زد پہ رہے۔
سیوان کی اس ملاقات میں گوشہ نشینی اختیار کرنے اور مسلسل چپّی سادھ لینے والے جذبی نے ایسی جلوت پسندی اور محفل بازی کا ثبوت دیا کہ ہم دنگ رہ گئے۔ دورانِ دورِ میکشی انھوں نے ایسے ایسے قصّے سنائے اور نشے کی ترنگوں کے ساتھ لطائف کے ایسے ایسے شگوفے چھوڑے کہ ہم لوٹ پوٹ ہوگئے۔ عالمِ سرور میں ایک ایسا مقام بھی آیا جہاں جذبی نے ترنم سے غزلیں بھی سنائیں۔ ترنم سے غزلیں سنتے وقت بار بار مجھے ایک واقعہ یاد آتا رہا: کسی محفل میں یونی ورسٹی کے ایک استاد نے جذبی سے ترنم کی فرمائش کر دی۔ جسے سن کر جذبی چراغ پا ہوگئے اور غصّے میں ایسا دیپک راگ الاپنا شروع کیا کہ لیکچرر صاحب کو اپنا دامن بچانا مشکل ہوگیا۔ وہ تو بھلا ہو اس محفل میں موجود کچھ نبض شناس سینئر استادوں کا کہ جنھوں نے انگلیوں میں دبے سگار کو ماچس کی تیلی دکھا دکھا کر جذبی کی حالتِ جذب کو ٹھنڈا کیا ورنہ تو اس جونیر استاد کا اس دن خدا ہی حافظ تھا۔
اس واقعہ کے ساتھ ساتھ میں جذبی کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ ایک طرف تو جذبی کسی استاد کی درخواست پر برہمی کا اظہار کرتے ہیں اور دوسری جانب بغیر کسی فرمائش کے طلبہ کو ترنم سے غزل سناتے ہیں۔ جذبی کی شخصیت کا یہ تضاد پوری طرح تو سمجھ میں نہیں آیا، ہاں اتنا ضرور محسوس ہوا کہ جذبی طریقتِ شعر و سخن کے مجذوب تھے۔ مجذوب جو صرف من کی سنتا ہے۔ من کہتا ہے تو اللہ ھو کا نعرۂ مستانہ بھی لگاتا ہے اور من نہیں کہتا ہے تو بس ہُو کا عالم لیتا ہے۔
غضنفر اپنے اس خاکے میں مزید لکھتے ہیں، دوسرے دن جب میں احمد جمال پاشا سے رخصت کی اجازت لینے گیا تو انھوں نے بتایا کہ جذبی صاحب میرے اخلاق اور فرماں برداری کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور میرے ایک شعر کی بھی۔ جمال پاشا نے یہ بھی بتایا کہ جذبی صاحب Talent کی بڑی قدر کرتے ہیں اور اپنے لائق شاگردوں سے محبت بھی بہت فرماتے ہیں اور ان کی یہ محبت ہی ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کر لینے کے باوجود میری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور یہاں تک آنے میں خاصی زحمت بھی اٹھائی۔
’’پاشا صاحب! آپ تو انھیں بہت قریب سے جانتے ہیں اور یہاں کی اس مختصر ملاقات میں مجھے بھی محسوس ہوا کہ وہ مجلسی آدمی ہیں اور کافی زندہ دل بھی۔
’’پھر ان کی اس گوشہ نشینی کا کیا راز ہے؟ وہ گھر سے کیوں نہیں نکلتے؟ شعبے میں کیوں نہیں آتے؟ یونیورسٹی کی محفلوں میں شرکت کیوں نہیں کرتے؟ دنیا سے بے زار کیوں ہو گئے ہیں؟
میری بات پر جمال پاشا خاصے اداس ہوگئے اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے نہایت سنجیدہ لہجے میں بولے :
’’غضنفر! تم جذبی صاحب کے کچھ شعر سن لو، شاید تمھارے سوالوں کا جواب مل جائے۔‘‘
اس حرص و ہوا کی دنیا میں ہم کیا چاہیں، ہم کیا مانگیں
جو چاہا ہم کو مل نہ سکا، جو مانگا وہ بھی پانہ سکے
مہکا نہ کوئی پھول نہ چٹکی کوئی کلی
دل خون ہو کے صرفِ گلستاں ہوا تو کیا
زندگی اک شورشِ آلام ہے میرے لیے
جو نفس ہے گردشِ ایام ہے میرے لیے
اور آخر میں یہ شعر بھی،
دنیا نے ہمیں چھوڑا جذبی، ہم چھوڑ نہ دیں کیوں دنیا کو
دنیا کو سمجھ کر بیٹھے ہیں، اب دنیا دنیا کون کرے
واقعی ان شعروں سے میرے سوالوں کے جواب مل گئے اور غورکرنے پر یہ راز بھی کھل گیا کہ گوشہ نشینی اختیار کرنے کے باوجود علی گڑھ سے میلوں دور احمد جمال پاشا کی محفل میں جذبی کیوں گئے؟ اور اپنے قریب کی محفلوں میں کیوں نہیں آتے؟
جذبی کی رودادِ سفر اور اندازِ حیات پر غور کرتے وقت یہ بھی محسوس ہوا کہ جذبی سادہ اور سیدھے ضرور تھے، مگر ان میں ٹیڑھ پن بھی بہت تھا۔ ان کی شخصیت کے اسی ٹیڑھ پن نے انھیں زمانہ تو زمانہ اپنے باپ کے آگے بھی جھکنے نہیں دیا۔ اسی نے انھیں بھیڑ سے نکال کر الگ کیا، منفرد بنایا، مضبوط کیا، مسرور کیا۔ لگتا ہے جذبی کے رفیقِ کار مشہور شاعر خلیل الرحمن اعظمی نے اپنا یہ شعر شاید جذبی کے لیے بھی کہا تھا،
لوگ ہم جیسے تھے اور ہم سے خدا بن کے ملے
ہم وہ کافر ہیں کہ جن سے کوئی سجدہ نہ ہوا