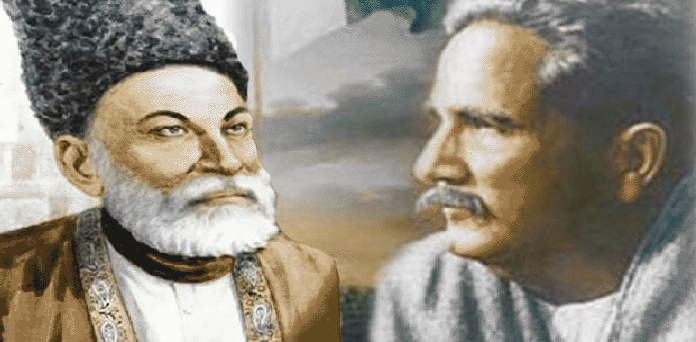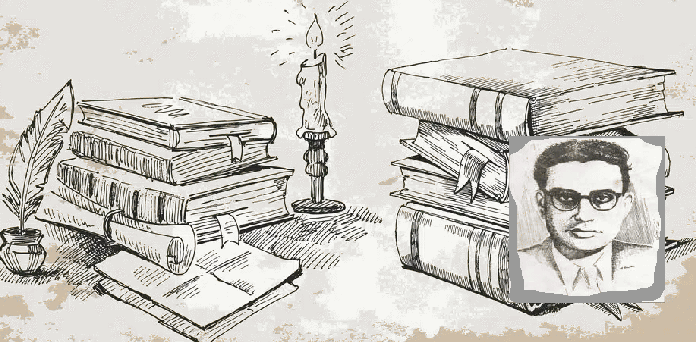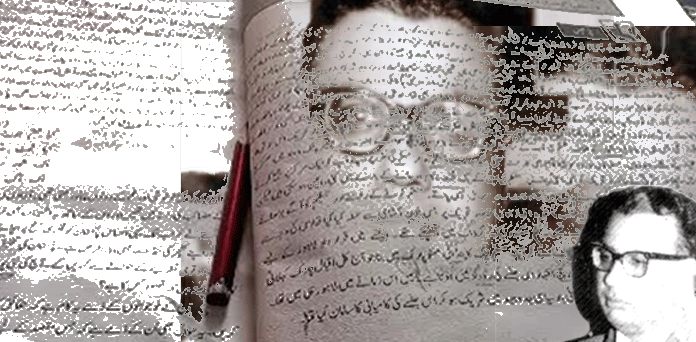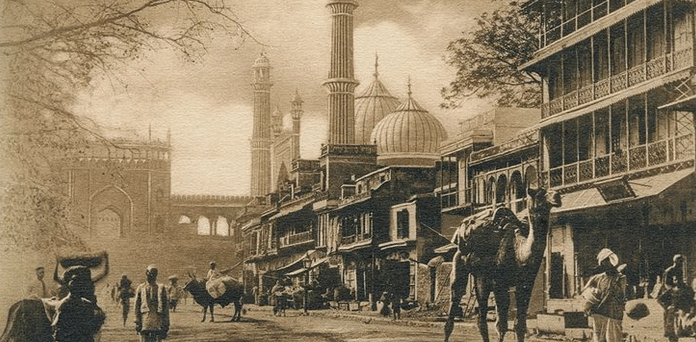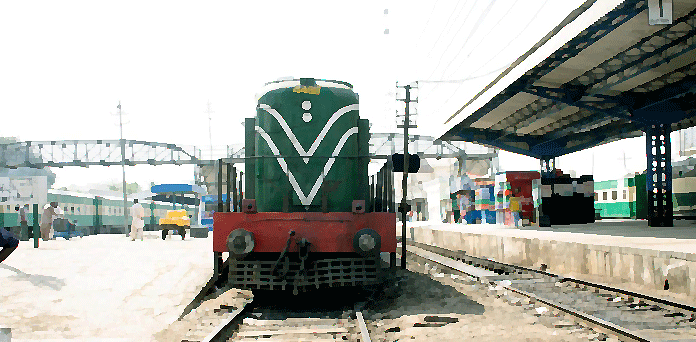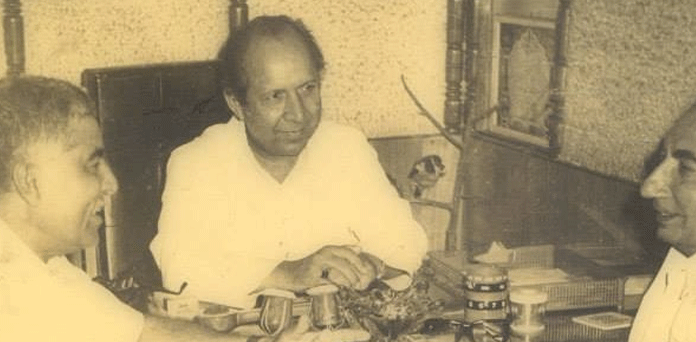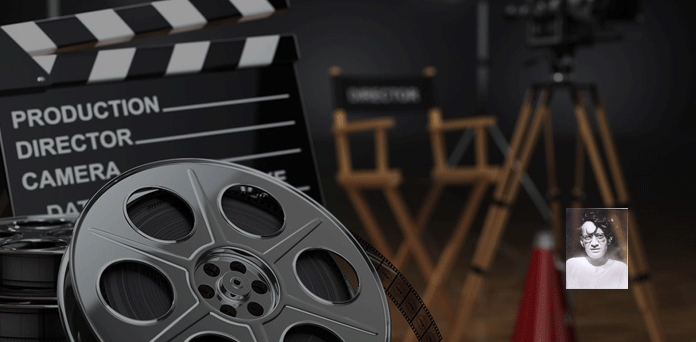فیض صاحب کی شخصیت آہستہ آہستہ پاکستانی ادب اور تہذیب و ثقافت کا امتیازی نشان بنتی چلی گئی۔ انہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری، اسی لیے ایک شاعر کی حیثیت سے، ایک نثر نگار کی حیثیت سے، ایک صحافی کی حیثیت سے، ایک تجزیہ نگار کی حیثیت سے، ایک ڈاکیومنٹری اور فلم پروڈیوسر کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے، ایک دانشور کی حیثیت سے، ایک ثقافتی کارکن اور مفکر کی حیثیت سے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک انسان کی حیثیت سے انہوں نے اپنے عہد پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔
فیض صاحب کی بہ حیثیت صحافی، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے بارے میں ان کے ایک رفیقِ کار اور پاکستان میں انگریزی صحافت کی ایک اہم شخصیت احمد علی خان نے لکھا:
’’فیض صاحب نے صحافت کے میدان میں اس وقت قدم رکھا جب ملکی صحافت ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ تقسیم سے سال بھر پہلے تک برصغیر پاک و ہند میں جہاں کئی کثیر الاشاعت انگریزی روزنامے کانگریس کے ہم نوا تھے، وہاں صرف تین قابلِ ذکر انگریزی روزنامے تحریک پاکستان کے حامی تھے۔ ڈان، دہلی سے نکلتا تھا جب کہ اسٹار آف انڈیا اور مارننگ نیوز کلکتے سے نکلتے تھے۔ ان دنوں اس علاقے میں جو اب مغربی پاکستان (اور اب صرف پاکستان) کہلاتا ہے انگریزی کے چار قابل ذکر روزنامے تھے۔ ٹریبیون اور سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور سے شائع ہوتے تھے جب کہ سندھ آبزرور اور ڈیلی گزٹ کراچی سے نکلتے تھے۔ یہ چاروں اخبار غیر مسلموں کے ہاتھوں میں تھے اور ان میں سے کوئی بھی تحریک پاکستان کا حامی نہ تھا۔ 1947ء میں جب میاں افتخار الدین مرحوم نے پاکستان ٹائمز کی بنیاد ڈالی تو گویا دو کام بیک وقت انجام دیے۔ ایک تو تحریک پاکستان کو جو نہایت نازک موڑ پر پہنچ چکی تھی تقویت پہنچائی اور دوسرے نوزائیدہ مملکت کی آئندہ صحافت کی سمت اور معیار کا نشان بھی دیا۔ لفظ پاکستان کے شیدائی پہلے تو اس کے نام ہی پر جھوم اٹھے اور پھر بہت جلد اس اخبار کے صحافتی معیار اور اس کے پر وقار اور متین انداز سے متاثر ہونے لگے۔
فیض صاحب نے جب اس کی ادارت کا بوجھ سنبھالا تو وہ اس ذمہ داری کے لیے نئے تھے لیکن ان میں اس کام کی بنیادی صلاحیتیں موجود تھیں۔ علمی لیاقت، سیاسی ادراک، تاریخ کا شعور، معاشرے کے مسائل کا علم، ادب پر گہری نظر، اور اچھی نظر لکھنے (انگریزی اور اردو) کا سلیقہ اور اپنی ان تمام صلاحیتوں سے انہوں نے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ ان کے اداریے اپنی سلاست، شگفتگی اور ادبیت کے باعث ابتداء ہی سے مقبول ہوئے۔ ملک کے سیاسی مسائل پر فیض صاحب کے اداریے وسیع حلقے میں پڑھے اور پسند کیے جاتے تھے۔ ‘‘
فیض صاحب کاتا اور لے دوڑے کے راستے پر چلنے کے قائل نہیں تھے۔ شاعری ہو نوکری ہو خطابت ہو یا صحافت ہو غرض یہ کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر وہ جلد باز نہیں رہے۔ ایک طرح سے تکمیلیت پسند شخصیت کے مالک تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ان کے بیش تر کام ادھورے رہ گئے۔ لیکن اخبار کا معاملہ مختلف ہے اس میں سر پر روزانہ ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ آج کا کام آج ہی ہونا چاہیے ورنہ تو اخبار کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ ان سب ترجیحات کے باوجود یہاں بھی انہوں نے اپنے ہی انداز میں کام نمٹایا۔ ان کے دوست حمید اختر کہتے ہیں: ’’وہ اپنے اداریے بالعموم شام کی محفلوں کے اختتام پر، پریس میں کمپوزیٹروں کے برابر بیٹھ کر لکھتے تھے۔ موضوع کا انتخاب تو ہمیشہ صبح کو ہی ہو جاتا تھا لیکن پریس والوں کو اداریہ رات کے دس گیارہ بجے سے قبل کبھی نہیں ملتا تھا۔ پاکستان ٹائمز کے عملے کا خیال تھا کہ وہ کام کو آخری وقت تک ٹالتے رہتے ہیں اور جب فرار کے تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں اس وقت اس بوجھ کو اتارتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ رائے درست نہیں اصل میں وہ دن بھر اپنے موضوع کے متعلق سوچتے رہتے تھے اور اس دوران غائب دماغی کے مظاہرے بھی کرتے رہتے تھے۔ دن بھر یا شام کو ملنے والے یا محفل میں ساتھ بیٹھنے والے انہیں غیر حاضر پاتے تو شاعر سمجھ کر معاف کر دیتے۔ جب کہ حقیقتاً وہ آخری وقت تک اپنے اداریے کے متعلق سوچتے رہتے تھے اور اس کے بعد لکھتے تھے۔‘‘
سبط حسن نے بھی جو کہ صحافت کی دنیا میں ان کے ساتھ تھے فیض صاحب کی صحافتی خدمات کے حوالے سے لکھا ہے: ’’فیض صاحب نے دس گیارہ سال اخبار نویسی کی۔ پاکستان کی صحافت کی تاریخ میں ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے اخبار نویسی بڑے آن بان سے کی۔ انہوں نے اپنے ضمیر کے خلاف کبھی ایک حرف نہیں لکھا بلکہ امن، آزادی اور جمہوریت کی ہمیشہ حمایت کی، اقتدار کی جانب سے شہری آزادیوں پر جب کبھی حملہ ہوا تو فیض صاحب نے بے دھڑک اس کی مذمت کی اور جس حلقے، گروہ، جماعت یا فرد سے بے انصافی کی گئی انہوں نے اس کی وکالت کی۔ فیض صاحب کے اداریے اپنی حق گوئی کی ہی بدولت مقبول نہ تھے بلکہ وہ نہایت دلچسپ ادبی شہ پارے بھی ہوتے تھے جن کو دوست اور دشمن سب لطف لے لے کر پڑھتے تھے۔ ‘‘
اس کا ایک سبب ان کی واضح سیاسی سوچ اور مسئلے کو اس کی اصل گہرائی تک جا کر دیکھنے کی صلاحیت تھی۔
(ماخوذ از مقالہ بعنوان فیض احمد فیض…. شخصیت اور فن، مصنّفہ اشفاق حسین)