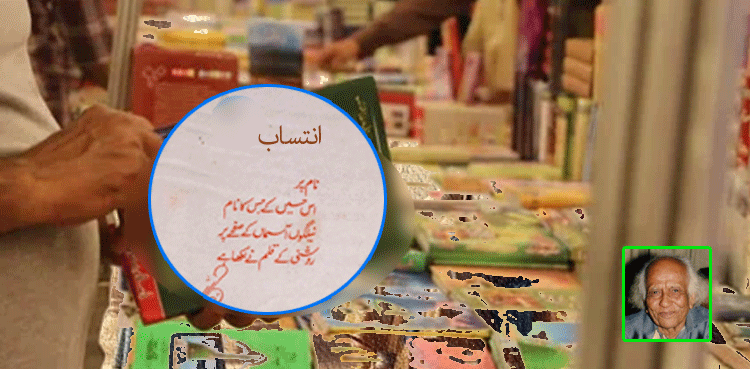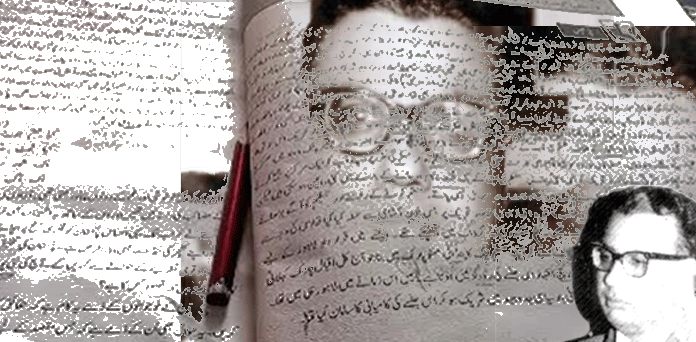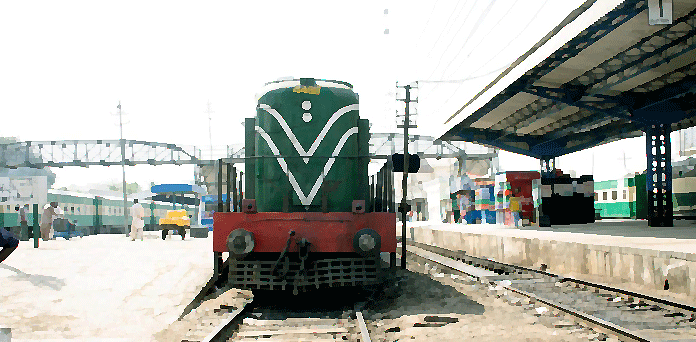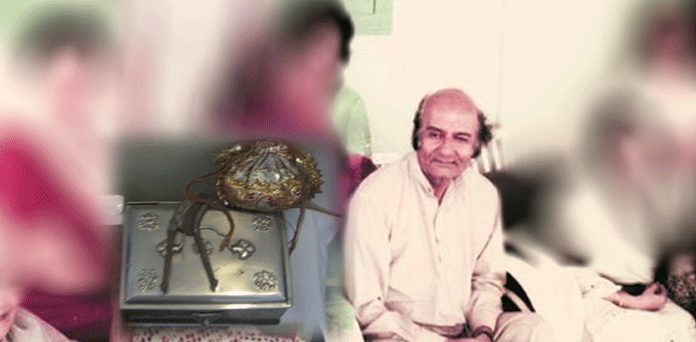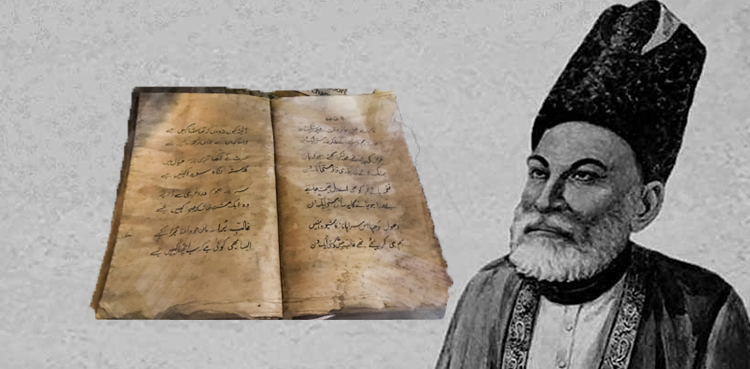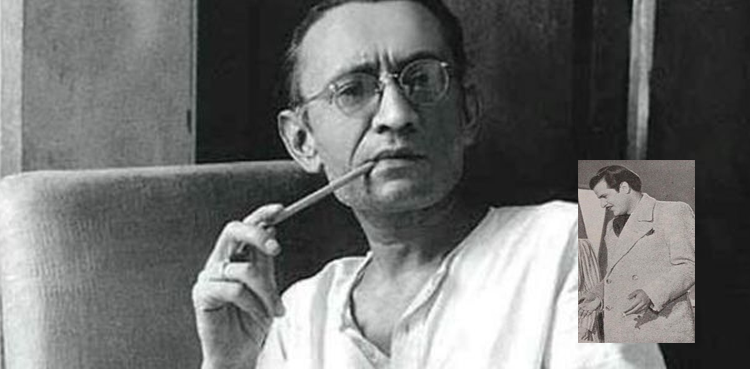ادب میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی نوعیت غیر قانونی نہ سہی، مشتبہ ضرور ہے۔ انھیں میں سے ایک انتساب ہے۔
انتساب نہ تو کوئی صنفِ ادب ہے نہ ادب کی کوئی شاخ (شاخسانہ ضرور ہے۔) اردو میں انتساب کو آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ یہ دورِ مغلیہ کے بعد کی چیز معلوم ہوتی ہے۔ بہت زیادہ قدیم ہوتی تو اب تک متروک ہو جاتی۔ متروک نہ ہوتی تو مکروہات میں ضرور شمار ہونے لگتی۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ جنہوں نے اچھے دن دیکھے تھے۔ ان دنوں انتساب نہیں ہوا کرتا تھا۔ لوگ خوشی خوشی کتابیں پڑھا کرتے تھے (اس زمانے میں کتابیں تھیں بھی کم۔) انتساب کی تحریک، پڑھے لکھے لوگوں کی اجازت بلکہ ان کے علم و اطلاع کے بغیر اچانک شروع ہوئی اور جب یہ شروع ہوئی اس وقت کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ آگے چل کر یہ اتنی خطرناک صورت اختیار کرے گی کہ صرف انتساب کی خاطر کتابیں لکھی جانے لگیں گی اور ان کے شائع کیے جانے کے لیے متعلقہ لوگ جان کی بازی لگا دیں گے۔
انتساب کو ادب میں اب وہی مقام حاصل ہے جو سترھویں صدی میں شہنشاہ اکبر کے دربار میں بیربل اور راجا ٹوڈر مل کو حاصل تھا۔ بیربل اور ٹوڈر مل کے فرائضِ منصبی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے اور مزاجاً بھی ان دونوں میں کوئی چیز مشترک نہیں تھی۔ اسی لیے ان دونوں کا نام ایک ساتھ لیا گیا۔ انتساب بھی اپنے صفات کے اعتبار سے اتنے ہی مختلف اور متضاد ہوتے ہیں۔
ادب کے نصاب میں انتساب اگرچہ اختیاری مضمون ہے لیکن بے انتساب کتاب اس موسیقار کی طرح ہوتی ہے جو سُر میں نہ ہو۔ آج بھی اکثر کتابیں یوں ہی چھپ جاتی ہیں۔ یوں ہی سے مراد ایسی جن میں صفحۂ انتساب نہیں ہوتا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی۔ صفحۂ انتساب موجود نہ ہو تو قاری کے ذہن میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ مصنف میں قوتِ فیصلہ کا فقدان ہے۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ اپنی تصنیفِ لطیف کو کسی کے نام معنون نہ کر کے مصنف نے کسی کا حق غصب کیا ہے لیکن اسے تساہل تو کہا ہی جاسکتا ہے۔ ایک ادیب میں قوتِ فیصلہ ہونی ہی چاہئے۔ بہت سے ادیب تو اپنے انتسابوں کی وجہ سے پہچانے جاتے اور ترقی کرتے ہیں۔ (انتساب کا کچھ نہ کچھ نتیجہ تو نکلتا ہی ہے) مشکل یہ بھی ہو گئی ہے کہ اگرکتاب میں صفحۂ انتساب نہ ہو تو اسے بداخلاقی بلکہ بدنیتی سمجھا جانے لگا ہے۔ (مری تعمیر میں مضمر ہے اک صورت خرابی کی)
انتساب ہر کسی کے استعمال کی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے ذرا ترقی کرنی پڑتی ہے۔ مضمون، افسانے، غزل یا رباعی کا انتساب نہیں ہوا کرتا۔ تہنیتی اور تعزیتی قطعات جن کے آخری مصرعے سے کسی واقعے یا سانحے کی تاریخ نکلتی ہو (صحیح یا غلط)، انتساب کی تعریف میں نہیں آتے۔ خود قصیدہ بھی جو کافی طویل اور سوائے ممدوح کے دوسروں کے لیے صبرآزما ہوتا ہے۔
انتساب تو ایک نازک چیز ہوتی ہے اور اہم بھی۔ اس کے لیے پوری ایک کتاب لکھنی پڑتی ہے۔ اس میں ضخامت کی کوئی قید نہیں۔ اگر وہ کتاب نہیں صرف کتابچہ ہے تب بھی اس کا انتساب جائز ہے۔ صندوق اور صندوقچے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ بلکہ صندوقچہ زیادہ قیمتی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
انتساب اور نذرمیں بڑا فرق ہے۔ نذر بظاہر انتساب سے ملتی جلتی چیز معلوم ہوتی ہے لیکن اسے زیادہ سے زیادہ انتساب کی طرف پہلا قدم سمجھا جا سکتا ہے۔ کچھ شاعر اپنی ایک مختصر سی غزل جس میں پورے 7 شعر بھی نہیں ہوتے۔ کسی پرچے میں چھپواتے وقت اسے اپنے سے ایک سینئر شاعر کے نام نذر کردیتے ہیں، یہ نجی طور پر تو جائز ہے، لیکن اس کی ادبی حیثیت صفر سے بھی کچھ کم ہوتی ہے۔ شاعر تو مشاعروں میں اپنا کلام سنانے کے دوران بھی اپنے اشعار(ظاہر ہے انھیں کے ہوتے ہوں گے) مختلف سامعین (جنھیں وہ اپنی دانست میں معززین سمجھتے ہیں) کی نذر کرتے رہتے ہیں اور کسی دوسرے مشاعرے میں وہی نذر شدہ اشعار بانیانِ مشاعرہ میں سے کسی اور کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسے انتساب سے کیا تعلق ہوسکتا ہے۔ اسے نذر کہنا بھی خوش اخلاقی ہے۔ یہ صرف ایک عادت ہے جو مصالحِ انتظامی کی بنا پر اختیار کی جاتی ہے اور یہ رفتہ رفتہ اتنی جڑ پکڑ لیتی ہے کہ شاعر سے صرف اسی وقت چھوٹتی ہے جب اس کا مشاعروں میں آنا جانا موقوف ہوجاتا ہے۔
اس کے برخلاف انتساب یوں جگہ جگہ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی ایک مستقل اور دائم حیثیت ہے، یعنی اگر اتفاق سے (جسے حسنِ اتفاق نہیں کہا جاسکتا) کسی کتاب کے دوسرے ایڈیشن کے چھپنے کی نوبت آئے تو اس ایڈیشن میں بھی، سابقہ انتساب حسبِ حال برقرار رہے گا۔ چاہے ممدوح کی وفات ہی کیوں نہ واقع ہو چکی ہو۔ اپنا بیان مع اندازِ بیان اور اپنا کلام مع زورِ کلام کسی حد تک واپس لیا جاسکتا ہے لیکن ایک مرتبہ کے کیے ہوئے انتساب پر ہاتھ نہیں ڈالا جاسکتا، یہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح ہوتا ہے۔
انتساب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ جتنی تصنیفات اتنی ہی قسمیں، لیکن سہولت کی خاطر انھیں چند قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ تقسیم کا عمل ان دنوں بہت ضروری ہے اور اسے مجلسِ اقوام متحدہ کی تائید حاصل ہے۔
انتساب کی موٹی موٹی قسمیں یہ ہیں۔
حروف تہجی کے نام
اس انتساب میں قارئین کو پتا نہیں چلتا کہ اس تصنیف کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ اس کا فیض مصنف اور ممدوح کی حد تک محدود رہتا ہے۔ ان دونوں کے قریبی دوستوں اور چند مخصوص سہیلیوں کو البتہ اس بات کی اطلاع ہوتی ہے کہ اس حروف تہجی کے پردہ نگاری کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے۔ یہ بات آہستہ آہستہ کوٹھوں چڑھتی ہے۔ (اب تو لفٹ کی بھی سہولت موجود ہے۔)
ایسی کوئی کتاب جس کا انتساب حرف الف کے نام کیا گیا ہو ہماری نظر سے نہیں گزری، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ضرور۔ ’ب‘ کا انتساب ہم نے ضرور دیکھا ہے۔ غالباً یہ کوئی مجموعۂ کلام تھا۔ اسی طرح سب تو نہیں لیکن کئی حروف تہجی انتساب میں کارآمد ثابت ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر سلام بن رزاق کی کتاب ’ع‘ کے نام ہے۔ اب یہ ’ع‘ ظاہر ہے عبدالسلام یا عبیداللہ نہیں ہوسکتے۔ ان دونوں میں سے کوئی ہوتے تو علی الاعلان سامنے آتے۔ حروف تہجی کے انتساب ہمیں بہرحال پسند ہیں۔ ہندستان میں تھوڑا بہت پردہ ابھی باقی ہے۔
بے نام کے انتساب
اس قسم کے انتساب بھی مقبول ہیں اور ان میں مصنف ذرا سی محنت کرے تو بڑی نزاکتیں پیدا کر سکتا ہے۔ اکثر مصنفین اس میں بہت کامیاب ہوئے ہیں۔ بشر نواز نے جب اپنا مجموعۂ کلام ’رائیگاں‘ شائع کیا تو اس کا انتساب اس طرح کیا، ’’نام پر اس حسین کے، جس کا نام نیلگوں آسمان کے صفحے پر روشنی کے قلم نے لکھا ہے۔ ’’
یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ یہ انتساب رائیگاں نہیں کیا ہوگا۔
بے نام کے انتساب کا اشارہ کئی لوگوں کی طرف بھی ہوسکتا ہے جن کی شناخت ایک مسئلہ بن سکتی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے جب اپنی کتاب ’نئے افسانہ نگاروں کے نام‘ معنون کی تو کئی افسانہ نگار جو کافی پرانے تھے اس انتساب کی خاطر نئے بن گئے (حالانکہ ادب میں دل بدلی ہوتی نہیں ہے) ایک نوجوان نے تو ہر کسی سے پوچھنا شروع کردیا کہ کیا آپ نے فاروقی صاحب کی وہ کتاب ’افسانے کی حمایت میں‘ پڑھی ہے جس کا انتساب میرے نام ہے۔ ایک اور نوجوان چار قدم اور آگے نکل گئے اور فرمایا کہ اب جب کہ میرے نام یہ کتاب معنون ہی کردی گئی ہے تو میں بھی افسانے لکھنے پر مجبور ہوگیا ہوں۔ کسی دن لکھ ڈالوں گا کیوں کہ پلاٹ کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔
اسی طرح بلراج کو مل نے اپنی ’نژاد سنگ‘ بچھڑے ہوئے دوستوں کے نام معنون کی ہے اور آج کل بچھڑے ہوئے دوستوں کی تعداد ’جاریہ‘ دوستوں سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ شناخت دونوں کی مشکل ہے۔ یوں بھی اب دوست ایک ہی جگہ رہتے ہیں لیکن بچھڑے رہتے ہیں۔ یہ خاموش ادبی معرکہ ہوتا ہے۔
غلام ربانی تاباں نے ’ذوقِ سفر‘ کا انتساب اس طرح کیا ہے، ’’میرے وہ دوست جنھیں میری شاعری پسند ہے اب اس بوجھ کو سنبھالیں۔ انھیں کے نام یہ کتاب معنون کرتا ہوں۔‘‘ اس انتساب میں بھی شناخت مشکل ہے۔ کوئی آگے بڑھ کر نہیں کہتا کہ یہ کتاب میرے نام ہے۔
انگریزی کی ایک کتاب کا انتساب البتہ کچھ اس طرح کا تھا، ’’اپنی بیوی کے نام جو اس کتاب کی اشاعت میں اگر میرا ہاتھ نہ بٹاتیں تو یہ کتاب آج سے 5 سال پہلے چھپ جاتی۔‘‘
(اردو کے ممتاز ادیب اور مشہور طنز و مزاح نگار یوسف ناظم کے مضمون سے شگفتہ پارے)