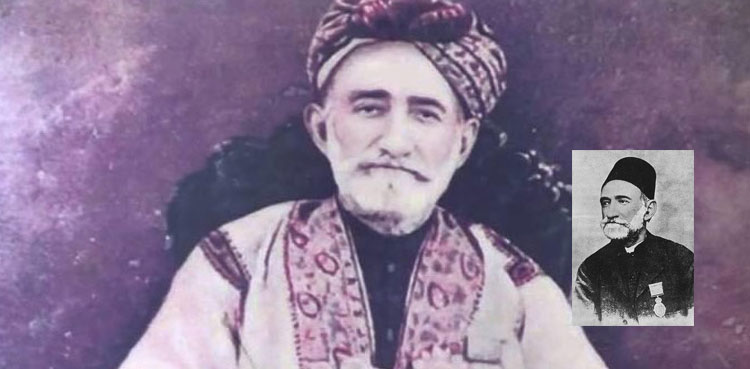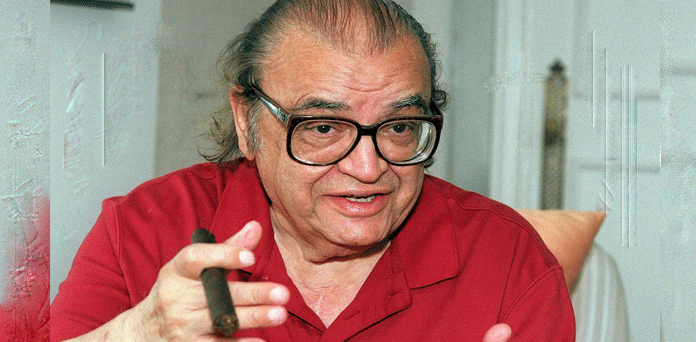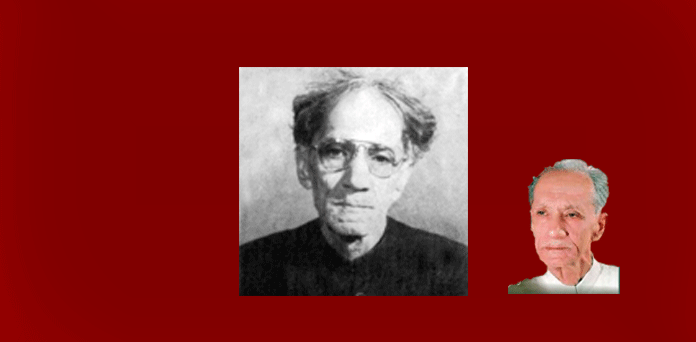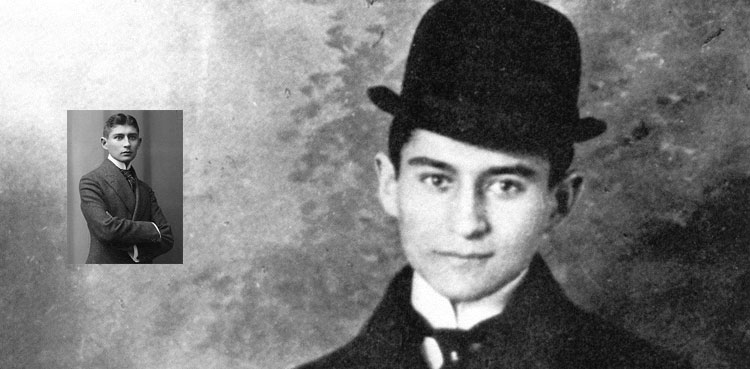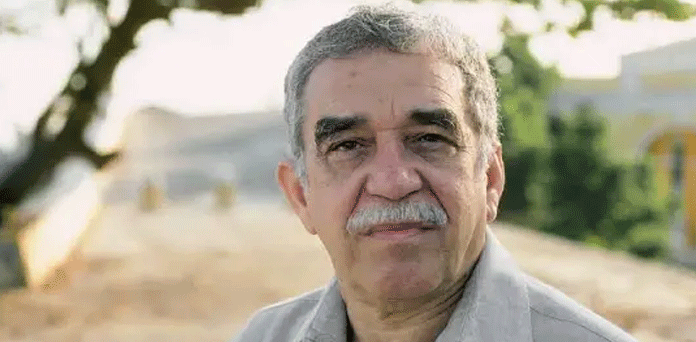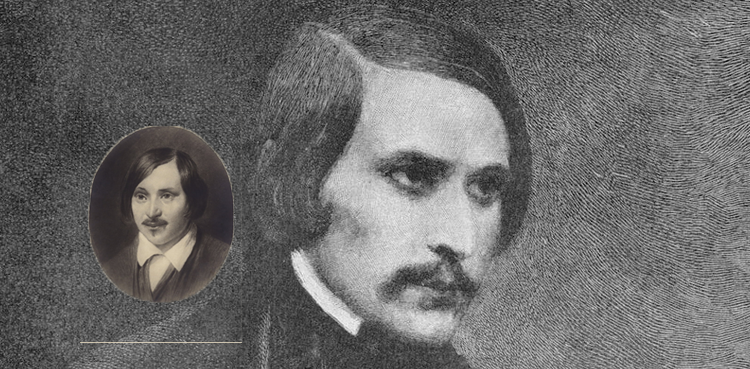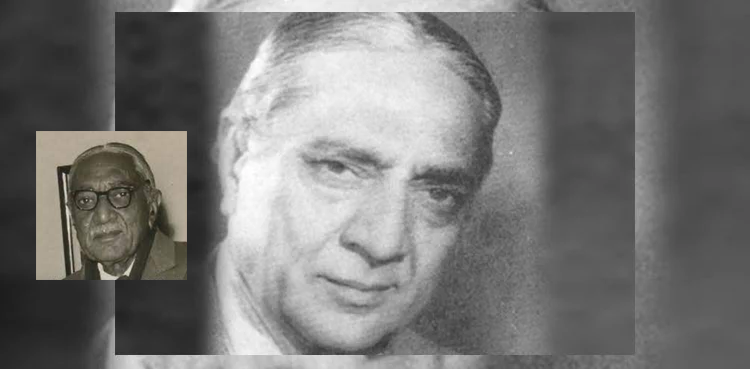یہ ستّر کی دہائی تھی جب مسعود اشعر نے اپنی کہانیوں سے ادبی دنیا میں پہچان بنائی۔ انھوں نے اپنے قارئین کے سامنے انسانی رشتوں کی الجھنیں، سماج اور لوگوں کے درمیان تعلقات کی پیچیدگیوں کو اپنے کرداروں اور مناظر کے ساتھ مؤثر انداز میں پیش کیا۔
مسعود اشعر کو افسانہ نگار، مترجم اور صحافی کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ انھیں حکومتِ پاکستان کی جانب سے تمغائے حسنِ کارکردگی اور ستارۂ امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ 5 جولائی 2021ء کو مسعود اشعر انتقال کرگئے تھے۔ آج ان کی برسی ہے۔
تقسیمِ ہند کا اعلان ہوا، تب وہ نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ انھیں رام پور چھوڑنا پڑا۔ وہ ہجرت کر کے پاکستان کے شہر ملتان چلے آئے اور پھر لاہور کو اپنا مستقر بنایا۔1930ء میں پیدا ہونے والے مسعود اشعر کا اصل نام مسعود احمد خان تھا۔ پاکستان میں انھوں نے علمی صحافت کا آغاز کیا اور تخلیقی کاموں کے ساتھ ادبی سرگرمیوں میں حصّہ لینے لگے۔ لاہور اور ملتان میں انھوں نے روزنامہ احسان، زمین دار، آثار اور امروز میں کام کیا۔ وہ ایک معروف علمی ادارے کے سربراہ بھی رہے۔ کالم نگاری بھی مسعود اشعر کا ایک حوالہ ہے۔ وہ روزنامہ جنگ کے لیے ہفتہ وار کالم لکھتے تھے۔ شمیم حنفی نے مسعود اشعر کے بارے میں لکھا ہے، "ان میں ایک بھری پری دنیا آباد دکھائی دیتی ہے۔ مذہب، سیاست، ادب، آرٹ، علوم، ہم جیسے عام انسانوں کی زندگی کے ہر زاویے کو وہ ایک سی ہمدردی، سچائی، اور دل چسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اور کیا خوب دکھاتے ہیں۔ کہیں کسی طرح کی بدمذاقی نہیں، بے جا طنز اور برہمی نہیں۔ مبالغہ نہیں، مصلحانہ جوش و خروش نہیں۔ مسعود اشعر کی شخصیت، اپنی سادگی کے باوجود بہت پرکشش ہے۔ ماہ سال کی گرد نے بھی اس کی آب و تاب میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ لہٰذا اپنی سادگی میں بھی آراستہ نظر آتے ہیں۔ نکھرے اور سنورے ہوئے۔ یہی حال ان کے کالموں کا ہے۔ بہ ظاہر سیدھی سادی، شفاف نثر لکھتے ہیں۔ کہیں بیان کی پینترے بازی نہیں۔ ابہام اور تصنع نہیں۔ سجاوٹ اور تکلف نہیں۔ مگر جب بھی جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، کہہ جاتے ہیں۔ معاملہ ارباب اقتدار کا ہو، یا ادیبوں، عالموں اور عام انسانوں کا۔ مسعود اشعر سب کو ایک سی توجہ اور بے لوثی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ صحافتی احتیاط کے ساتھ ساتھ ان کی طبیعت میں تہ داری کا اور زندگی کے ہر عمل، ہر شعبے کی اخلاقی جہت کے وجود کا احساس بھی نمایاں ہے۔ صحافت کی دنیا کے طویل تجربے اور اپنی فطرت کے تقاضوں سے مر بوط، یہی انداز و اوصاف مسعود اشعر کے افسانوں اور ان کی نثر میں بھی نظر آ تے ہیں۔”
مسعود اشعر نے صحافت کی دنیا میں ہمیشہ حق گوئی اور جرأت سے کام لیا۔ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کی آمریت کا زمانہ تھا اور مسعود اشعر امروز ملتان کے ایڈیٹر تھے۔ انہی دنوں کالونی ٹیکسٹائل ملز میں مزدوروں پر گولی چلائی گئی اور یہ فرمان بھی جاری ہوا کہ اس سانحے کی خبر نہ بنائی جائے۔ مسعود اشعر اس کے لیے تیّار نہ ہوئے۔ اخبار میں خبر چھپی تو ان کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ فتح محمد ملک نے لکھا ہے کہ مسعود اشعر بے روزگار رہے اور جیل کاٹی مگر آزادیٔ صحافت پر سمجھوتہ نہیں کیا۔
مسعود اشعر کے افسانے ’’آنکھوں پر دونوں ہاتھ‘‘ کی صورت میں شایع ہونے کے بعد جو کتابیں منظرِ عام پر آئیں ان میں متنوع موضوعات پر مسعود اشعر نے اپنے تخلیقی وفور کا اظہار کیا ہے۔ ایک کتاب ’’سارے افسانے‘‘ اور دوسری ’’اپنا گھر‘‘ کے عنوان سے اور چند برس قبل ’’سوال کہانی‘‘ کے نام سے شایع ہوئی تھی۔