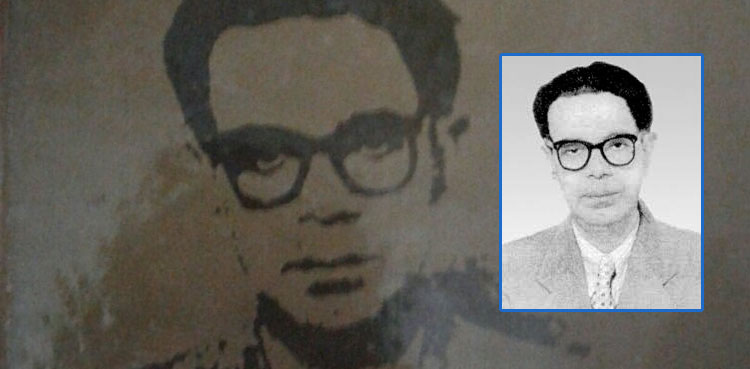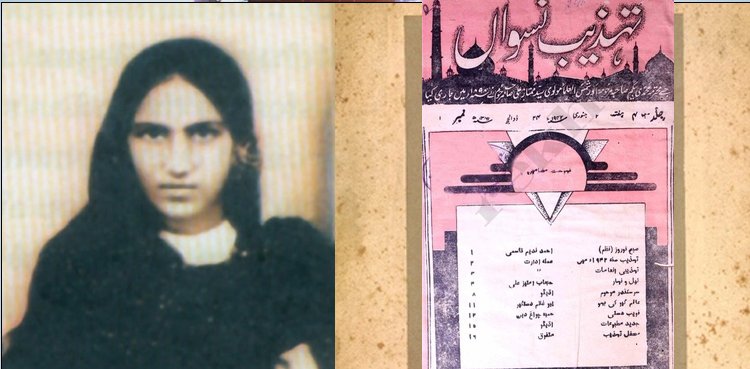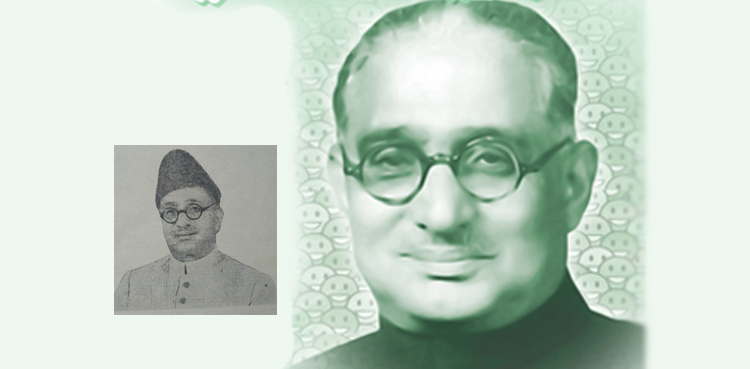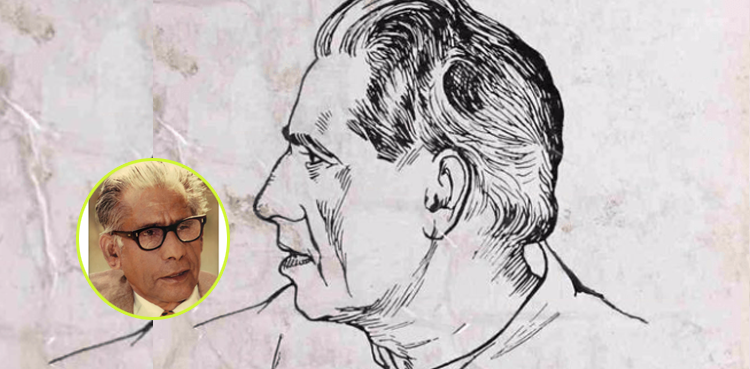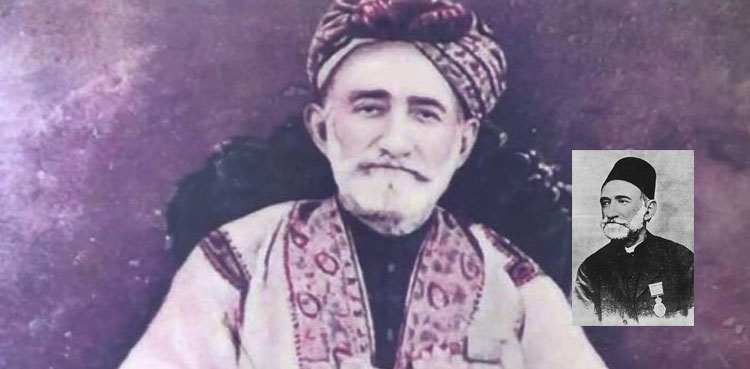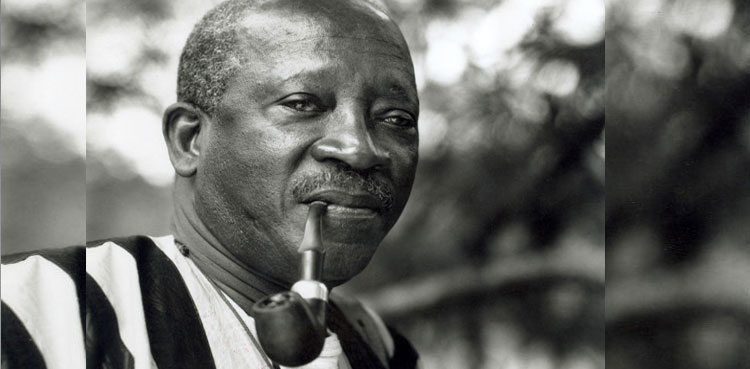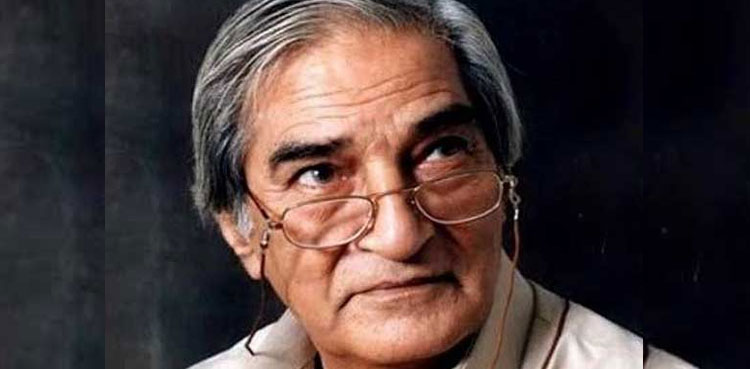نوبیل انعام یافتہ امریکی ناول نگار سال بیلو کا قلم سے رشتہ اور تخلیقی سفر تقریباً پانچ دہائیوں پر محیط رہا۔ وہ 2005ء میں آج ہی کے دن چل بسے تھے۔
اس امریکی ناول نگار کو جنگِ عظیم کے بعد کا دانش وَر بھی کہا جاتا ہے جس کی وجہ ان کے مخصوص فکر کے حامل کردار تھے۔ سال بیلو نے کہا تھا ’میں جو دیکھتا ہوں، اس سے تجاوز نہیں کر سکتا، دوسرے لفظوں میں، مَیں اُس تاریخ نویس کی مانند ہوں جو اُس خاص عہد کا پابند ہے جس کے بارے میں وہ لکھ رہا ہے۔‘ لیکن سال بیلو کی تاریخ نویسی ذاتی اور مخصوص نوعیت کی تھی۔ یہ دراصل ان کی یہودی شناخت اور اس سے جڑے ہوئے مسائل تھے جس کو انھوں نے کرداروں کی صورت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔
انھیں 1976ء میں نوبیل انعام سے نوازا گیا اور تسلیم کیا گیا کہ ان کی تخلیقات میں تنوع ہے۔ سال بیلو کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے کردار بڑے جان دار تھے۔ انہی کرداروں کے بَل پر مصنّف نے اپنی کہانیوں کو خوبی سے پھیلایا اور خاص تھیم پر لکھا۔ اس کی مثال ان کے ناول ’آگی مارچ کی مہمات‘ (1953)، ’ہینڈرسن دی رین کنگ‘ ( 1959) اور ’ہرزوگ‘ (1964) ہیں۔ ادب کے ناقدین کردار نگاری ہی کو ان کی تخلیقات کا نمایاں وصف قرار دیتے ہیں۔ اس میں ہرزوگ کو خاص مقام حاصل ہے۔ ہرزوگ دراصل ایک دانش ور کردار ہے جس کے ذریعے بیلو نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ اس ’ہی مین‘ والے عہد میں ایک دانش ور گویا وہ نامرد ہے جو صرف سوچتا رہتا ہے اور کچھ نہیں کرسکتا۔ بیلو کے بیشتر کردار دانش وروں کے اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن میں ایک خاص قسم کا مزاح بھی ہے۔
مرزا اے بی بیگ نے سال بیلو کی وفات پر اپنی تحریر میں لکھا تھا کہ ناقدین کی بڑی تعداد بیلو کے ناولوں کو مختلف پیرائے، بیانیہ اور مابعد جدیدیت کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتی رہی ہے، لیکن ایڈورڈ سعید اور چومسکی جیسی قد آور شخصیات نے بیلو کے فکشن اور غیر فکشن میں ان کے سیاسی نظریے کو کھول کر رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیلو مشرق وسطی کے مسئلے پر کسی حد تک صیہونیت کے حامی اور علم بردار ہیں۔
ایک زمانے تک سال بیلو نے خود کو ’یہودی-امریکی ادیب‘ کے لیبل سے آزاد اور الگ رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ تاہم یہ اب ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ان کے ناولوں میں یہودیت ایک عام بحث کا موضوع ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سال بیلو کی تحریریں یہودی اساطیر میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ امریکا میں یہودی شناخت ان کا مسئلہ رہا۔ اسی وابستگی کے پس منظر میں معاشرہ اور انسان ان کی تخلیقات پر حاوی نظر آتا ہے، لیکن جب دنیا بھر کے ادیب اور دانش ور اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے تو سال بیلو اس سے دور رہے۔ اسی طرح وہ اپنے انٹرویوز اور گفتگو میں بھی اس بابت اپنا نقطۂ نظر واضح کرنے سے گریز کرتے رہے۔
بیلو نے 1915ء میں مانٹریال کے مشہور علاقے کیوبک میں آنکھ کھولی تھی۔ 1924 میں ان کا خاندان شکاگو منتقل ہو گیا۔ وہ 17 سال کے تھے جب والدہ کی شفقت سے محروم ہوگئے۔ 1933 میں سال بیلو نے شکاگو یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور پھر ایک اور سستی جگہ پر منتقل ہوکر وہاں درس گاہ میں داخل ہوئے۔ انھوں نے وسکونسن یونیورسٹی میں گریجویشن ادھوری چھوڑ دی تھی۔
اس امریکی ناول نگار کی پہلی تصنیف ’ڈینجلنگ مین‘ ہے جسے انھوں نے 1944 میں شائع کروایا تھا۔ سنہ 2000ء میں سال بیلو کی آخری تصنیف ’ریولسٹائن‘ کے عنوان سے منظرِ عام پر آئی تھی۔ بیسویں صدی کے انگریزی کے اس اہم ناول نگار کو ادب کے کئی معتبر ایوارڈز اور انعامات سے نوازا گیا جن میں فکشن کا پلٹزر پرائز بھی شامل ہے جب کہ مین بکر انٹرنیشنل پرائز کے لیے بھی ان کا نام فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔