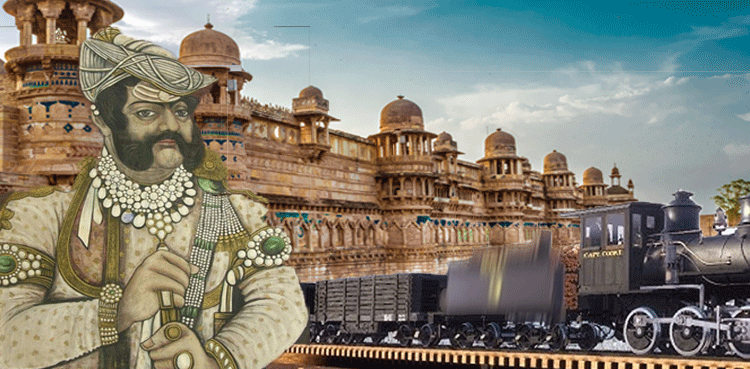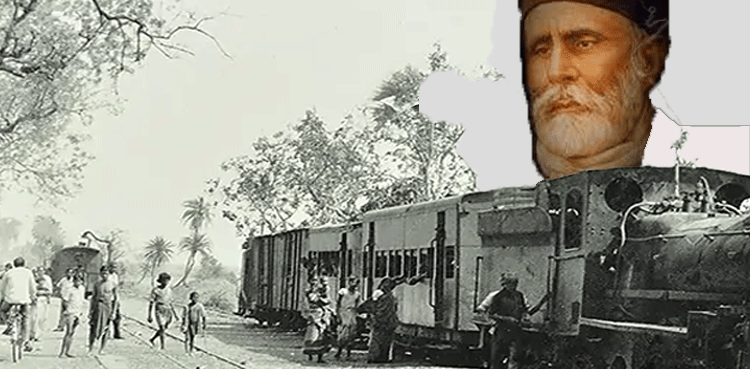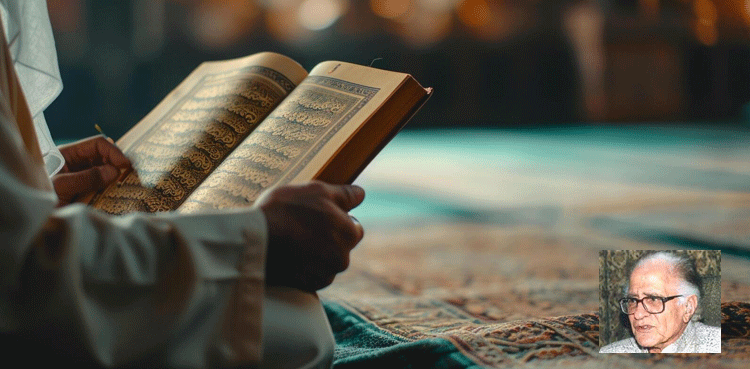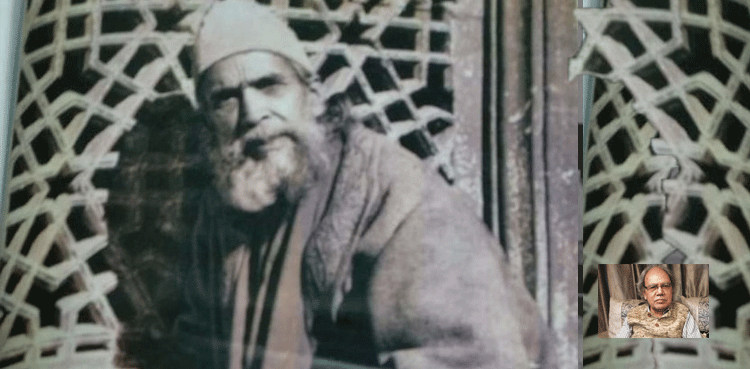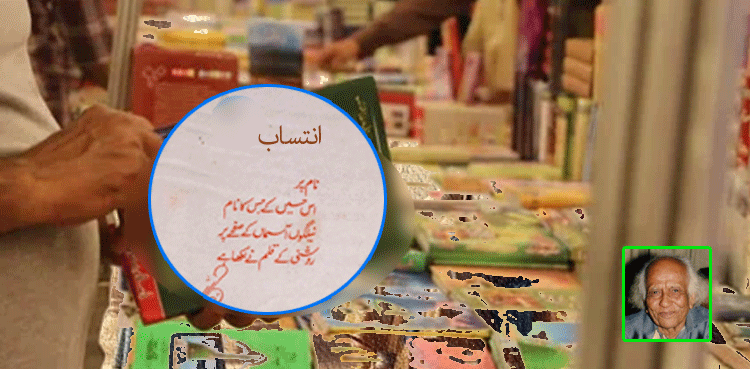مولانا حالی جب اینگلو عربک اسکول دہلی میں فرسٹ اورینٹل ٹیچر تھے تو موسمی تعطیلات میں جو اس وقت ایک مہینے کی ہوا کرتی تھیں، انہوں نے خاص طور پر ایک تفریحی سفر ریاست الور کا کیا تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ تفریح کے لئے خاص الور ہی کو مولانا نے کیوں منتخب کیا۔
بہرحال اس سفر میں وہ علی گڑھ، فیروز آباد، اٹاوہ، مین پوری، کان پور، ہمیر پور اور باندی کوٹی ہوتے ہوئے الور پہنچے۔ علی گڑھ میں سرسید کے مہمان رہے اور علی گڑھ کالج دیکھنے کا ان کا یہ تیسرا موقع تھا۔ اس کا حال بیان کرتے ہوئے مولانا کے ایک ایک لفظ سے اس محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہے جو مولانا کو علی گڑھ اور سرسید کی ذات سے تھی۔ راستے میں مولانا جن جن مقامات سے گزرے، ان کی مختصر کیفیت بیان کی ہے۔ (محمد اسماعیل)
سفر کا مختصر احوال
ایام تعطیل میں دوستوں اور عزیزوں سے ملنے کی غرض سے ہم کو چند مقامات میں دورہ کرنے کا اتفاق ہوا اور ہم دہلی سے علی گڑھ پہنچے اور جناب آنریبل سید احمد خاں بہادر کی کوٹھی پر ٹھہرے۔
علی گڑھ
اب کی دفعہ ہم نے مدرسۃ العلوم کو تیسری بار دیکھا اور اس کی روز افزوں ترقی دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ مدرسے کو دیکھ کر ہم کو اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ اولوالعزم اور مستقل مزاج آدمی اپنے ارادوں کی مزاحمت سے اور زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے سوا جو عناد اور دشمنی سے اس مدرسے کے مخالف ہیں، باقی سب مسلمان رفتہ رفتہ اس کی قدر کرتے جاتے ہیں اور جن عمدہ اصول پر اس مدرسے کی بنیاد قائم کی گئی ہے، اب ان کی خوبی و عمدگی سب سے پر ظاہر ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے طلبہ کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ بہت سے بے خبر اور ناواقف لوگ جو اپنی اولاد کو یہاں بھیجتے ہوئے جھجکتے تھے اور ان کے مذہب و عقائد کے بدل جانے سے ڈرتے تھے، وہ اب نہایت اطمینان اور دلجمعی سے اپنی اولاد کو وہاں بھیجنے لگے ہیں۔
یہ بات تحقیق ہو گئی ہے کہ بانی مدرسۃ العلوم کے مذہبی اعتقادات اور رایوں کو مدرسۃ العلوم کی تعلیم میں کچھ بھی دخل نہیں ہے۔ اس امر کا یہاں تک خیال رکھا جاتا ہے کہ رسالہ ’تہذیب الاخلاق‘ جو مطبع علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ سے چھپ کر شائع ہوتا ہے، اس کی کوئی کاپی مفت یا بہ قیمت کسی طالب علم کو نہیں دی جاتی۔ طلبائے مدرسہ کے افعال و اخلاق کی نگرانی پر یہاں وہ لوگ مامور ہیں جو جمہور اہل اسلام کے طریقے سے سرِ مو تجاوز کرنے کو بھی کفر جانتے ہیں۔ علی گڑھ میں ہم بعض ایسے دوستوں سے بھی ملے جو چند سال پہلے اس مدرسے کو ’’دارالکفر‘‘ سمجھتے تھے، لیکن اب حد سے زیادہ اس کے مداح اور ثنا خواں ہیں اور اپنے بچوں کو وہاں تعلیم کے لئے بھیجتے ہیں۔
مدرسے میں دو چار کے سوا، جو کہ مریض تھے، ہم نے سب مسلمان طالب علموں کو روزہ دار پایا۔ افطار کے وقت نماز کے چبوترے پر، جو بالفعل عارضی طور پر بنایا گیا ہے، سب جمع ہوتے تھے اور نہایت لطف کے ساتھ روزہ افطار ہوتا تھا۔ نماز عشا کے بعد جناب مولوی محمد امیر صاحب تراویح میں قرآن سناتے تھے اور اکثر طالب علم ان کا قرآن سنتے تھے۔ ایک روز جناب مولوی سید فرید الدین احمد خاں بہادر نے اور دوسرے روز ہمارے جلیل القدر میزبان (یعنی سید احمد خاں صاحب) نے بھی روزہ افطار کی تقریب میں اپنے دوستوں کو بلایا تھا اور ان دونوں صحبتوں میں ہم بھی شریک تھے۔
مدرسہ العلوم کی تعمیر نہایت شد و مد سے جاری ہے اور جس قدر کام اس میں ہو چکا ہے اور ہورہا ہے، اس کو دیکھ کر بے انتہا تعجب ہوتا ہے۔ مدرسۃ العلوم کے حامیوں اور کار پردازوں کی سرگرمی اور کوشش دیکھ کر ان لوگوں کے دل میں بھی، جو مسلمانوں کی ترقی سے مایوس ہیں، ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے اور یہ امید ہوتی ہے کہ اس قوم کی ترقی کا اگرذمہ دار ہو سکتا ہے تو یہی مدرسہ ہو سکتا ہے۔ علی گڑھ میں پانچ روز ٹھہر کر ہم فیروز آباد، اٹاوہ، مین پوری اور کانپور ہوتے ہوئے ہمیرپور میں پہنچے۔
فیروزآباد
فیروزآباد ضلع آگرہ کا ایک مشہور قصبہ ہے جس میں سرکاری تھانہ اور تحصیل بھی ہے۔ یہ قصبہ جیسا کہ مشہور ہے، فیروز خواجہ سرا کا آباد کیا ہوا ہے، لیکن یہ ایک غیر محقق بات ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ فیروز شاہ کا آباد کیا ہوا ہو، جیسے فیروز پور یا حصار فیروزہ وغیرہ۔ یہاں کھجور کے پٹھے کی پنکھیاں ایسی عمدہ بنتی ہیں کہ ہندوستان میں شاید ہی کہیں اور بنتی ہوں۔ سادی پنکھیاں جن میں کسی قدر ریشم کا کام بھی ہوتا ہے۔ ایک روپیہ قیمت کی ہم نے بھی یہاں دیکھیں۔ اس کے سوا یہاں کی کوئی بات ذکر کے قابل نہیں ہے۔ یہاں کے مسلمان جو پہلے بہت آسودہ اور مرفہ الحال تھے، اب اس قدر پست حالت میں ہیں کہ وہاں کے ذی اعتبار باشندوں میں ان کا کوئی ذکر نہیں آتا۔
اٹاوہ
اٹاوے میں ہم کو زیادہ ٹھہرنے کی مہلت نہیں ملی اور نہ اپنے شفیق میزبان کے مکان کے سوا کہیں جانے کا اتفاق ہوا۔
مین پوری
مین پوری میں ہم دو روز ٹھہرے۔ خوش قسمتی سے ہم کو ایک دن اور ایک رات جناب مرزا عابد علی بیگ صاحب سب آرڈنیٹ جج کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا۔ یہاں بھی طریقۂ معاشرت میں ہم نے وہی انوار و برکات مشاہدہ کئے جو علی گڑھ میں کئے تھے۔ جناب مرزا صاحب بھی اسی ’’مردود گروہ‘‘میں سے ہیں جو قومی ہمدردی کو راس الحسنات اور مخ العبادات جانتا ہے۔ جب ہم ان کے دولت خانے سے رخصت ہو کر ڈاک گاڑی پر پہنچے تو ان کے دو آدمی ہمارے ساتھ تھے، جن سے کوچ بان کو معلوم ہوا کہ وہ صدرِ اعلیٰ کے ہاں سے آئے ہیں۔ اس بات نے ہم کو بہت تکلیف میں ڈالا کیوں کہ گاڑی کا کوچ بان اتفاق سے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی نہایت متقی بھی تھا۔ اس نے یہ بات معلوم ہونے پر راستے میں ہم کو پانی پینے کے لئے اپنا کٹورا تک نہیں دیا اور ہم سے برابر ایسا پرہیز کرتا رہا جیسے بعض ہندو مسلمان سے کرتے ہیں۔ اوّل تو ہم کو اس سے بہت تعجب ہوا، لیکن پھر یاد آیا کہ ہم نے اپنے عالی قدر میزبان کے ہاں برابر دو وقت میز پر کھانا کھایا تھا اور اسی لئے ہم سے پرہیز کرنا ضروری تھا۔
ہمیرپور
جب ہم کانپور میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں سے ہمیر پور تک اونٹ گاڑی کے سوا کوئی سواری نہیں جاتی، اس لیے لاچار اسی میں جانا پڑا اور اتفاقاً ہم کو اوپر کے درجے میں جگہ ملی۔ ہم کو یاد نہیں کہ ہم نے کبھی کسی سواری یا پیدل جانے میں ایسی تکلیف اٹھائی ہو جیسی اس اونٹ گاڑی میں ہمیں پہنچی۔
ریل کے زمانے سے پہلے یہی سواریاں نہایت غنیمت سمجھی جاتی تھیں مگر اب تو ان کے نام سے ہول آتی ہے۔ افسوس کہ یورپ کی صنعتیں روز بروز ہم کو پرلے درجے کا آرام طلب اور راحت پسند بناتی جاتی ہیں، اور اب وہ تمام اسباب اور ذریعے مفقود ہیں جن کے باعث سے کبھی کبھی ہم کو جفا کشی اور محنت کرنے کا بھی موقع ملتا رہے۔
ہمیر پور کو جاتے ہوئے پچھم کی طرف سڑک سے کسی قدر فاصلے پر ہم نے ایک مندر دیکھا جو بیربر کا بنایا ہوا مشہور ہے۔ گو یہ مندر کچھ زیادہ شاندار نہیں ہے مگر اس سنسان جنگل میں ایک ایسے زمانے کو یاد دلاتا ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں ’’طلائی زمانہ‘‘ کہلانے کا مستحق ہے۔ اب ہم جمنا سے اتر کر ہمیر پور پہنچے۔ ہمیر پور راجا ہمیر سنگھ کا آباد کیا ہوا مشہور ہے، جس کے خاندان کی عمارتوں کے کھنڈر اب تک وہاں موجود ہیں۔ یہ قصبہ کان پور سے چالیس میل جانب جنوب بہت بلندی پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں جمنا اور جنوب میں بیدونتی ندی بہتی ہے اور مشرق میں ایک میل پر جاکر دونوں مل گئی ہیں۔ مغرب میں ایک نالہ ہے جو بیدونتی میں جاکر گرتا ہے۔ یہ نالہ برسات میں جاری ہو جاتا ہے اور ویسے ایام میں خشک رہتا ہے اور اس لحاظ سے ہمیر پور کو کبھی جزیرہ اور کبھی جزیرہ نما کہا جا سکتا ہے۔
قدیم باشندے یہاں کے زیادہ تر ہندو ہیں۔ شریف مسلمانوں میں صرف ایک سیدوں کا خاندان ہے جو اکثر خانہ نشین اور بزرگوں کے متروکے پر قانع ہے۔ اس خاندان کے جتنے آدمی میں نے دیکھے ہیں، سب پرانی روش کے بھولے بھالے سیدھے سادے سید ہیں، جن پر زمانۂ حال کی چھینٹ بھی نہیں پڑی۔ اس مقام کی رونق زیادہ تر سرکاری ملازموں سے ہے، اور یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ یہاں سرکاری ملازموں میں جس قدر پردیسی مسلمان ہیں، وہ برخلاف عام مسلمانوں کے باہم برادرانہ محبت اور برتاؤ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے درد اور دکھ میں شریک ہوتے ہیں مگر باوجود اس کے تعصباتِ بے جا میں سب گرفتار ہیں۔ حقیقت میں ہمیر پور ایک ایسے گوشے میں واقع ہے جہاں زمانے کے شور و شغب کی آواز بہت کم پہنچتی ہے۔ مدرسۃ العلوم کا نام وہاں کے اکثر مسلمانوں نے کبھی کان سے بھی نہیں سنا اور جنہوں نے سنا ہے، ان کے ذہن میں اس کی ایسی ہول ناک صورت سمائی ہوئی ہے کہ اس کے نام سے پناہ مانگتے ہیں۔
دلی سے ہمیر پور تک
دلی سے ہمیر پور تک ہم کو شریف مسلمانوں کی اکثر صحبتوں میں بیٹھنے اور ان کی بات چیت سننے کا اتفاق ہوا۔ تقریباً تمام مجلسوں کا رنگ ہم نے ایک ہی اصل پر دیکھا۔ وہی بے جا شیخی اور تعلی اور ہر ایک پہلو سے اپنی تعریف نکالنی، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے اور ان کو برائی سے یاد کرنا، حاضرین کی خوشامد اور غائبین کی بد گوئی، بات بات میں فحش اور دشنام سے زبان کو آلودہ کرنا، اور سب سے زیادہ خود غرضی اور تعصب کا بازار ہر جگہ گرم پایا۔
آگرے سے باندی کوٹی تک
مراجعت کے وقت ہم ایک دن آگرے میں ٹھیر کر الور پہنچے۔ یہاں ہم کو راجپوتانہ اسٹیٹ ریلوے میں بیٹھنا پڑا۔ چونکہ یہ سرکاری ریل ہے، اس لیے ہم کو امید تھی کہ اس میں زیادہ آرام ملے گا، مگر بر خلاف اس کے سب سے زیادہ اسی میں تکلیف اٹھانی پڑی۔ اوّل تو اس میں انٹرمیڈیٹ کلاس کے نہ ہونے سے بڑا نقص ہے۔ کیوں کہ متوسط الحال آدمیوں کے لیے یہ درجہ فرسٹ کلاس کا حکم رکھتا ہے۔ دوسرے گاڑیاں اس قدر چھوٹی ہیں کہ ایک کمرے میں صرف چار آدمی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ باوجود اس کے ایک ایک کمرے میں آٹھ آٹھ ادمی بٹھائے جانے کا حکم ہے۔ اور اس پر غضب یہ ہے کہ جب تک ایک کمرہ میں پورے آٹھ آدمی نہیں بیٹھ لیتے، تب تک دوسرا کمرہ نہیں کھولا جاتا، حالاں کہ اکثر اسی کلاس کی پانچ پانچ سات سات گاڑیاں ٹرین میں بالکل خالی جاتی ہیں۔
ہم رات کی ٹرین میں سوارہوئے تھے اور ہماری گاڑی کے کسی کمرے میں آٹھ آدمی سے کم نہ تھے۔ نیند کے مارے ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا اور تمام راستے مسافروں میں باہم تکرار ہوتی رہی۔ علاوہ ان ’’خوبیوں‘‘ کے یہ ریل اور ریلوں کی نسبت سست رفتار بھی بہت ہے۔ صبح کے سات بجے ہم باندی کوٹی میں پہنچے اور دس بجے تک یہاں ٹھیرے رہے۔ یہاں تقریبا ڈیڑھ میل طول اور اسی قدر عرض کے میدان میں بالکل سنگین عمارتیں اس قدر بنائی گئی ہیں کہ بجائے خود ایک شہر آباد ہو گیا ہے۔ سنا جاتا ہے کہ یہاں کسی قدر سرکاری فوج رکھی جائےگی۔
الور
وہاں سے چل کر ساڑھے بارہ بجے ہم الور پہنچے اور دوپہر تک نئی سرائے میں جو کیڈل صاحب پولیٹکل ایجنٹ کے عہد میں تیار ہوئی ہے، ٹھہرے۔ اس سرائے کی عمارت بالکل سنگین ہے۔ ظاہراً ہندوستان میں یہ پہلی سرائے ہے جس کے نقشے میں ہر ایک مسافر کی آسائش اور تمام ضروریات کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ رات کو ہمارے ایک معزز دوست نے ہم کو اپنے مکان پر بلا لیا اور پانچ روز تک ہم ان ہی کے مکان پر ٹھہرے رہے۔ الور کو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شہر کی آبادی دامن کوہ میں واقع ہوئی ہے اور اسی وجہ سے شہر کا شمالی حصہ جنوبی حصے سے کسی قدر بلند ہے۔ یہاں کے بازار اگرچہ بہت وسیع نہیں مگر پُر رونق ضرور ہیں اور عمارتیں اکثر سنگین ہیں۔
شہر کی عام عمارتیں کچھ زیادہ امتیاز نہیں رکھتیں، لیکن سرکاری محلوں سے راج کی پوری پوری شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ خصوصاً وہ محل جو موتی ڈونگری کے باغ میں مہا راجا بنے سنگھ نے بنوایا ہے۔ عمارت کی خوبی کے علاوہ وہ ایک ایسے موقع پر واقع ہوا ہے جس سے اس کی شان اور عظمت دس گنی ہو گئی ہے۔ محل کے اوپر کے درجے پر چڑھ کر جس طرف نظر ڈالیے، زمین اور پہاڑ اور فرشِ زمردیں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ اب تک وہاں بارش کم ہوئی تھی مگر پھر بھی وہاں کی قدرتی فضا دیکھنے کے قابل تھی۔
یہاں ایک اور مقام بھی کمال دل کش اور روح افزا ہے جو سیلی سیڑھ کے نام سے مشہور ہے۔ شہر سے تقریبا ًچھ میل کے فاصلے پر ایک سیتلا کا مندر ہے۔ جس کو وہاں کے لوگ سیلی سیڑھ کہتے ہیں۔ (سیلی سیڑھ کے لفظی معنی ٹھنڈی سیتلا کے ہیں۔) یہاں دو طرف سے پہاڑ آ کر مل گیا ہے اور ایک مثلث کی سی شکل پیدا ہو گئی ہے۔ اس مثلث کے گوشے میں ایک بڑا اور نہایت مستحکم بند باندھا گیا ہے جس میں وقتاً فوقتاً بارش کا پانی دونوں پہاڑوں سے جھر جھر کر اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ اور یہاں سے الور تک ایک پختہ نہر بنی ہوئی ہے جس کے ذریعہ سے بند کا پانی رستے کے تمام کھیتوں کو سیراب کرتا ہوا شہر تک پہنچتا ہے اور وہاں جا کر الور کے تمام باغات اور اس کے تمام سواد کو سال بھر تک سر سبز و شاداب رکھتا ہے۔ بند کے ایک جانب پہاڑ پر ایک نہایت پختہ گؤ گھاٹ تقریبا پاؤ میل اونچا بنا ہوا ہے۔ جو پہاڑ کی چوٹی پر جاکر ختم ہوتا ہے اور وہاں سرکاری محل بنے ہوئے ہیں۔ یہ مہاراجا بنے سنگھ کی ایک نمودار یادگار ہے جو ہمیشہ ان کے عہد حکومت کو یاد دلائے گی۔
الور کا سواد نہایت دل کش اور دل ربا ہے اور تمام باغات سے گھرا ہوا ہے۔ موتی ڈونگری کے باغ کے سوا جو کہ مشہور ہے، ایک کمپنی باغ بھی ہے جو مہاراجا شیو دھیان سنگھ نے حضور ڈیوک آف ایڈنبراکی تشریف آوری کے زمانے میں تیار کروایا تھا۔ یہ بھی ایک عمدہ پارک ہے۔ اس کے سوا کیڈل گنج، شفاخانہ اور اسکول وغیرہ کی عمارتیں جو کیڈل صاحب کے عہد میں بنی ہیں، نہایت عمدہ اور شہر کے لئے باعث زینت ہیں۔ ریاست الور کے پولیٹکل حالات جس قدر ہم کو معلوم ہوئے ہیں، ان سے ریاست کی آئندہ بہبودی اور ترقی کی بہت کچھ امید ہوتی ہے۔
مہاراجا منگل سنگھ جو تقریبا دو ڈھائی برس سے با اختیار ہوئے ہیں ان کی تعریف میں صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ نواب گورنر جنرل بہادر سابق جب سال گزشتہ کے ختم پر اجمیر میں تشریف لئے گئے تھے تو انہوں نے میو کالج کے طالب علموں سے خطاب کر کے ایک لمبی اسپیچ کی تھی جس میں مہاراجا منگل سنگھ کی شہ سواری، گولہ اندازی، بہادری، جفاکشی، شائستگی اور عالی دماغی کی نہایت تعریف کرکے مخاطبین کو ان کی پیروی کرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔
مہاراجا صاحب نے اس نہایت قلیل زمانے میں جو دو ڈھائی برس سے زیادہ نہ ہو گا کئی ایسے کام کئے ہیں جن کا ایک نوجوان ہندوستانی رئیس سے وقوع میں آنا نہایت عجیب معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے پہلے جنوبی ہندوستان کا ایک سفر اختیار کیا جس میں کسی قدر بحری سفر اور جزیرہ سیلون کی سیاحت بھی شامل تھی، اور بہت شوق سے اپنا سفر نامہ بھی تیار کرایا۔ پھر با اختیار ہونے کے وقت خزانہ بالکل خالی تھا بلکہ ریاست کسی قدر مقروض تھی، مگر اب سنا جاتا ہے کہ خزانے میں تقریبا سات آٹھ لاکھ روپیہ جمع ہے۔ ہر جمعرات کے دن ایک عام دربار مقرر کیا جس میں تمام ریاست کے مستغیثو ں کو اجازت دی گئی کہ خود مہاراجا کے روبرو حاضر ہوکر عرض معروض کریں۔ اور معمولی دربار جو ہر روز تین گھنٹے سے چار گھنٹے تک رہتا ہے اور جس میں کونسل کی تجویزات اور فیصلے پیش ہوتے ہیں یہ اس عام دربار کے علاوہ ہے۔ پولس اور مال کا ازسرنو انتظام کیا جس کی وجہ سے تقریباً پانچ سو روپے ماہوار کا اضافہ، پولس اور عملہ مال کی تنخواہوں میں کیا گیا۔ سررشتہ تعلیم میں بھی روزبروز ترقی ہوتی جاتی ہے۔
ایک بڑا اسکول شہر میں عام رعایا کی تعلیم کے لئے ہے جس میں انٹرنس تک پڑھائی ہوتی ہے اور جو لڑکے یہاں سے انٹرنس پاس کرتے ہیں ان کو وظیفہ دے کر کسی کالج میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اگلے برس دو لڑکوں نے انٹرنس پاس کیا تھا، وہ دونوں لڑکے اجمیر کے گورنمنٹ کالج میں ترقی تعلیم کے لئے بھیج دیے گئے اور آٹھ روپیہ ماہوار ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ اس کے سوا ایک اور اسکول شہر میں ہے جو خاص ٹھاکروں اور سرداروں کی اولاد کے لئے مخصوص ہے۔ اس مدرسے کی حالت ابھی تک کچھ اچھی نہیں ہے۔ علاقہ الور کے دیہاتی مدارس کی ٹھیک تعداد ہم کو یاد نہیں رہی، لیکن غالباً سو سے زیادہ اور ڈیڑھ سو سے کم ہے۔ چودہ مدرسے زنانے بھی ہیں جن میں ہندو مسلمان دونوں قوموں کی لڑکیاں تعلیم پاتی ہیں۔
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آرام طلبی اور سستی اور کاہلی جو ہندوستانی رئیسوں کی سرشت میں داخل ہے، وہ مہاراجا کے مزاج میں بالکل نہیں ہے۔ اور سادگی اور بے تکلفی ایسی ہے کہ اہل یورپ میں بھی ایسی نہیں دیکھی گئی۔ البتہ شکار کا شوق جس قدر ہونا چاہئے اس سے کسی قدر زیادہ ہے۔ باقی تعیش، لہو و لعب اور مسکرات سے، جہاں تک ہم نے سنا ہے، بہ کلی نفرت ہے اور یہ تمام باتیں بشرطیکہ استقلال کے ساتھ قائم رہیں، ایسی ہیں جو انسان کی ترقی کی اصل اصول ہیں۔ پانچ روز الور میں ٹھہر کر ہم رمضان کی انتیسویں تاریخ دن کی ریل میں الور سے روانہ ہوئے اور شام کو دلّی پہنچ گئے۔