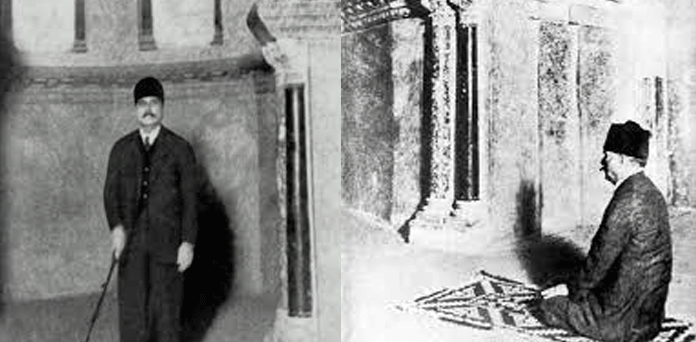برصغیر بالخصوص ہندوستان میں علّامہ اقبال بطور شاعر ہی شہرت اور مقبولیت نہیں رکھتے تھے بلکہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر پہچانا جاتا تھا جس نے تقسیم سے قبل پہلی مرتبہ نوجوان نسل کو درسِ خودی اور اس وقت کے مسلمانوں میں سیاسی اور ملّی شعور اجاگر کرنے کے ساتھ انھیں ان کی گم گشتہ میراث کی جانب متوجہ کیا۔ بطور مفکر اور شاعر اقبال کا فلسفہ، افکار اور اشعار آج بھی دنیا بھر میں موضوعِ بحث بنتے ہیں۔
شاعرِ مشرق علامہ اقبال کی شاعری پر جہاں مغرب اور یورپ کے اہلِ دانش، علمی و ادبی حلقے بات کرتے ہیں، وہیں اسلامی دنیا میں بھی ان کی نظموں کا شہرہ ہوا۔ اردو اور فارسی زبان میں شاعری کرنے والے اقبال کے اشعار کا عربی میں ترجمہ بھی ہوا اور عرب دنیا کے معروف اہلِ قلم نے ان کے فلسفہ پر بحث کی ہے جب کہ عرب گلوکاروں نے ان کا کلام گایا ہے۔ لیکن یہ بات شاید کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ تقسیمِ ہند سے قبل ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگا تھا۔
یہ بات ہے 15 اکتوبر 1925 کی جب اس دور کے مشہور اخبار ’زمیندار‘ میں ایک سنسنی خیز خبر شائع ہوئی جس کی بنیاد ایک فتویٰ تھا۔ یہ فتویٰ لاہور کی مسجد وزیر خان کے خطیب مولوی دیدار علی الوری کی طرف سے دیا گیا تھا جو اپنے وقت کے مشہور و معروف عالمِ دین اور مفتی تھے۔ دراصل مولوی دیدار کو کسی نے خط لکھا تھا جس میں اقبال کے بعض اشعار میں اپنی دانست میں کفریہ کلمات کی طرف توجہ مبذول کروائی تھی۔ اس پر مولوی صاحب نے فتویٰ دیا تھا۔ لیکن اس وقت کے جید اور بڑے ناموں کے ساتھ عوام نے بھی مولوی دیدار علی کو اس فتویٰ پر مطعون کیا تھا۔ اس بارے میں عبدالمجید سالک نے اپنی کتاب ’ذکرِ اقبال‘ میں لکھا ہے کہ ’اس فتوے پر ملک بھر میں شور مچ گیا۔ مولوی دیدار علی پر ہر طرف سے طعن و ملامت کی بوچھاڑ ہوئی۔ مولانا سلیمان ندوی نے ’زمیندار‘ میں اس جاہلانہ فتوے کی چتھاڑ کر دی۔ ایک گمنام مقالہ نگار نے ایک مدلل مضمون میں اس فتوے کا جواب دیا، یعنی اشعارِ منقولہ کے ایک ایک لفظ پر بحث کر کے ثابت کیا کہ ان سے ہرگز کفر کا شائبہ تک پیدا نہیں ہوتا۔‘
عبدالمجید سالک مزید لکھتے ہیں کہ ’مولوی دیدار علی کی اس حرکت سے علمائے اسلام کے اجتماعی وقار کو سخت صدمہ پہنچا کیوں کہ مسلمانوں کے تمام طبقات عالم و عام، قدیم، تعلیم یافتہ اور جدید پڑھے ہوئے لوگ علامہ اقبال کو نہایت مخلص مسلمان، عاشقِ رسول، درمندِ ملت، حامیِ دینِ اسلام تسلیم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہمارے علما کے نزدیک اقبال جیسا مسلمان بھی کافر ہے تو پھر مسلمان کون ہے؟‘
دوسری طرف اسی دور میں علامہ اقبال کو برصغیر ہی نہیں عالمِ عرب میں بھی پذیرائی مل رہی تھی اور انھیں ایک عظیم اسلامی مفکر کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ ان کے کلام اور ہر طبقۂ عوام کے لیے اس میں پنہاں پیغام کو عربی زبان میں ڈھالا جانے لگا تھا۔ 1931ء میں علّامہ اقبال فلسطین میں منعقدہ اسلامی کانفرنس میں شرکت سے قبل مصر گئے تو ان کے اعزاز میں ایک تقریب ہوئی جس میں عبدالوہاب عزام نے جو خود ایک بڑے شاعر اور نثر نگار تھے، اقبال سے سب کو متعارف کروایا اور بعد میں ان کے اشعار کا عربی ترجمہ کیا۔ عبد الوہاب عزام نے پیام مشرق، اسرار خودی، ضرب کلیم اور دیگر مجموعہ ہائے کلام کا عربی ترجمہ شائع کروایا۔
شاعری
شاعرِ مشرق کی مشہور نظم ’شکوہ‘ اور ’جواب شکوہ‘ کا بھی عربی ترجمہ ہوا اور یہ کام مصر کے ایک ادیب اور شاعر صاوی الشعلان نے انجام دیا۔ انھوں نے ’حدیث الرّوح‘ کے نام سے اس کلام کا عربی ترجمہ کیا جسے عرب آج بھی پڑھتے ہیں اور فکر و پیامِ اقبال سے روشناس ہوتے ہیں۔ عرب دنیا میں اقبال کے اس کلام کو بعد میں معروف مصری گلوکارہ ام کلثوم نے بھی اپنی دلنشیں آواز میں ریکارڈ کروایا۔ اقبال کے کلام کا عربی ترجمہ کرنے والوں میں ہندوستان کی معروف علمی و ادبی شخصیت ابوالحسن علی ندوی بھی شامل ہیں جنھوں نے اقبال کے منتخب اشعار کا ترجمہ کیا اور ان کی کتاب دمشق سے شائع ہوئی۔
(اقبال سے متعلق علمی و تحقیقی مضامین سے ماخوذ)