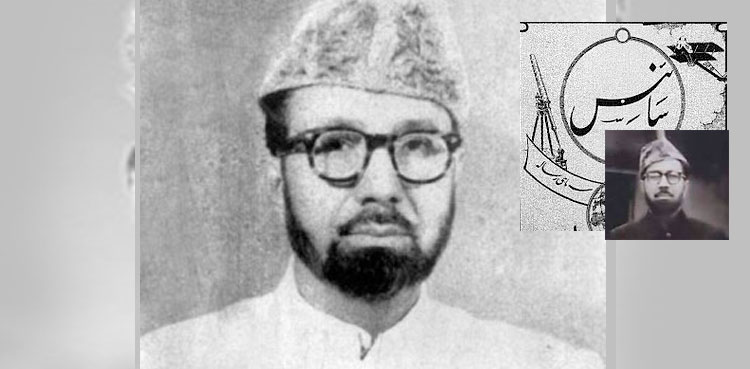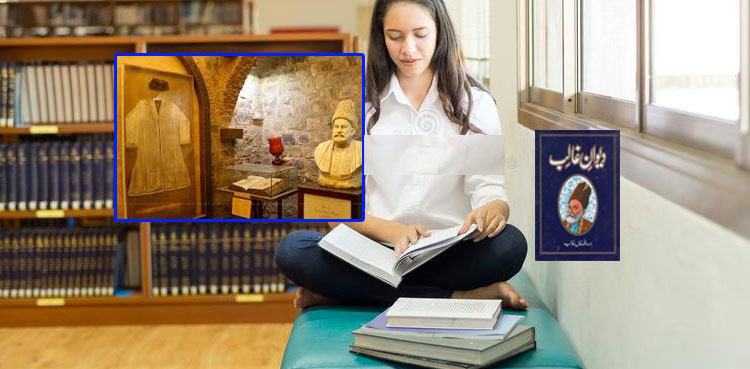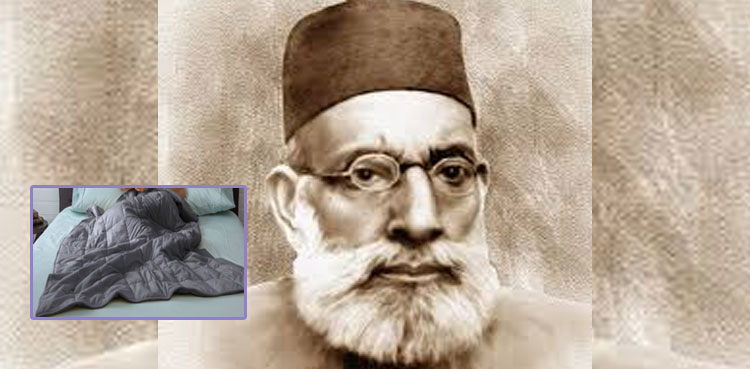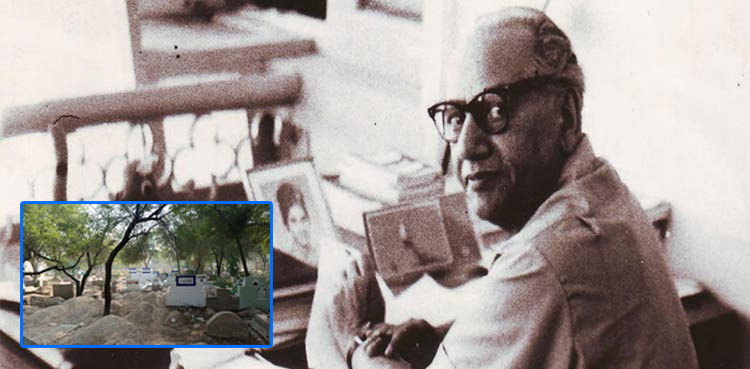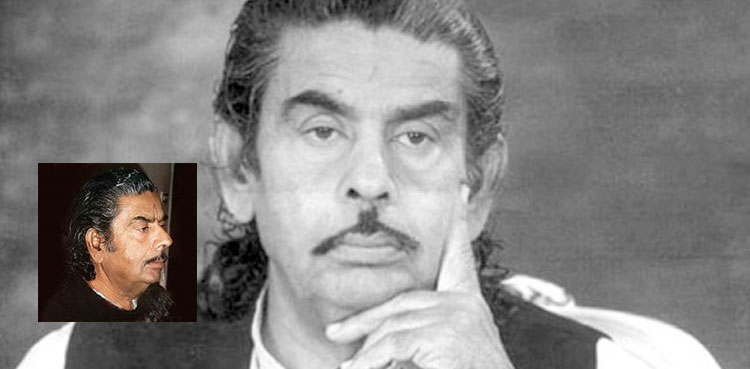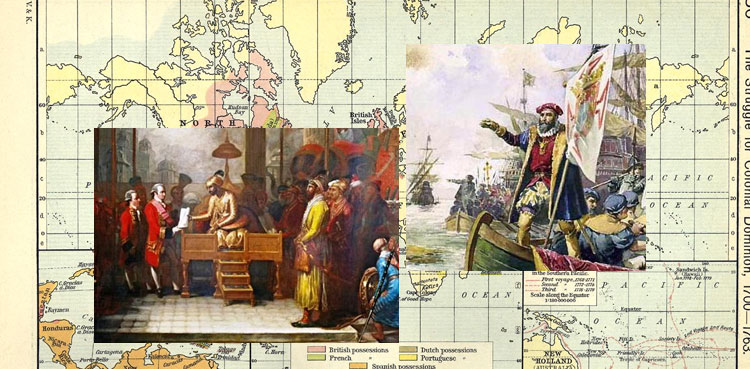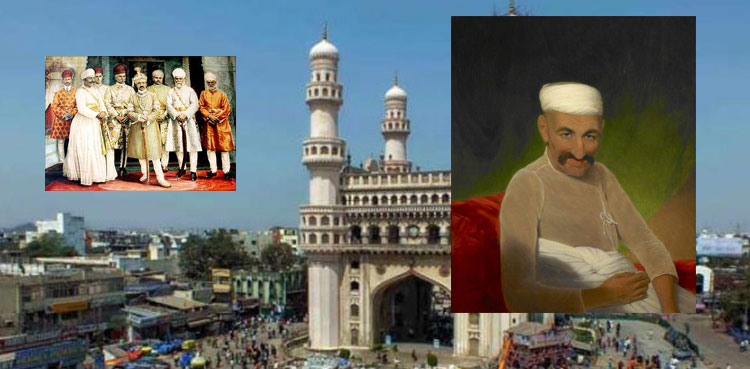یورپ میں سوئٹزر لینڈ کو قریب قریب وہی حیثیت حاصل ہے جو ایشیا میں ہمالیہ اور کاکیزس ماؤنٹین (کوہ قاف) کی وادیوں کو، بلکہ بعض انگریزی سیّاح تو دعویٰ کرتے ہیں کہ سوئٹزر لینڈ کی نزہت و شادابی اور وہاں کی سینریوں کی خوش نمائی و نظر فریبی دنیا بھر کے ممالک سے بڑھی ہوئی ہے۔
خیر اس کو تو ہم اسی خود پسندی کے اصول پر مبنی سمجھتے ہیں جس بنا پر کہ بعض وطن دوست انگریز لندن کے گرجے سینٹ پال کو روم کے سینٹ پیٹرس اور مِلا ن کے بڑے کنیسہ پر ترجیح دینے لگے ہیں، لیکن اس میں شک نہیں کہ سوئٹزر لینڈ کے سواد میں خدا نے بہت کچھ دل فریبیاں ودیعت کر رکھی ہیں۔
کوہسار آلپس کا سلسلہ ملک کو ایک طرف سے دوسری طرف تک قطع کرتا چلا گیا ہے اور اسی کوہستان کے دامنوں اور اونچے اونچے سر بہ فلک قلوں کی گھاٹیوں میں یہ چھوٹا سا ملک آباد ہے۔
تاہم کوہ قاف کی گھاٹیوں اور سرکیشیا کی سرزمین کی طرح یہاں یہ بات کہاں کہ نباتی پھولوں اور سبز پوشانِ چمن کی طرح انسانی چہرے بھی ہر طرف دل فریبیاں کر رہے ہوں۔ وہ پری جمال اور دل رُبا چہرے جو صد ہا سال سے ایران اور روم کی حرم سراؤں کی رونق رہا کیے ہیں اور وہ نازک اندام اور آفت زمانہ لڑکیاں جو کوہِ البرز وغیرہ کی گھاٹیوں کے لطیف آبشاروں میں ہاتھ منہ دھوتی اور مویشیوں کے گلے چراتی نظر آتی ہیں، ان کا سوئٹزر لینڈ کی بھدّی مگر توانا و تن درست عورتوں میں کہیں پتہ نہیں۔ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آلپس کی گھاٹیوں میں چاہے وہ دل فریب حسن و جمال نہ ہو، مگر ایسے ایسے نظر فریب منظر اور اس طرح کی جاں بخش سینریاں آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں کہ ہر مقام پر یہی جی چاہتا ہے کہ دین و دنیا چھوڑ کے یہیں بیٹھ رہیے۔
الغرض یہ اور ایسا روح افزا اور فرحت بخش ملک ہے جہاں ہم مِلان سے ریل پر سوار ہو کے اور اٹلی کی سرحد سے نکل کے پہنچے۔ مِلان سے 4 بجے کے قریب تیسرے پہر کو سوار ہوئے تھے۔ رات ہونے تک بلکہ اس وقت تک جب کہ ہم نے لیٹ کے سونے کا تہیہ کیا، وہی اٹلی کے خوش نما، تر و تازہ اور انگور کی بیلوں سے گھرے ہوئے کھیت نظر کے سامنے تھے، جن کے دیکھنے سے آنکھیں سیر ہو گئی تھیں اور جن میں اب کوئی جدّت نہیں نظر آتی تھی۔
صبح کو تڑکے ہی اٹھائے گئے، اس لیے کہ ٹرین چیاسو میں کھڑی ہوئی تھی جو جنوب کی طرف سوئٹزر لینڈ کا سرحدی اسٹیشن ہے اور جہاں مسافروں کے اسباب کی تلاشی لی جاتی ہے۔ ہم سب اپنا اسباب لے لے کے گاڑی سے اترے اور قیدیوں کی طرح ایک بڑے کمرے میں بند کر دیے گئے۔ چنگی وصول کرنے والوں نے صندوقوں کو کھول کھول کے دیکھا اور پاس کیا۔ اس سخت امتحان سے نجات حاصل کرتے ہی ہم ایک دوسرے دروازے سے پھر پلیٹ فارم پر آئے اور گاڑی میں اسباب رکھا۔
یہاں کی زندگی بخش آب و ہوا نے اتنا اثر یہیں ظاہر کر دیا کہ صبح کو ہم خلافِ معمول بہت بھوکے اٹھے، کھانا ملنے میں ابھی دیر تھی اور انتظار کی طاقت نہ تھی۔ اسٹیشن پر نہایت عمدہ تر و تازہ اور شاداب انگور بکنے کو آئے جو بہت سستے تھے، ہم نے لے کے خوب سیر ہو کے کھائے اور گاڑی آگے کو روانہ ہوئی۔
تھوڑی دیر تک تو وہی اٹلی کی سواد نظر آتی رہی، مگر دو چار گھنٹے کے بعد ہمیں کوہستان آلپس کے سلسلے کی چوٹیاں نظر آنے لگیں اور زیادہ انتظار نہیں کرنے پائے تھے کہ انھیں پہاڑیوں کے اندر ہماری ٹرین گھسنے لگی اور وہ قدرتی مناظر ہماری نظر کے سامنے تھے، جن میں انسانی کاری گری کا ہاتھ بالکل نہیں لگا تھا۔
ریل سر سبز اور تر و تازہ پہاڑیوں کے اندر چلی جاتی ہے، کبھی بلندی پر چڑھتی ہے اور کبھی نشیب میں اترتی ہے اور پھر اسی نشیب و فراز کے درمیان میں ایسے خوش سواد اور دل میں ولولہ پیدا کرنے والے مرغزار اور قدرت کے لگائے ہوئے چمن نظر کے سامنے آتے ہیں اور کچھ ایسی کشش سے اپنی طرف بلاتے ہیں کہ ہمارے ایک ہم سفر انگلش دوست بار بار چلّا کے کہہ اٹھتے ہیں: “مجھے نہ پکڑنا، میں یہیں کودا پڑتا ہوں”۔
جا بجا بڑے بڑے آبشار پہاڑوں کی چوٹیوں سے بہتے اور لہراتے ہوئے نیچے آتے ہیں اور ان سبزہ زاروں میں پانی پہنچا رہے ہیں۔ اکثر جگہ جہاں کہیں کوئی مسطح تختہ ہے، وہاں ایک چھوٹا شہر آباد ہے جس کی سفید سفید اور برف میں دھوئی ہوئی پختہ عمارتیں کچھ ایسی دل فریبی کرتی ہیں کہ ان پر سرور بخش اور جاں افزا وادیوں اور مرغزاروں سے بھی زیادہ بہار نظر آتی ہے۔ ہر چہار طرف سَر بہ فلک پہاڑ جو قوی ہیکل دیوؤں کی طرح سر اٹھائے کھڑے ہیں، انھوں نے بھی انسان کے مانوس بنانے کے لیے برف کے سفید اور اجلے کپڑے پہن کے بہت کچھ مہذب صورت بنالی ہے۔
(اردو کے نام ور ادیب، مشہور ناول نگار اور جیّد صحافی عبدالحلیم شرر کے سفر نامے سے انتخاب)