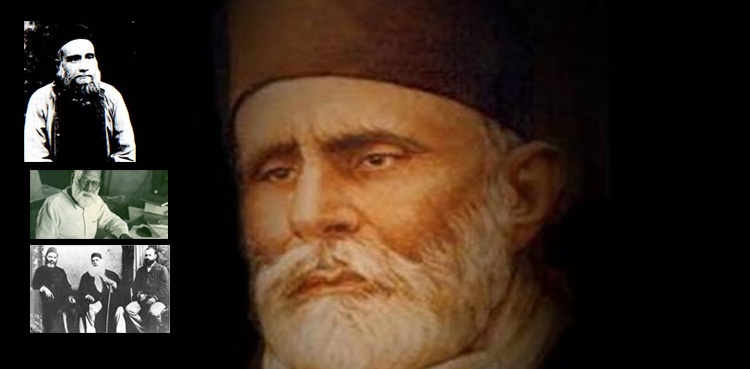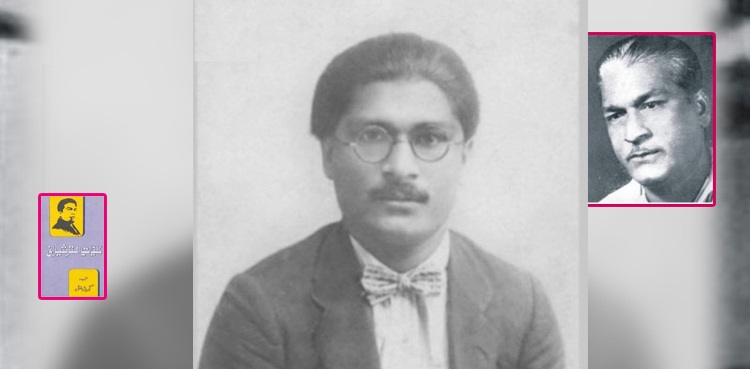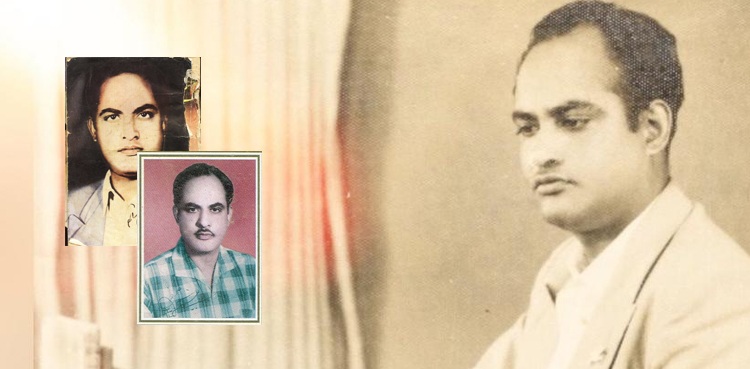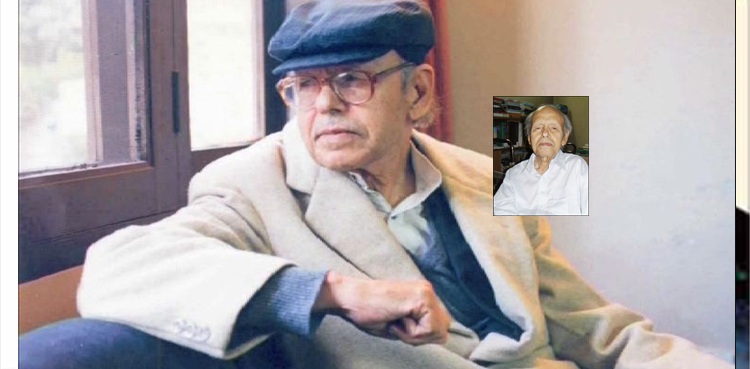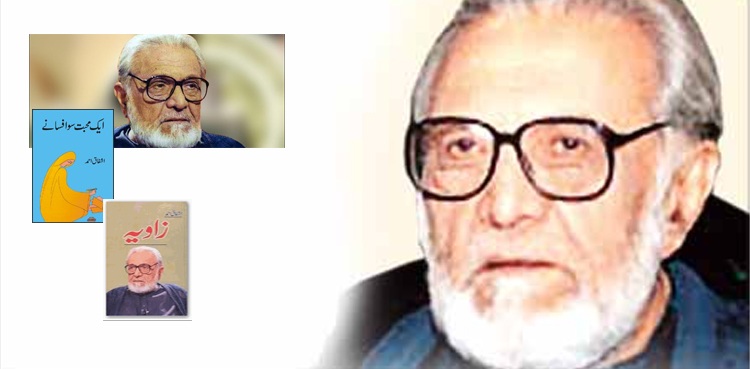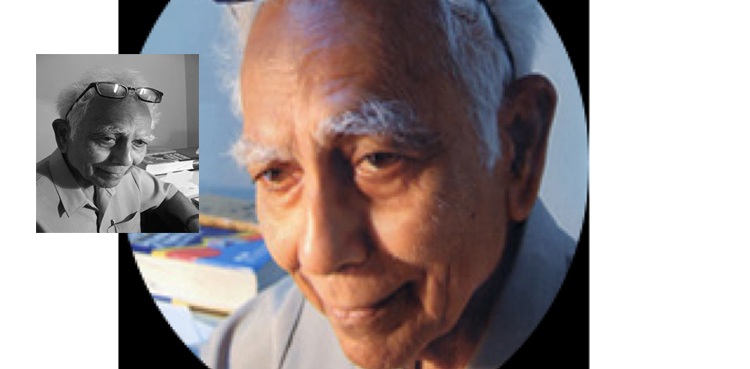آج اردو کی ممتاز افسانہ نگار ہاجرہ مسرور کی برسی ہے۔ وہ 15 ستمبر 2012 کو کراچی میں وفات پا گئی تھیں۔ لکھنؤ سے تعلق رکھنے والی ہاجرہ مسرور قیامِ پاکستان کے بعد پاکستان آگئیں اور یہاں لاہور میں سکونت اختیار کی۔
ان کے والد ڈاکٹر تہوّر احمد خاں برطانوی فوج میں ڈاکٹر تھے جو 17 جنوری 1929 کو پیدا ہونے والی ہاجرہ مسرور کو کم عمری میں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوگئے۔ والد کے انتقال کے بعد کنبے کی کفالت کی ذمہ داری والدہ کے کاندھوں پر آگئی۔ یوں اس خاندان اور ہاجرہ مسرور نے سخت اور مشکل حالات دیکھے۔ ہاجرہ مسرور کی بہن خدیجہ مستور بھی اردو کی معروف ادیب تھیں۔
پاکستان میں ہاجرہ بطور کہانی و افسانہ نگار اپنا سفر شروع کرچکی تھیں۔ ان کی کہانیوں کو ادبی حلقوں میں بہت پذیرائی ملی۔ ہاجرہ مسرور نے معروف ادیب احمد ندیم قاسمی کے ساتھ مل کر ادبی جریدہ ’’نقوش‘‘ شایع کرنا شروع کیا جب کہ کے ان کے افسانوں اور مختصر کہانیوں کے سات مجموعے شایع ہوئے جن میں چاند کے دوسری طرف، تیسری منزل، اندھیرے اجالے، چوری چھپے، ہائے اللہ، چرکے اور وہ لوگ شامل ہیں۔ ہاجرہ مسرور نے ڈرامے بھی لکھے۔
ہاجرہ مسرور نے پاکستان میں متعدد فلموں کے لیے اسکرپٹ بھی لکھے۔ انھیں اپنے ایک اسکرپٹ پر پاکستانی فلمی صنعت کا سب سے بڑا اعزاز ’’نگار ایوارڈ‘‘ بھی ملا۔
پاکستان کی اس معروف ادیب کو متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ حکومتِ پاکستان نے ادب کے شعبے میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے صدارتی تمغہ برائے حسنِ کارکردگی عطا کیا۔
ہاجرہ مسرور پاکستان کے معروف صحافی احمد علی خان سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ بعد میں ہاجرہ مسرور کراچی منتقل ہوگئیں اور اسی شہر میں اپنی زندگی کا سفر تمام کیا۔ وہ ڈیفنس سوسائٹی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔