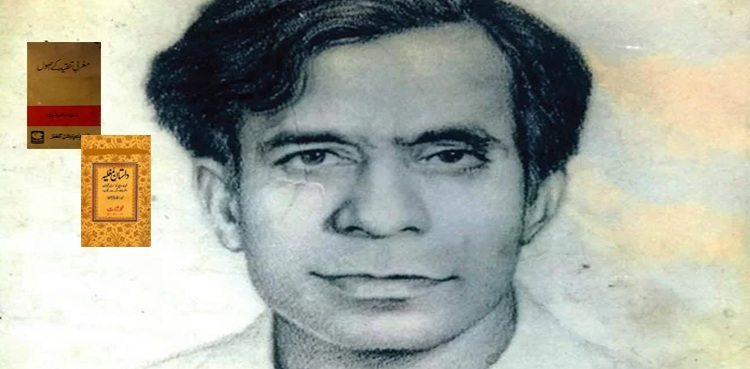بعض ساعتیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، پل بھر میں بے جان چیزوں کو جاندار اور جاندار کو بے جان بنا دیتی ہیں۔ دین محمد میرے پاس سے گیا تھا تو کیسا زندہ آدمی تھا اور واپس آیا تو زندہ لاش بن چکا تھا۔ ساتھ کام کرنے والے دونوں لڑکے اس کے پاس افسردہ بیٹھے تھے۔
دین محمد نے جب مجھ سے چھٹی مانگی تھی تو میں نے کہا تھا۔ ’’دیکھو رمضان کے مہینے میں ساری سلائیاں ہوتی ہیں، تم چلے جاؤ گے میرا بہت نقصان ہوجائے گا، بوتیک کی ساکھ خراب ہوجائے گی۔‘‘
’’باجی بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔‘‘ اس نے شوخی سے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تھا۔
’’تم نے کہا اور میں نے مان لیا، چار دن تو آنے جانے میں لگیں گے پھر اگر دو تین دن بھی رہے تو پورا ہفتہ ہوگیا، آخر اتنی جلدی کیا ہے، عید پر تو تمہیں جانا ہی ہے۔‘‘
’’باجی عید کس نے دیکھی ہے، بیچ میں پورا مہینہ رمضان کا پڑا ہے، عید پر لمبی چھٹی لوں گا۔ ابھی جاؤں گا صرف دو دن ٹھہروں گا۔‘‘ اس نے اپنے بیگ کو بند کرتے ہوئے کہا۔ دونوں لڑکے جو اس کی سفارش کے لیے پاس ہی کھڑے تھے مسکرائے۔
’’عید بعد اس کی شادی ہے، ابھی یہ اپنی ماں، بہن اور بھابھی کے جوڑے لے کر جا رہا ہے، دلہن کا جوڑا اس نے خود سیا ہے، آپ دیکھیں نا کتنا خوب صورت ہے۔‘‘ دونوں لڑکوں کی روشن آنکھوں کی چمک میں دین محمد کے خوابوں کی تعبیر کی آرزو یوں جھلک رہی تھی جیسے وہ ان کا بھی خواب ہو۔
والدین اور گھر والوں سے ملنے دین محمد جارہا تھا مگر تصور میں یہ دونوں لڑکے بھی اس کے ہم سفر تھے، میرے اصرار پر دین محمد نے شرما کر اپنا سفری بیگ کھولا اور یکے بعد دیگرے بیس جوڑے نکال کر سامنے رکھ دیے۔ تین چار بہت قیمتی اور خوب صورت جوڑے تھے۔
’’یہ لشکارا مارنے والے جوڑے دلہن کے ہیں نا۔‘‘ میں نے اسی کے انداز میں پوچھا۔
اس کی آنکھوں میں مستقبل کی خوشیوں کے چراغ جل اُٹھے۔ ’’یہ میری ماں کا جوڑا ہے، یہ تین جوڑے جو ایک سے ہیں ایک میری بھرجائی، ایک میری بہن اور یہ سرخ جوڑا اس کے لیے ہے۔‘‘ اس نے باری باری چاروں جوڑوں کو نکال کر وضاحت کی۔
’’بھائی نے کہا تھا اپنی بھرجائی کا جوڑا دلہن سے کم نہ ہو۔‘‘
میں نے اس سے کہا تھا۔ ’’تمہاری دلہن کے لیے جھومر اور ٹیکا میں لاؤں گی، تصویریں اچھی آتی ہیں۔‘‘ اگلے دن میں نے صرف تین ہزار میں خوب صورت نگوں سے مزین جھومر اور ٹیکا اس کے سامنے رکھا، وہ خوشی کے مارے کھِل اُٹھا۔
’’باجی یہ تو بالکل ٹی۔ وی والی کشش کے جھومر اور ٹیکے جیسا ہے۔‘‘
’’ہاں یہ کشش جھومر اور کشش ٹیکا ہی ہے، ہیں تو یہ نقلی مگر بالکل اصلی لگتے ہیں، ان سے سج کر تمہاری دلہن ٹی۔ وی ڈرامے والی کشش ہی لگے گی۔‘‘ اس کے دونوں ساتھی بھی آنکھوں میں خواب سجائے محویت کے عالم میں جھومر اور ٹیکے کو دیکھنے لگے۔
’’میری شادی پر کشش بالیاں بھی دینا۔‘‘ جہانگیر کی آواز میں خواہش اور امنگ کا غلبہ تھا۔ دین محمد نے اپنا بیگ کھولا، کنگن، بالیاں اور پراندہ دکھاتے وقت اس کی آنکھوں میں سجی سجائی دلہن کی تصویر صاف نظر آرہی تھی، چہرہ دمک رہا تھا۔
سات اکتوبر کی شام کو چنار پہنچتے ہی اس کا فون آیا۔ ’’باجی میں صرف دو دن یہاں رہوں گا، تم بالکل فکر نہ کرنا۔‘‘
’’دین محمد تم نے کپڑے اور زیور دکھائے سب کو، کیسے لگے؟‘‘ دوسری طرف سے امنگوں اور آرزوؤں سے بھری آواز میرے کانوں میں گونجی۔
’’باجی ابھی میں گھر نہیں گیا، پی سی او سے فون کر رہا ہوں، جہانگیر اور نور محمد سے کہنا مجھے رات کو موبائل پر فون کریں میں 13 یا 14 تاریخ کو آپ کے پاس آجاؤں گا۔‘‘
ساری رات آنکھوں میں کٹی، سحری کے لیے بستر سے اُٹھی، فجر کی نماز کے بعد پل بھر کو آنکھ لگی، میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا، مجھے محسوس ہوا جیسے زمین رو رہی ہے، میں نے آنکھیں ملیں اور پھر سونے کی کوشش کی، اس بار میں نے دیکھا تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور زمین بین کر رہی ہے، یکایک محسوس ہوا ساری دنیا سمندر بن گئی ہے اور میں سمندر میں ہوں۔ خوف سے میری آنکھ کھل گئی مگر شاید یہ بھی خواب ہی کا عالم تھا کیوں کہ میں اس وقت بھی خواب کے حصار سے نکل نہیں پائی تھی۔
زمین ایک ستم زدہ ماں کے روپ میں سینہ کوبی کررہی تھی، سمندر رو رہا تھا، ایک شور قیامت تھا، میں نے چیخنا چاہا مگر آواز گھٹ گئی تھی، میری نیند یوں اچاٹ ہوئی کہ پھر کوشش کے باوجود نہیں سوسکی، میرا دھیان اپنے سمندر کی طرف گیا، میں نے اپنے شہر کی سلامتی کی دعا ئیں مانگیں، دعاؤں کے بعد کمرے سے ٹی۔ وی لاؤنج کی طرف آئی، گھر کے سارے افراد ہمہ تن گوش تھے، ہر چینل سے پل پل زلزلے کی خبریں آرہی تھیں، پہلے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، خواب کے اثر سے باہر بھی نہیں نکلی تھی کہ یہ حقیقت آنکھوں کے سامنے تھی۔
فوری طور پر میرے ذہن میں دین محمد کا شرماتا، مسکراتا خوابوں اور آرزوؤں سے بسا پیکر سوال کی صورت میں سامنے آیا۔
’’باجی عید کس نے دیکھی ہے۔‘‘ اس کا یہ جملہ مجھے اسی وقت کھٹکا تھا میں نے چاہا بھی تھا کہ کہہ دوں بری بات منہ سے نہیں نکالتے مگر اگلے سارے جملوں میں خوشیوں کی جھنکار تھی اس لیے وہ جملہ یاد بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے بے شمار بار اس کے سیل فون پر رابطہ کرنا چاہا مگر دوسری طرف سے جواب نہیں آرہا تھا۔
پندرہ دنوں کے بعد دین محمد کی آواز سن کر میں رو پڑی۔’’شکر ہے تم زندہ ہو دین محمد۔‘‘ میں نے بمشکل کہا۔ دین محمد کا نام سن کر دونوں لڑکے میرے پاس آگئے۔
’’باجی سب ختم ہوگیا۔‘‘ شدتِ غم سے اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی، میں اور میرے پاس کھڑے دونوں لڑکے اس کا نام لیتے رہے، مگر وہ ایک لفظ بھی ادا نہیں کرسکا۔
بیس دنوں کے بعد دین محمد واپس آیا مگر وہ دین محمد کب تھا، وہ تو کوئی اور ہی شخص تھا، ویران آنکھوں میں سارے جہان کا درد سمیٹے خوف زدہ سا ایک کونے میں کھوئی کھوئی سی پہچان لیے بالکل خاموش تھا۔
بہت دیر کے بعد میں نے بولنے کی ہمت کی۔ ’’دین محمد چنار ایک بار پھر آباد ہوجائے گا، حوصلہ رکھو۔‘‘ میرا دل میری آواز کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اس نے بھی جن نظروں سے میری طرف دیکھا میں ان کی تاب نہ لاسکی گویا کہہ رہا ہو،
’’میرا شہر تو آباد ہوجائے گا، اینٹ، گارے، اور سریے سے بنی ہوئی عمارتیں دوبارہ کھڑی ہوجاتی ہیں مگر دل کا نگر اُجڑ جائے تو دوبارہ نہیں بستا۔‘‘ اس کا وجود بند قبر کی مانند تھا جس میں جیتا جاگتا دین محمد تمام امیدوں اور اُمنگوں کے ساتھ دفن تھا۔
میرے پاس حروفِ تسلی تھے نہ اسم شفا۔ ’’باجی اب یہ کبھی کپڑے نہیں سی سکتا۔‘‘اس کے دونوں دوستوں نے روتے ہوئے کہا۔
’’کیوں نہیں سی سکتا، اسے اللہ نے زندہ رکھا ہے، تم لوگ اس کا حوصلہ بڑھاؤ، کشمیر کے لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں، تم نے ٹی۔ وی پر ان کے انٹرویو سنے ہیں نا۔۔۔؟‘‘
’’وہ اور لوگ ہیں باجی، اپنا دینے کراچی میں رہ کر کراچی والوں جیسا ہو گیا ہے، یہ اپنی روح وہیں چھوڑ آیا ہے۔‘‘
’’تم لوگ مجھے لاجواب کر دیتے ہو، اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟‘‘
’’باجی ہم بھی انسان ہیں، ٹی وی اور فلموں میں ہماری کہانیاں ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے اس نے گھر جا کر سارا سامان اپنی ماں کو دے دیا تھا، مگر اپنا لیا ہوا کنگن اور آپ کا دیا ہوا جھومر اسے لے جاکر ساری چیزیں دکھائی تھیں، اس کی کلائی میں اپنے ہاتھوں سے کنگن پہنایا تھا، اس نے شرما کر کنگن کو چوما تھا، اور پھر اتار کر دین محمد کو تھما دیا تھا کہ ماں سے کہنا صبح پہنا دے، ابھی پہنوں گی تو سب چھیڑیں گے۔
ریشم گھر چلی گئی تھی مگر دین محمد سحری کے بعد اپنے دوست کے ساتھ کھلے میدان میں چادر تان کر سو گیا تھا، مجھے یہ سب اسی دوست نے بتایا تھا۔
صبح ایک تیز آواز نے ان دونوں کو اُٹھایا جب تک یہ اپنے گھر گیا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے ملبہ ہٹایا تھا، ماں، باپ، بھائی، بھابھی، چاچا اور چاچی اور ان کی بیٹی سب اللہ کو پیارے ہوچکے تھے، تین چار دن تک کھدائی ہوتی رہی تھی، مٹی کے ڈھیر میں ایک ہی جگہ پر وہ پوٹلی پڑی تھی اور یہ کنگن جس میں ریشم کے ہاتھوں کی خشبو ہے، دین محمد کے پاس ہی پڑا تھا۔‘‘
سحر زدہ سا دین محمد اپنے ساتھیوں سے اپنی ہی کہانی سن رہا تھا، اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ گویا کسی اور کی بات ہورہی ہو۔
زلزلے نے اس کے دماغ کے کسی حصے کو ایسا دھچکا لگایا تھا کہ سارے کا سارا دین محمد اپنی آنکھوں میں آگیا تھا۔ گلے میں پڑا ہوا پراندہ درد کی تصویر بنا تھا۔ یکایک اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ کنگن نکالا جس میں ریشم کے ہونٹوں کی گرمی اور کلائی کی خوشبو بیتے دنوں کی یاد بن کر سسک رہی تھی۔
دین محمد چپ تھا، مگر کنگن بول رہا تھا۔
(اس کہانی کی مصنف شہناز پروین ہیں جنھوں نے برصغیر کے سیاسی اور سماجی حالات کو اپنی تخلیقات میں سمویا ہے، افسانوں کے علاوہ شہناز پروین کا ایک ناول بھی شایع ہوچکا ہے)